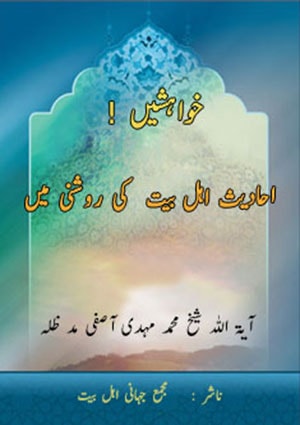یہ کتاب برقی شکل میں نشرہوئی ہے اور شبکہ الامامین الحسنین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں تنظیم ہوئی ہے
نام کتاب : خواہشیں ! احادیث اہل بیت کی روشنی میں
مصنف : آیة اللہ شیخ محمد مہدی آصفی مد ظلہ
مترجم : سید کمیل اصغر زیدی
تصحیح: سید منظر صادق زیدی
نظر ثانی: سید احتشام عباس زیدی
پیشکش: معاونت فرہنگی ادارۂ ترجمہ
ناشر : مجمع جہانی اہل بیت
کمپوزنگ: سید حسن اصغرنقوی
طبع اول: ۱۴۲۷ ھ ۲۰۰۶ ئ
تعداد ۳۰۰۰
مطبع : اسراء
بِسْمِ ﷲالرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ
بنام خدائے رحمان ورحیم
قُلْ أَعُوذُبِرَبِّ النَّاسِ٭مَلِکِ النَّاسِ٭
اے رسول کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوںجو تمام لوگوں کا مالک و بادشاہ
اِلٰهِ النَّاسِ٭مِنْ شَرِّالوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ٭الَّذِی
اور سارے انسانوں کا معبود ہے شیطانی وسواس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے
یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِالنَّاسِ٭مِنَ الجِنَّةِوَالنّاسِ٭
اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کراتا ہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم
حرف اول
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچے و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کرلیتی ہیں تاریکیاں کافور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور ،عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے اپنی قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔
اسلام کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفیصلىاللهعليهوآلهوسلم غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمۂ حق و حقیقت سے سیراب کردیا، آپ کے تمام الٰہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمراں ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑگئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے ہوں تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کرلیا۔
اگرچہ رسول اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کی یہ گرانبہا میراث کہ جس کی اہلبیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کردی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہلبیت علیہم السلام نے اپنا چشمۂ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہلبیت علیہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت واقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامراں زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین وبے تاب ہیں،یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔
(عالمی اہلبیت کونسل) مجمع جہانی اہلبیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہلبیت عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہوسکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہلبیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوتصلىاللهعليهوآلهوسلم و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔
ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہلبیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل علّامہ آیة اللہ شیخ محمد مہدی آصفی مد ظلہ کی گرانقدر کتاب ( الہویٰ فی حدیث اہل البیت )کوسید کمیل اصغر زیدی نے اردو زبان میںاپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے ان تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔
والسلام مع الاکرام
مدیر امور ثقافت، مجمع جہانی اہلبیت علیہم السلام
مقدمہ ٔ مؤلف
آپ کے سامنے اس حدیث قدسی سے متعلق کچھ فکری کا وشوں کا نتیجہ حاضر خدمت ہے جو خواہشات نفس،ان کی پیروی اور مخالفت نیز انسانی زندگی میں ان کے آثار کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔
یہ فکری کوشش درحقیقت ا ن یا دداشتوں کا مجموعہ ہے جنہیں میں نے حوزہ علمیہ قم کے کچھ طلاب کے درمیان درس کے عنوان سے بیان کیا تھا ،اور اب خداوند عالم نے انہیں اس شکل وصورت میںمرتب اور نشر کرنے کی توفیق عنایت فرمادی ہے ۔
ان تمام عنایتوں پر اسکی حمد ہے ۔اور ﷲتعالی سے دعا ہے کہ اسے مومنین کے لئے مفید بنادے اور اسکے صاحب تحریر کے لئے بھی اس دن فائدہ مند قرار دے کہ جس دن مال واولاد کچھ کام نہ آئیںگے۔
محمد مہدی آصفی
قم مقدسہ
۲۸شوال ۱۴۱۲ھ
بِسْمِ ﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ
حدیث قدسی
عن الامام الباقرعليهالسلام :عن رسول ﷲصلىاللهعليهوآلهوسلم قال:یقول ﷲ عزوجل:
''وعزتی،وجلالی،وعظمتی،وکبریائی،ونوری،وعُلُوّی،وارتفاعِ مکانی، لایؤثرعبد هواه علیٰ هوای لاشتّتُ أمره،ولبّست علیه دنیاه،وشغلت قلبه بها،ولم أوته منهالاماقدّرت له وعزتی،وجلالی،وعظمتی،وکبریائی،ونوری،وعُلُوّی،وارتفاع مکانی، لایؤثرعبد هوای علیٰ هواه لااستحفظته ملا ئکتی،وکفّلت السماوات والارض رزقه،وکنت له من وراء تجارةکل تاجر،وأتته الدنیاوهی راغمة''( ۱ )
____________________
(۱)عدةالداعی:ص۷۹۔اصول کافی :ج۲ص۳۳۵۔بحارالانوار:ج۷۰ص۷۸۔بحار الانوار ج۷۰ ص۸۵ و ۸۶۔الجواہر السنیةفی الاحادیث القدسیة:ص۳۲۲۔اور شیخ محمد مدنی نے تقریباً انہیں الفاظ میں اسے :الاتحافات السنیةفی الاحادیث القدسیہ:ص۳۷پر نقل کیا ہے ۔
بِسْمِ ﷲالرَّحْمٰنِ الرَّحیمِ
حدیث قدسی
امام محمد باقر سے روایت ہے کہ رسول ﷲصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم کاارشاد ہے :
''میری عزت و جلالت ،عظمت وکبریائی ،نور ورفعت اور میرے مقام ومنزلت کی بلندی کی قسم کوئی بندہ بھی اپنی ہویٰ وہوس کو میری مرضی اور خواہش پر ترجیح نہیں دیگا مگر یہ کہ میں اسکے امور کو درہم برہم کردونگا اسکے لئے دنیا کو بنا سنوار دونگا ۔اسکے دل کو اسی کا دلدادہ بنا دونگا اور اسکو صر ف اسی مقدار میں عطا کرونگاجتنا پہلے سے اسکے مقدر میں لکھ دیا ہے''
''اورمیری عزت وجلالت،عظمت وکبریائی،نورورفعت اورمقام ومنزلت کی بلندی کی قسم کوئی بندہ میری مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح نہیں دیگامگر یہ کہ ملائکہ اسکی حفاظت کرینگے ۔آسمان اور زمین اسکے رزق کے ذمہ دار ہیں اور ہر تاجر کی تجارت کی پشت پرمیں اسکے ساتھ موجود ہوں گااور دنیا اسکے سامنے ذلت و رسوائی کے لبادہ میں حاضر ہوگی''
یہ حدیث شریف ان روایات میں سے ہے جن کی شہرت کتب فریقین میں مستفیضہ ہونے کی حد تک ہے ۔
ہم نے اس حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے جن میں سے بعض سندیں ہمارے نزدیک صحیح ہیں ۔
اس حدیث کی تشریح تین فصلوں میں پیش کی گئی ہے۔
پہلی فصل:ہوائے نفس کی تعریف ،اس کے عوارض کی تشخیص ،اسکے علاج اور اس پر قابو پانے کے راستے پر مشتمل ہے یہ فصل در حقیقت اس کتاب (حدیث کی تشریح)کا مقدمہ ہے ۔
دوسری فصل:اپنی خواہش کو خداوند عالم کی مرضی پر ترجیح دینے والوں کے ذکر میں ہے ۔
تیسری فصل:خداوند عالم کی مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح دینے والوں کے ذکر میں ہے ۔
پہلی فصل
خواہش
قرآن وسنت کی روشنی میں
''ہویٰ'' (خواہش)قرآن وحدیث
کی روشنی میں
ہویٰ (خواہش )ایک اسلامی اصطلاح ہے جو قرآن و حدیث سے ماخوذہے ۔اسلامی تہذیب میں اسکے اپنے ایک خاص معنیٰ مراد لئے جاتے ہیں۔
یہ لفظ قرآن اور احادیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے جیسا کہ ﷲ تعالی کا ارشاد ہے :
( أرایت من اتخذإلٰهه هواه أفأنت تکون علیه وکیلا ) ( ۱ )
''کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنالیا ہے کیا آپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہیں ''
دوسرے مقام پر ارشاد ہوتاہے:( وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهویٰ فإن الجنة هی المأویٰ ) ( ۲ )
''اور جس نے رب کی بار گاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے تو جنت اس کا ٹھکانا اور مرکز ہے ''
____________________
(۱)سورئہ فرقا ن آیت ۴۳۔
(۲)سورئہ نازعات آیت۴۰۔۴۱۔
سید رضی نے مولائے کائنات حضرت علی کا یہ قول نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے:
(إن أخوف ماأخاف علیکم إثنان:إتباع الهویٰ وطول الأمل )
''مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کاخوف رہتا ہے :خواہشات کی پیروی اورآرزووںکا طولانی ہونا ''
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم اور امام جعفر صادق دونوں سے ہی یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ آپ حضرات نے فرمایا :
(حذرواأهوائکم کماتحذرون أعدائکم،فلیس شی أعدیٰ للرجال من اتباع أهوائهم وحصائدألسنتهم )( ۱ )
'' اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرتے رہو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو۔ کیونکہ انسان کیلئے خواہشات کی پیروی اور زبان کے نتائج سے بڑاکوئی دشمن نہیں ہے۔''
اور امام جعفر صادق ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ:
(لاتدع النفس وهواها،فن هواهارداها )( ۲ )
'' نفس اور اسکی خواہشات کو ہرگز یونہی نہ چھوڑدینا کیونکہ نفسانی خواہشیں ہی اسکی پستی کا باعث ہیں''
بنیادی محرکات
انسانی زندگی میں نفس اور''خواہشات ''کیا کردار ادا کرتے ہیں اسکے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ خداوند عالم نے ہر انسان کو متحرک وفعال رکھنے اور علم وکمال کی جانب گامزن کرنے کے لئے
____________________
(۱)اصول کافی ج۲ص۳۳۵۔
(۲)گذشتہ حوالہ اسکے وجودمیں کچھ بنیادی محرکات رکھے ہیں اور انسان کی تمام ارادی اور غیر ارادی حرکات نیز اسکی مادی و معنوی ترقی ا نھیں بنیادی محرکات کی مرہون منت ہے یہ چھ محرکات ہیں اور ان میںبھی سب سے اہم محرک ''ہویٰ''یعنی خواہشات نفس ہے۔
۱۔فطرت:
اس کے ذریعہ خداوند عالم نے اپنی معرفت نیز وفاء ، عفت ،رحمت،اور کرم جیسے اخلاقی اقدارکی طرف رجحان کی قوت ودیعت فرمائی ہے۔
۲۔عقل :
یہ انسانی وجودمیں حق و باطل کے درمیان تشخیص اور تمیز دینے کی ذمہ دار ہے۔
۳۔ارادہ:
کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا انحصار اسی پر ہوتاہے اور شخصیت کا استقلال اسی سے وابستہ ہے۔
۴۔ضمیر:
عدل و انصاف پر مبنی درونی و باطنی آوازہے جس کا کام انسان کو صحیح فیصلہ سے آگاہ اور غلط باتوں پر اسکی توبیخ کرنا ہے تاکہ انسان حد اعتدال پر قائم رہے ۔
۵۔قلب ،صدر،:
آیات قرآنی کے مطابق علم ومعرفت کا ایک اور دروازہ ہے۔ اسی پر خداوند عالم کی جانب سے علم ومعرفت کی تجلی ہوتی ہے ۔
۶۔ہویٰ(خواہشیں):
وہ خواہشات اور جذبات جو انسان کے نفس میں پائے جاتے ہیںاور ہر حال میں انسان سے اپنی تکمیل کامطالبہ کرتے ہیں اور ان کی تکمیل کے دور ان انسان لذت محسوس کرتاہے انسان کو متحر ک رکھنے اور اسے علم ومعرفت سے مالا مال کرنے کے یہ اہم ترین محرکات ہیںجنہیںاللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میںودیعت فرمایاہے ۔سردست ان کی تعداداورتفصیلات کے بارے میں کسی قسم کی علمی اور تفصیلی گفتگو مقصودنہیں ہے ۔
نفسیات کے اس گوشہ پر ابھی اسلامی نقطہ نظر سے مزید غور وفکر اور بحث وجستجو کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کہ کو ئی ایسا بلند پایہ مفکر سامنے آجائے جو آیات و روایات کی روشنی میں اس گوشے سے متعلق فکری جولانیاں دکھا سکے۔۔فکر اسلامی کا یہ گوشہ نہایت شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ اچھوتابھی ہے اور یہی دونوں خصوصیات علماء و مفکرین کے اشہب فکر کو مہمیز کرنے کیلئے کافی ہیں۔
لہٰذا خدا وند کریم سے یہ دعا ہے کہ جو شخص اسلامی علوم کے خزانوں کے سہارے اس مہم کو سر کرنے کا بیڑا اٹھا ئے وہ اسکے لئے ہر طرح کی آسانیاں فراہم کردے ۔
فی الحال اس کتاب میں ہویٰ کے معنی ،اسکی تعریف ،اور انسانی زندگی میں اسکے کردار نیز اسکے خصوصیات ،اثرات ،اس سے مقابلہ کا طریقہ اور اس سے متعلق دوسرے امور کا جائزہ لینا مقصودہے لہٰذا ہم انسانی وجود میں موجود دوسرے محرکات سے صرف نظر کرکے صرف اور صرف''ہویٰ''خواہشوںکے بارے میں گفتگوکریںگے ۔
''ہویٰ'' کی اصطلاحی تعریف
جب ہم اسلامی علوم میں ہویٰ کے معانی تلاش کرتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب وتمدن میں ہویٰ ''انسان کے اندر پو شیدہ ان خواہشات اور تمنائوں کو کہا جاتا ہے جو انسان سے اپنی تکمیل کے خواہاں ہوتے ہیں ۔''
انسان کی شخصیت میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کو متحرک بنانے اوراسے آگے بڑھانے کا ایک بنیادی سبب نیز اسکی تمام ارادی اور غیرارادی حرکتوں کی اہم کنجی ہیں ۔
''ہویٰ''کے خصوصیات
انسانی زندگی کی تعمیر یا بربادی میں اسکی نفسانی خواہشوں کے مثبت اور منفی کردارسے وا قفیت کے لئے سب سے پہلے ان کی اہم خصوصیات کوجاننا ضروری ہے لہٰذا ہم آئندہ صفحات میں اسلامی نقطۂ نگاہ سے خواہشات نفس کے اہم خصوصیات کا جائز ہ لیں گے ۔
۱۔چاہت میںشدت
اپنی چاہت کی تکمیل میں بالکل آزاد اور بے لگام ہونا انسانی خواہشات کی سب سے پہلی اور اہم ترین خصوصیت ہے البتہ سیر ہو نے یانہ ہونے کے اعتبار سے اس کے مختلف درجات ہیں کیونکہ کچھ خواہشات تو ایسی ہو تی ہیں جن سے کبھی سیری نہیںہو پاتی اور چاہے جتنا بھی اس کی تکمیل کی جائے اس کی طلب اور چاہت میں کمی نہیںآتی ۔جبکہ کچھ خواہشات ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ سردتو پڑجاتی ہیں مگر بہت دیر کے بعد۔مختصر یہ کہ ان تمام خواہشات کے درمیان اعتدال اور توازن کے بجائے شدت طلبی ایک مشترکہ صفت ہے۔
جیسا کہ رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے ارشاد فرمایا ہے :
(لَوْکَانَ لِاِبْنِ آدَم وادٍمن مال لابتغیٰ لیه ثانیاً،ولوکان له وادیان لابتغیٰ لهماثالثاً،ولایملأ جوف ابن آدم لاالتراب )( ۱ )
''اگرفرزند آدم کے پاس مال ودولت کی ایک وادی ہو تی تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرتا اور اگر اس کے پاس ایسی ہی دو وادیاں ہو تیں تب بھی اس کو تیسری وادی کی تمنا رہتی اور اولاد آدم کا پیٹ مٹی کے علا وہ کسی اور چیزسے نہیں بھر سکتا ہے ''
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے یہ بھی فرمایا ہے :
(لوکان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغیٰ وراء هما ثالثاً )( ۲ )
''اگر آدمی کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو بھی اسے تیسری وادی کی تلاش رہے گی ''
جناب حمزہ بن حمران کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ مجھے جس چیز کی خواہش ہو تی ہے وہ مجھے مل جاتی ہے تب بھی میرا دل اس پرقانع نہیں ہوتا ہے اور مزیدکی خواہش باقی رہتی ہے ،لہٰذا مجھے کو ئی ایسی چیز تعلیم فر مائیے جس سے میرے اندر قناعت پیدا ہو جائے اور مزیدکی خواہش نہ رہے توامام نے فرمایا:
____________________
(۱)الجامع الصغیرللسیوطی بشرح المناوی۔ ج۲ص۲۲۰ط ۱۳۷۳۔
(۲)مجموعۂ ورام ص۱۶۳۔
''جو چیز تمہارے لئے کافی ہے اگر وہ تمھیں مستغنی بنا دے تو دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کا معمولی سا حصہ بھی تمھیں مستغنی بنا نے کے لئے کافی ہے اور جو چیز تمہارے لئے کافی ہے اگر وہ بھی تمہیں مستغنی نہ بنا سکے تو پھر پوری دنیا پاکر بھی تم مستغنی نہیں ہو سکتے ہو ''( ۱ )
امیرالمو منین فرمایا کرتے تھے :
''اے فرزندآدم، اگر تجھے دنیا صرف اتنی مقدار میںدرکارہو جو تیری ضروریات کے لئے کافی ہو سکے تو اس کا معمولی ساحصہ بھی تیرے لئے کافی ہے اور اگر تجھے وہ چیزبھی درکار ہے جو تیرے لئے ضروری نہیںتو پوری دنیا بھی تیرے لئے ناکا فی ہے ''( ۲ )
مذکورہ روایات میں خواہشات کی مزید طلب برقراررہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبھی ان کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے بلکہ ان کی شدت طلب کو بتانا مقصود ہے اور یہ کہ عموماًخواہشات حد اعتدال پر قائم نہیں رہتے ۔ورنہ بعض خواہشات ایسی ہو تی ہیں جو زند گی کے آخری مرحلہ میں بالکل کمزور پڑجاتی ہیں حالانکہ کچھ ایسی خواہشات بھی ہیں جوانسان کے آخری سانس تک بالکل جوان رہتی ہیں اور ان میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہو تی ہے ۔( ۳ )
____________________
(۱)اصول کافی ج۲ص۱۳۹۔
(۲)بحار الانوار ج ۷۳ ص ۱۷۰۔
(۳)انس نے رسول سے (جامع صغیر سیوطی حر ف (ی)ج۲ص۳۷۱)پر روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ٔ''فرزند آدم بالکل بوڑھا پھوس ہوجاتا ہے مگر اس کے ساتھ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں لالچ اور آرزو ۔''
میں خداوند عالم کے ایک ایسے بندہ ٔصالح کو پہچانتاہوںجس نے توفیق الٰہی کے سہارے جوانی میں ہی اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرلیا تھا۔ جب ان کی عمر ۹۰سال کے قریب ہوئی توان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ بنیادی طور پر صرف تین خواہشات ہیں : ۱۔جنسیات ۲۔مال ۳۔عہدہ پہلی دو خواہشات کو تو میں نے اپنی جوانی میںہی رام کرکے ان پر غلبہ حاصل کرلیاتھا لیکن تیسری خواہش اب بھی میرے دل میں مسلسل ابھرتی رہتی ہے اور مجھے اس کی بنا پر شرک میں پڑنے کا خطرہ لاحق رہتاہے۔
۲۔خواہشات میں تحرک کی قوّت
خواہشات، انسان کی حرکت و فعالیت کا سب سے اہم اور طاقتور ذریعہ ہیں اور ان کے اندر پائی جانے والی قوت متحرکہ کے بارے میں صرف اتنا کہناکافی ہے کہ خواہشات نفس و ہ تنہا سبب ہیں جوجاہلانہ تہذیب و تمدن کو پروان چڑھاتے رہے ہیں اورتاریخی نیز جغرافیائی لحاظ سے یہی جاہلانہ تمدن روئے زمین کے بیشتر حصوں پر حکم فرمارہاہے ۔اس جاہلانہ تمدن میں فطرت،ضمیراورعقل کی حکم فرمائی کا سرے سے انکار تو نہیں کیا جاسکتاہے لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اس تمدن کی پیشرفت میں خواہشات ہی سب سے بڑاعامل اور سبب ہیں چاہے وہ جنگ و صلح کے معاملات ہو ں یا اقتصاد اور علو م وفنون کے میدان یا دیگر جرائم سب اسی کی کوکھ سے جنم لیتے رہے ہیں ۔
انسانی تاریخ کے بیشتر ادوارمیںجاہلیت کی حکمفرمائی دیکھنے کے بعد خواہشات میں پائی جانے والی قوت متحرکہ کی وسعت کا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتاہے۔روایت میں ہے کہ جناب زیدبن صوحان نے امیر المومنین سے سوال کیا :
(ای سلطان اغلب وأقویٰ) '' کس بادشاہ کا کنٹرول اور غلبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا : (الھوی)'' خواہشات کا ۔''( ۱ ) اسی طرح قرآن مجید نے عزیز مصر کی بیوی کا یہ اقراری جملہ نقل کیا ہے :
( إن النفس لأمارة بالسوء إلامارحم ربی ) ( ۲ )
''نفس تو برائیوں کی طرف ہی اکسا تاہے مگر یہ کہ جس پرخدا رحم وکرم کردے (وہی اس سے ۔
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۰ص۷۶حدیث۶۔
(۲)سورئہ یوسف آیت ۵۳۔علمائے نحو کے بقول اس جملے میں نحوی اعتبارسے اتنی تاکیدیں پائی جاتی ہیں جو بہت کم جملوں میں ہوتی ہیں جیسے یہ جملہ اسمیہ ہے اور اسکی ابتداء میں انّ پھرا مارہ صیغۂ مبالغہ اور اسکے شروع میں لام تاکید یہ سب کثرت تاکید کی علامتیں ہیں۔
محفوظ رہ سکتا ہے)''یہ مختصر سا جملہ انسانی زندگی پر خواہشات کے مستحکم کنڑول کی ایک مضبوط سند ہے ۔
اور امیر المومنین سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:
(الخطایا''الشهوات''خیل شُمُس حُمِل علیهاأهلها،وخُلِعَت لُجُمها،فتقحمت بهم فی النار،ألاوان التقویٰ مطایاذُلُلُ،حُمِل علیهاأهلها،واُعطواأزِمّتها،فأوردتهم الجنة )( ۱ )
'' خطائیں اور''خواہشات'' وہ سرکش گھوڑے ہیں جن پر کسی کو سوار کرکے انکی لگام اتاردی جائے اور وہ اپنے سوار کو لیکر جہنّم میں پھاند پڑیں لیکن تقویٰ وہ رام کی ہوئی سواریاں ہیں جن پر صاحبان تقویٰ کو سوار کرکے ان کی لگام انکے ہاتھ میں دیدی جائے اور وہ ان کو جنّت میں پہونچادیں ''
شمس در اصل شموس کی جمع ہے اور شموس اس سرکش اور اڑیل گھوڑے کو کہتے ہیں جو کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا اورنہ ہی سوار کا تابع رہتاہے۔گویاسوار اسے لگام لگائے بغیر اس پر سوار ہوگیا تووہ اسکے قابو میں نہیںرہتااور وہ سوار کو لے اڑتاہے اور سواربھی اسے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا ۔یہی حال خواہشات کا بھی ہوتا ہے جو اپنے اسیرانسان کوہر طرف لئے پھرتی ہیں اور وہ ان خواہشات کو صحیح جہت نہیں دے پاتا اور ان پر اپنا قابو اسی طرح کھو بیٹھتا ہے جس طرح ایک سرکش گھوڑا بے قابو رہتا ہے۔
اسکے برخلاف تقویٰ انسان کو اسکے خواہشات نفس اور ہوی وہوس پر قابو رکھنے کی قوت عطا کرتا ہے اور نفس کو اسکا مطیع اور فرمانبردار بنا دیتا ہے جسکے بعدانسان جدھر چاہے انکا رخ موڑ سکتا ہے اورانہیں خواہشات کے ذریعہ وہ جنت میں پہنچ سکتا ہے ۔
۳۔خواہشات اور لالچ کی بیماری
طمع اور لالچ خواہشات کی تیسری خصوصیت ہے جس کی بنا پر خواہشات کی طلب میں
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۱۵۔
اوراضافہ ہوجاتا ہے اور اسکی خواہش بڑھتی رہتی ہے ۔جبکہ دیگر مطالبات میں معاملہ اسکے بالکل بر عکس ہوتاہے کیونکہ جب انسان کسی اور مطالبہ کو پورا کرتا ہے تو اسکی گذشتہ شدت اور کیفیت و کمیت باقی نہیں رہتی بلکہ شدت میں کمی آتی ہے اورسیرابی کا احساس ہوتاہے ۔
لیکن خواہشات( ۱ ) کامعاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے مطابق عمل کرتے رہیں تو ان کی طلب میں اضافہ ہوتاجاتاہے ،ان کی چاہت کا لاوا مزید ابلنے لگتاہے ۔جسکے بعد دھیرے دھیرے ان پر انسان کا کنٹرول نہیں رہ جاتا لیکن اگر معقول ضابطہ کے تحت ،اعتدال کے دائرہ میںرہ کر ان خواہشات کو پورا کیا جائے تو پھر ان کے مطالبات خود بخود سردپڑجاتے ہیںاورانسان بخوبی انکے او پر غلبہ حاصل کرلیتاہے۔
مختصر یہ کہ بالکل آگ کی طرح ہوتی ہیں کہ اس میں جتنی زیادہ پھونک ماری جاتی ہے اسکے شعلے مزیدبھڑکنے لگتے ہیں اسکی لپٹیںاور بلند ہو جا تی ہیں ۔لہٰذا شرعی حدود میں رہ کر مناسب اور معقول انداز میں ان خواہشات کو پورا کرناان کو آزاد اور بے لگام چھوڑدینے سے بہتر ہے کیونکہ اگر بلاقید و شرط ان کی پیروی کی جائے تو ہر قدم پر تشنگی کا احساس ہوتارہے گااور خواہشات پر انسان کا اختیاربالکل ختم ہو جائے گا ۔
ان دونوں ہی باتوں کی طرف روایات میں اشارہ موجود ہے۔
۱۔خواہشات کی بلاقید و شرط تکمیل سے ان کی شدت میں اور اضافہ ہوتاہے اور ان کے مطالبات بڑھتے ہی رہتے ہیں اور اسکے برعکس اگر صرف شرعی حدود کے دائرہ میںان کی تکمیل ہوتو سیرابی حاصل ہوتی ہے ۔جیسا کہ مولائے کائنات نے فرمایا ہے:
(ردالشهوة أقضی لها،وقضاؤهاأشدّلها )( ۲ )
____________________
(۱)خواہشات سے ہماری مراد تمام چاہتیں نہیں ہیں ۔کیونکہ بعض چاہتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ قاعدہ درست نہیں ہے ۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۳۸۰۔
''شہوت اور خواہش کو ٹھکرادینا ہی اسکے ساتھ بہترین انصاف ہے اور اسکو پورا کرنا اسے مزید بڑھاوا دینا ہے۔''
یہاں خواہش کو ٹھکرادینے سے مراد محدود اور معقول پیمانہ پر ان کی تکمیل ہے ۔اور تکمیل سے مراد انہیںبے لگام چھوڑدینا اور ان کی تکمیل میں کسی قاعدہ و قانون کا لحاظ نہ رکھناہے۔
۲۔خواہشات کی بے جاتکمیل اور اس راہ میں افراط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کے سامنے انسان اتنابے بس اور مجبورہو جاتا ہے کہ اپنی خواہشات پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتااوروہ ان کاغلام اور نوکر بن کر رہ جاتا ہے لیکن اس کے برخلاف اگر انسان واقعاً کسی اصول وضابطہ کے مطابق محدود پیمانہ پران کی تکمیل کرے تو پھر اپنی خواہشات پر اسکا مکمل اختیار رہتا ہے اور وہ انہیں جدھر چاہے موڑسکتاہے۔
امام محمد باقر کا ارشاد ہے :
(مثل الحریص علی الدنیاکمثل دود القز،کلماازدادت من القزعلی نفسها لفّاًکان أبعد لها من الخروج حتیٰ تموت )( ۱ )
دنیا کے لالچی انسان کی مثال ریشم کے اس کیٹرے جیسی ہے کہ جو اپنے اوپر جتنا ریشم لپیٹا جاتاہے اسکے نکلنے کا راستہ اتنا ہی تنگ ہوتاجاتا ہے اور آخر کا روہ موت کے منھ میں چلا جاتا ہے۔
____________________
(۱)بحار الانوارج۷۳ص۲۳۔
خواہشات پر عقل کی حکومت
اگر چہ انسان پرخواہشات کی حکومت بہت ہی مستحکم ہوتی ہے لیکن عقل کے اندر ان خواہشات کو کنٹرول کرنے اور انہیں صحیح رخ پرلانے کی مکمل صلاحیت اورقدرت پائی جاتی ہے۔بشرطیکہ انسان خواہشات پر عقل کو فوقیت دے اور اپنے معاملات زندگی کی باگ ڈورعقل کے حوالہ کردے۔
صرف یہی نہیں بلکہ جس وقت خواہشات پر عقل کی گرفت کمزور پڑجاتی ہے اور خواہشات اسکے دائرہ اختیار سے باہر نکل جاتے ہیں تب بھی عقل کی حیثیت حاکم و سلطان کی سی ہوتی ہے وہ حکم دیتی ہے ،انسان کو برے کامو ںسے روکتی ہے،اور خواہشات ،نفس کے اندرصرف وسوسہ پیدا کرتے ہیں حضرت علی نے فرمایاہے:
(للنفوس خواطرللهویٰ،والعقول تزجروتنهی )( ۱ )
''نفسوں کے اندرمختلف خواہشیں سر ابھارتی ہیںاور عقلیں ان سے مانع ہوتی ہیں اورانہیں روکتی رہتی ہیں''
آپ ہی سے منقول ہے :
(للقلوب خواطرسوئ،والعقل یزجرمنها )( ۲ )
''دلوںمیں برے خیالات آتے ہیں اور عقل ان سے روکتی رہتی ہے''
اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات کی بناء پر انسان کے نفس میں صرف برے خیالات،اوہام اور وسوسے جنم لیتے ہیں لیکن عقل کے پاس انہیں کنڑول کرنے نیز ان سے روکنے کا اختیار موجود ہے اور اس کی حیثیت حاکم و سلطان کی سی ہے۔ اسی لئے مولائے کائنات نے فرمایاہے:
(العقل الکامل قاهرللطبع السُّوئ )( ۳ )
''عقل کامل ،بری طبیعتوں پر غالب ہی رہتی ہے''
جسکا مطلب یہ ہوا کہ انسانی مزاج اور اسکا اخلاق، بے جا خواہشات کی بناء پر بگڑکرچاہے جتنی پستی میں چلاجائے تب بھی عقل کی حکومت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے اور عقل سلیم وکامل اپنے اندر
____________________
(۱)تحف العقول ص۹۶۔
(۲)غررالحکم ج۲ص۱۲۱۔
(۳)بحار الانوارج۱۷ص۱۱۶۔
ہر قسم کی بری طبیعت اور مزاج کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔یہ اسلامی تربیت کا ایک اہم اصول ہے جسکے بارے میں ہم آئندہ تفصیل سے گفتگوکریں گے۔
انسان ،عقل اور خواہش کا مجموعہ
یہاں تک ہم اس واضح نتیجہ تک پہونچ چکے ہیں کہ خواہشیں کتنی ہی قوی اورموثر کیوں نہ ہوںلیکن وہ انسان سے اسکاارادہ اور قوت ارادی کونہیں چھین سکتی ہیں۔بشرطیکہ انسان عقل کو کامل بنالے اور معاملات زندگی میں عقل کو اہمیت دیتارہے کیونکہ انسان، عقل اور خواہشات سے مل کر بنا ہے لہٰذاعقل اور خواہشات کے باعث انسان ہمیشہ ترقی و تنزلی کی منزلیںطے کرتارہتاہے انسان اپنے معاملات حیات میں جس حد تک عقل کی حاکمیت کا قائل ہوگا اور اپنی عقل کے تکامل کی کوشش کرے گا اسی حد تک ترقی اور کمال کی جانب قدم بڑھائے گا اسکے برخلاف عقل کو بالکل نظر انداز کرکے اور اس سے غافل ہو کراگرخواہشات کوعقل پر ترجیح دے گاتو اسی کے مطابق پستیوں میں چلاجائے گا۔
لیکن حیوانات کی زندگی کا معاملہ انسان کے بالکل بر خلاف ہے کیونکہ ان کے یہاں کہیں سے کہیں تک عقل کا گذر نہیں ہے اوروہاںسوفیصد خواہشات کی حکومت ہوتی ہے گویا وہ صرف ایک سبب کے تابع ہوتے ہیںاوران کی زندگی صرف اسی ایک سبب کے تحت گذرتی ہے۔مولائے کائنات کا ارشاد ہے:
(إن ﷲ رکّب فی الملائکة عقلا ًبلا شهوة،ورکّب فی البهائم شهوةبلاعقل،ورکّب فی بنی آدم کلیهمافمن غلب عقله شهوته فهوخیرمن الملائکة،ومن غلبت شهوته عقله،فهوشرمن البهائم )( ۱ )
''خداوند عالم نے ملائکہ کو صرف عقل دی ہے مگرخواہشات نہیں دیںاورحیوانات
____________________
(۱)وسائل الشیعہ،کتاب الجھاد:جہاد النفس باب ۹ح۲۔
کو خواہشات دی ہیں مگر عقل سے نہیں نوازا ،مگر اولاد آدم میں یہ دونوںچیزیں ایک ساتھ رکھی ہیں لہٰذا جسکی عقل اس کی خواہشوں پر غالب آجائے وہ ملائکہ سے بہتر ہے اور جس کی خواہشیں اسکی عقل پر غلبہ حاصل کرلیں وہ حیوانات سے بدتر ہے ''
خواہشات کی شدت اورکمزوری
اسلامی تہذیب کاایک اہم مسئلہ خواہشات کی شدت اورکمزوری کا بھی ہے۔کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی خواہش نہایت مختصر اور کم ہواور ممکن ہے کہ بعض خواہشات بھڑک کرشدت اختیار کرلیں ۔ چنانچہ اگر یہ مختصر ہوگی تو اس پر عقل حاکم ہوگی اور آدمی ،انسان کامل بن جائے گا اوراگر یہی خواہشات شدت اختیار کرلیں تو پھر ان کا تسلط قائم ہوجاتا ہے اور انسان،حیوانیت کی اس پستی میں پہنچ جاتا ہے جہاں صرف اور صرف خواہشات کا راج ہوتاہے اور عقل وشعور نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے ۔
انسان چاہے اس حالت کے ماتحت ہو یا اس حالت کے ماتحت ہو ہرصورت میں خواہشات کی کمی یا زیادتی کا دارومدار خود انسان کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ جب وہ خواہشات کا تابع ہوتاہے اور ان کے تمام مطالبات کو پورا کرتاہے تو خواہشات اور بھڑک اٹھتی ہیں اور انسان کو مکمل طور پر اپنا اسیر بنالیتی ہیںاور انسانی زندگی میں ایک مضبوط قوت کے روپ میں ابھرتی ہیں اور انسان کی زندگی میں ان کاکردار بہت اہم ہوتا ہے۔
اوراسی کے برعکس جب انسان اپنی خواہشات پرپابندی لگاتارہے اوران کوہمیشہ حداعتدال میں رکھے اور خواہشات پرانسان کا غلبہ ہواور وہ عقل کے ماتحت ہوں تو پھر اسکی خواہشات ضعیف ہوجاتی ہیں اور انکا زور گھٹ جاتاہے ۔
ایک متقی کے اندر بھی وہی خواہشات ہوتے ہیں جو دوسروں کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ متقی افراد خواہشات کو اپنی عقل و فہم کے ذریعہ اپنے قابو میں رکھتے ہیں جبکہ بے عمل افرادپر ان کے خواہشات حاکم ہوتے ہیں اورخواہشات ان کو قابو میںکرلیتے ہیں۔ اس دور اہے پر انسان کوکوئی ایک راستہ منتخب کرناہے وہ جسے چاہے اختیار کرے۔ خواہشات کو کچل کر ان کا مالک ومختا ر بن جائے یا انکی پیروی کرکے ان کاغلام ہوجائے۔
آئندہ صفحات میں ہم خواہشات پرغلبہ حاصل کرنے کے کچھ طریقے ذکر کریںگے لیکن فی الحال آیات وروایات کی روشنی میں ان باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن سے خواہشات کی کمزوری یاشدت اور ان صفات کے اسباب کا علم حاصل ہوتاہے۔
سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات ملاحظہ فرمائیں۔ﷲتعالیٰ ارشادفرماتاہے:
( ولکن ﷲ حبَّب لیکم الایمان وزیَّنه فی قلوبکم وکَرَّه إلیکم الکفروالفسوق والعصیان ) ( ۱ )
''لیکن خدا نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کردیا ہے اور کفر،فسق اور معصیت کو تمہارے لئے ناپسندیدہ قرار دیدیا ہے ''
فسوق (برائی) کی یہ نفرت خداوند عالم نے مومنین کے دلوں میں پیداکی اور اہل تقویٰ اس سے ہمیشہ متنفر رہتے ہیںمگرفاسقین اس پرلڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں اسکے واسطے جان توڑ کوشش کرتے ہیں اور اس کی راہ میں بیش قیمت اشیاء کو قربان کردیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ کس ذات نے اس برائی کو مومنین کی نظروں میں قابل نفرت بنادیا؟ کون ہے جس نے فاسقوں کی نگاہ میں اسے محبوب بنادیا؟یقینا خدا وند عالم ہی نے مومنین کو اس سے متنفر کیا ہے۔کیونکہ مومن کا دل خداکے قبضۂ قدرت میں رہتا ہے لیکن برائیوں کو فاسقوں کیلئے پسندیدہ بنانے والی چیز خود ان برائیوں اور خواہشات کی تکمیل نیزان کوہرقیمت پر انجام دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جسکی بناپر وہ ان کی
____________________
(۱)سورئہ حجرات آیت۷۔
من پسند چیز بن جاتی ہے ۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے روایت ہے:
(المداومة علیٰ الخیرکراهیة الشر )( ۱ )
''کار خیر کی پابند ی برائیوں سے بیزار و متنفر کرتی ہے''
یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اگر مسلسل کا رخیر کی پابندی کی جاتی رہے تو خود بخود شر اور برائی سے نفرت پیدا ہوجاتی ہے شر سے مراد انسان کی وہ خواہشات اور لذتیں ہیںجن کے پیچھے لوگ دوڑتے رہتے ہیں۔ یعنی فاسق اور گمراہ لوگ انھیں حرام خواہشات ولذائذ کے متلاشی رہتے ہیں۔
اس کے برعکس ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کارخیرکی پابندی کے باعث برائی سے نفرت ہوجاتی ہے اسی طر ح یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ''برائیوں کی پابندی سے برائیوں کی محبت پیدا ہوجاتی ہے''
خطبہ متقین جو خطبہ ہمام کے نام سے مشہور ہے اس میں امیر المومنین کا یہ ارشاد ہے: (تراه قریباًأمله،قلیلاًزلَله،خاشعاًقلبه،قانعةنفسه،منزوراًأکله،سهلاًأمره، حریزاًدینه،میتةً شهوته،مکظوماًغیظه )( ۲ ) '' متقین کی پہچان یہ ہے کہ ان کی آرزوئیں بہت مختصر ،لغزشیںکم،دل خاشع،نفس قانع، غذا معمولی،معاملات آسان،دین محفوظ ،خواہشات مردہ اور غیظ و غضب اور غصہ ٹھنڈارہتاہے''
بیشک تقویٰ شہوات اور خواہشات کو مختصر اور سادہ بنا دیتا ہے جسکے نتیجہ میں حریص اور لالچی نفوس بھی متقی اور قانع ہو جاتے ہیںاور انکی خواہشات گھٹ کر گویا مردہ ہوجاتی ہیں۔
البتہ اس طرح کی روایات نقل کرنے سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ تقویٰ ،خواہشات کو لگام
____________________
(۱)بحارالانوارج۱ص۱۱۷۔
(۲)نہج البلا غہ خطبہ ۹۵(ہمام)
لگاکر ایک دم روک دیتا ہے( اگر چہ یہ بات اپنی جگہ پر کسی حد تک درست ہے )۔بلکہ نفس کے اوپر تقویٰ کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کو بہت ہی ہلکا اور سادہ بنادیتا ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم نے مذکورہ روایات بیان کی ہیں اب حضرت علی سے مروی مندرجہ ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں جنہیں ہم بغیر کسی تبصرہ کے پیش کررہے ہیں:
(کلما قویت الحکمة،ضعفت الشهوة )( ۱ )
''جس قدر حکمت قوی ہوگی خواہش اتنی ہی کمزور ہوجائے گی''
(اذاکثرت المقدرة قلت الشهوة )( ۲ )
''جب قدرت زیادہ ہوگی تو شہوت کم ہوجائے گی''
(العفة تضعف الشهوة )( ۳ )
''عفت اور پاکدامنی شہوت کو کمزور بنادیتی ہے''
(من اشتاق الیٰ الجنة سلا من الشهوات )( ۴ )
''جو جنت کا مشتاق ہوا وہ خواہشات سے بری ہوگیا ''
(واذکرمع کل لذة زوالها،ومع کل نعمة انتقالها،ومع کل بلیة کشفها فن ذلک أبقیٰ للنعمة،وأنقیٰ للشهوة،وأذهب للبطر،وأقرب للفرج، وأجد ر بکشف الغمةودرک المأمول )( ۵ )
____________________
(۱)غررالحکم ج۲ص۱۱۱۔
(۲)بحار الانوار ج۷۲ص۶۸ونہج البلاغہ حکمت ۲۴۴۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۱۱۸۔
(۴)نہج البلاغہ حکمت ۳۱۔
(۵)غررالحکم۔
''ہر لذت کے ساتھ اسکے زوال پر، ہر نعمت کے ساتھ اسکے منتقل ہونے اورہر بلاکے ساتھ اسکے رفع ہونے پر بھی نظر رکھو کیونکہ یہ نعمت کو تادیر باقی رہنے، شہوت کو صاف و پاکیزہ بنانے ،نعمت پر اترانے اور اسکی ناشکری کو ختم کرنے ،آسانی اور کشادگی کو قریب کرنے ،مشکلات اور پیچیدگیوں کودور کرنے نیزآرزووں کی تکمیل کے لئے سب سے زیادہ مناسب ہے۔''
تقویٰ اورضبط نفس کاتسلط انسانی خواہشات اور آرزووں پر اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ انسانی خواہشات کو حدود الٰہیہ کے سانچہ میں ڈھال دیتے ہیں جسکے بعد انسان صرف وہی چاہتااور پسند کرتا ہے جو خداوند عالم پسند کرتا ہے اور صرف اسی سے نفرت اور کراہت محسوس کرتا ہے جس سے خداوندعالم نفرت کرتاہے اور یہ انسانی نفس اور حدود الٰہیہ کے آپسی رابطہ کی آخری حد ہے اسی عجیب و غریب انقلاب کی طرف اس آیۂ کریمہ نے اشارہ کیا ہے :
(وکرَّه لیکم الکفر والفسوق والعصیان )( ۱ )
''اور کفر،فسق اور معصیت کو تمہارے لئے ناپسندیدہ قرار دیدیا ہے ''
اس مرحلہ میں تقویٰ کاانسان پر صرف یہی اثر نہیںہوتا ہے کہ وہ کفر،فسق وفجور اور گناہ سے دوررہتا ہے بلکہ تقویٰ انسان کو ان باتوں سے متنفر بھی کردیتا ہے۔
انسانی زندگی میں خواہشات کا مثبت کردار
انسانی زندگی میں اسکی خواہشوں کی تباہ کاریوں کو دیکھنے کے بعد ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ ان کی اتنی تباہ کاریوںکے باوجودبھی خداوند عالم نے انسان کے اندر ان خواہشات کو کیوں پیدا کیا ہے؟اور ان کاکیا فائدہ ہے ان میںایساکونسا مثبت پہلو پایاجاتا ہے جسکی بناپر انہیں خلق کیا گیا ہے؟اگر چہ آئندہ ہم خواہشات کی تباہ کاریوں اور اسکے منفی اثرات کا جائزہ لیں گے
____________________
(۱)سورئہ حجرات آیت۷۔
لیکن فی الحال اسکے مثبت اثرات اور فوائد کا تذکرہ کررہے ہیں۔
۱۔انسانی زندگی کا سب سے طاقتور محرک
انسانی خواہشات اس کی زندگی میں سب سے بڑا محرک ہیں کیونکہ ﷲ تعالیٰ نے حیات انسانی کے اہم ترین پہلوئوں کو انہیں خواہشات سے جوڑدیا ہے اوریہی خواہشات اسکی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی کی ضامن ہیں۔
جیسے تولیدنسل، انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان صفحہ ہستی سے نابود ہوکر رہ جائے گا۔لہٰذا افزائش نسل اوراسکی بقاکے لئے کوئی ایساذریعہ یا جذبہ در کار تھا جسکی بنا پر نسل انسانی باقی رہے۔چنانچہ اس اہم مسئلہ کو خداوند عالم نے جنسی خواہشات سے جوڑکر بقائے انسانیت کا سامان فراہم کردیا۔
اسی طرح جسمانی نشوونما کو کھانے پینے سے جوڑ دیا اگر آب ودانہ کی یہ خواہش نہ ہوتو انسانی جسم نمو نہیں پاسکتا اور مسلسل جد و جہد کی وجہ سے اسکے بدن میں جو کمزوری پیدا ہوجاتی ہے اس کی کمی پوری نہیں ہوسکتی تھی اور اسکے بدن میں جو خلیے مردہ ہوجاتے ہیں ان کی جگہ زندہ خلیے حاصل نہ ہوپاتے۔
اسی طرح خدا وند عالم نے اجتماعی زندگی کے لئے نفس میں سماج کی جانب رغبت اوررجحان کا جذبہ رکھا ہے اگر یہ جذبہ نہ ہوتاتو سماجی زندگی انتشار کا شکار ہوجاتی اور انسانی تہذیب و تمدن تارتار ہوجاتا۔
انسانی زندگی کے اقتصادی اور معاشی حصہ میں ملکیت اورمالکیت کا جذبہ کا رفرما رکھا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو پھر اقتصادی نظام بالکل برباد ہوجاتا ۔
جان ،مال،ناموس اورعزت و آبرو کے تحفظ کیلئے قوت غضب رکھی گئی ہے اگر انسان کے اندر یہ قوت نہ رہے تو پھر ہر سمت دشمنی کارواج ہوگا اور کہیںبھی امن وامان کا نام ونشان باقی نہ رہے گا
اسی طرح انسان کے وہ دوسرے تمام ضروریات جن کے بغیر اسکے لئے روئے زمین پر زندگی گذار ناممکن نہیںہے ان کے لئے بھی خداوند عالم نے کوئی نہ کوئی جذبہ اور خواہش ضرور رکھی ہے اور اسی خواہش کے ذریعہ ان ضروریات کی فراہمی کا انتظام کیا ہے۔
۲۔خواہشات ترقی کا زینہ
خواہشات انسانی زندگی میں ترقی کا زینہ ہیںاسی کے ساتھ یہ وہ پھسلن بھرا راستہ بھی ہے جس پر چل کرانسان پستیوں میںبھی پہنچ سکتا ہے۔اوراسی زینہ کے ذریعہ خدا تک بھی پہونچ سکتا ہے یہی زینہ انسان کی ترقی اور تکامل میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جسکی تفصیل کچھ یوں ہے۔
قرب خدا کی جانب انسان کا سفر اور اسی طرح انسان کی نشو ونما کادارو مداراس کے ''ارادہ''پر ہے جبکہ جمادات ،حیوانات اورنباتات کی نشو و نما اور ان کاتکاملی سفر ایک فطری اور قہری انداز میں انجام پاتاہے۔اور اس میں ان کے کسی ارادہ کا دخل نہیں ہوتا ہے لیکن انسان کو خداوند عالم نے ''ارادہ''کے ذریعہ یہ خاص شرف بخشا ہے کہ اس کی ہر حرکت ،ہر کام اسکے اپنے ارادہ واختیار کے تحت انجام پاتاہے ۔ انسان اور کائنات کی دوسری تمام اشیاء مشیت وارادہ ٔ الٰہی کے تابع ہیں اس اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ساہے کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ مشیت الٰہی کا تابع ہوتا ہے اوربقیہ کا ئنات فطری اورقہری طور پر یعنی اپنے ارادہ و اختیار کے بغیر مشیت الٰہی کے مطابق چلتی رہتی ہے۔
احکام الٰہی در اصل خدا کی مشیت اور اس کے ارادہ کا مظہر ہیں جن پر بندہ اپنے اختیار سے چلتا ہے اسی طرح سنن الٰہی بھی مشیت و ارادہ الٰہی کامظہر ہیں جن پر جمادات نباتا ت اور حیوانات اپنے ارادہ و اختیار کے بغیر رواں دواں ہیں۔
اسی لئے انسان کو قرآن مجید میں:(خلیفة ﷲ)قرار دیا گیاہے( ۱ ) اور اسکے علاوہ پوری کائنات کو (مسخرات بأ مرہ)''اسکے حکم کی تابع ''کہا گیا ہے۔( ۲ )
____________________
(۱)سورئہ بقرہ آیت۳۰۔
(۲)سورئہ اعراف آیت ۵۴وسورئہ نحل آیت ۱۲و۷۹۔
خلافت اور تسخیر کے درمیان ایک چیز مشترک ہے اور ایک لحاظ سے ان کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ان کا مشترک پہلو یہ ہے کہ دونوں ہی مشیت و ارادئہ الٰہی کے تابع اور مطیع ہیں البتہ اس لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ خلیفہ خدا (انسان)اپنے ارادہ و اختیار سے حکم الٰہی کی پابندی کرتا ہے اور(والمسخرات بامرہ) تقریباًمشینی اندا ز میں اپنے کسی ارادہ و اختیار کے بغیر حکم خدا پر چلتے رہتے ہیں۔
اور یہی نکتہ انسان کی عظمت و بلندی کا راز ہے کیونکہ اگر وہ بھی اپنے قصد و ارادہ سے خداوند عالم کی اطاعت نہ کرتااور مجبور ہوتا تو پھر اسکے اور بقیہ پوری کائنات کے عمل میں کوئی فرق نہ ہوتااور اس کے عمل کو کسی قسم کا امتیاز یا برتری حاصل نہ ہوتی۔
اسی ارادی اور اختیاری اطاعت نے دیگر مخلوقات کے مقابل انسان کوخلافت الٰہیہ کا اہل بنایا ہے اور اسی بناء پر اسکے ہر عمل کی قدروقیمت بھی اسکی محنت و مشقت کے متناسب ہوتی ہے۔
چونکہ ارادی عمل میں جسمانی زحمت کے ساتھ نفسیاتی اور روحانی زحمت ومشقت بھی برداشت کرنا پڑتی ہے لہٰذاخدا کے نزدیک اس عمل کی قدروقیمت زیادہ ہونی ہی چاہئے ۔ارادی عمل سے پیدا ہونے والی حرکت میں سرعت و استحکام بھی زیادہ ہونا چاہئے لہٰذا یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان تو کسی عمل کیلئے باقاعدہ زحمتیں اٹھائے اور دوسرا شخص بغیر کسی مشقت کے کوئی عمل انجام دے اور قدرو قیمت کے اعتبار سے دونوں برابر قرار د یدئے جائیں ۔
جیسے'' کھانے پینے'' اور'' روزہ رکھنے'' کے درمیان زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے جبکہ چاہے کھانا پینا ہو اور یا روزہ ہو یہ سب اعمال قصد وارادہ اور حکم الٰہی کی اطاعت کے جذبہ سے انجام پاتے ہیں لیکن کھانے پینے میں چونکہ انسان کے ارادہ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا اور اس میں اسے کسی قسم کی زحمت ومشقت نہیں ہوتی ہے اورچونکہ ہرعمل کی قیمت کا اندازہ اس عمل کی راہ میں ہونے والی اس محنت و مشقت کو دیکھکر لگایا جاتا ہے جو اس عمل کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کیلئے درکار ہوتی ہے اور کیونکہ کھانے پینے میں ایسی کوئی خاص زحمت نہیں ہے لہٰذاروزہ کے برخلاف اس عمل کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے۔
جس عمل میں زحمت و مشقت کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اس عمل کی قدروقیمت بھی اسی اعتبار سے بڑھتی رہے گی۔اور ایسا عمل انسانی ترقی اور قرب الٰہی کے سفر میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوتاہے ۔ لہٰذا اصل حیثیت عمل پر صرف ہونے والی محنت ومشقت کی ہے اور اگر یہ محنت و مشقت نہ ہو تو پھر عمل بالکل بے قیمت ہوکر رہ جاتاہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زحمت ومشقت کیا ہے؟یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟اور اسکے درجات مختلف کیوں ہوتے ہیں؟
اس زحمت و مشقت کودینی اصطلاح میں''ابتلا''یعنی امتحان اور آزمائش کہا جاتا ہے اور یہ زحمت و مشقت خواہشات اور آرزووںکے وقت ظاہرہوتی ہے کیونکہ اگر ہمارے وجود میں خداوند عالم کی ودیعت کردہ یہ خواہشات نہ ہوتیں یا اسی طرح ان خواہشات کی مخالفت کے بغیر اطاعت ممکن ہوتی تو پھر ہمارے کسی عمل کی کوئی قیمت باقی نہ رہ جاتی اور کوئی عمل بھی قرب الٰہی کا ذریعہ نہیں بن سکتاتھا۔
اس ابتلاء اور مشقت کے درجات میں تفاوت در اصل خواہشات اور آرزووں کی شدت و ضعف یاکمی وزیادتی کا نتیجہ ہوتا ہے ۔ کیونکہ خواہشات جتنی زیادہ طاقتور ہونگی ان پر قابو پانے کیلئے انسان کو اتنی ہی مشقت اٹھا ناپڑے گی( ۱ ) اور عمل کو انجام دینے کیلئے خواہشات نفس کی جتنی زیادہ مخالفت درکارہوتی ہے وہ عمل قرب خداکیلئے اتنا ہی بیش قیمت ہوتاہے اور اسی کے مطابق خداوندعالم اسے جنت میں ثواب عنایت فرما تاہے ۔
____________________
(۱)خواہشات کے بارے میں اسلام کا نظریۂ اعتدال واضح ہے اوراسے تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔مختصر یہ کہ:
اسلام نہ تومکمل طورپر خواہشات کا گلا گھو ٹنے کی اجازت دیتاہے اور نہ وہ انھیں مطلق العنا ن چھوڑنے کاقائل ہے بلکہ اسلام کا ہر انسان سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو شرعی احکام کے دائر ہ میں پورا کرتا رہے ۔
اس وضاحت کے بعد بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کی جانب انسان کے ارتقائی سفر میں خواہشات کی کیا قدر وقیمت ہے کیونکہ قرب الٰہی کے ہر راہرو کو خواہشات اور آرزووںکے اس دلدل سے گذرناپڑے گاجسے خداوندعا لم نے ہر انسان کے وجود کا حصہ قرار دیا ہے ۔
اس وضاحت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتاہے کہ جسطرح خواہشات پستی اور ہلاکت کا باعث ہیںاسی طرح خداوندعالم تک پہونچنے کا زینہ بھی ہیں یہ نظریہ اسلامی فکر کی امتیازی جدت کا ایک نمونہ ہے ۔
جس کی طرف متعدد روایات میں اشارہ پایاجا تا ہے مگرہم اس مقام پر بطور نمونہ صرف دوروایات ذکر کر رہے ہیں :
۱۔(عن أبی البجیر،وکان من أصحاب النبی صلىاللهعليهوآلهوسلم قال:اصاب النبی صلىاللهعليهوآلهوسلم یومًاجوع شدید،فوضع حجراً علیٰ بطنه ثم قال:''ألارُبَّ طاعمة،ناعمة،فی الدنیاجائعة،عاریةیوم القیامة،ألارُبَّ مکرم لنفسه،وهولها مهین،ألاربّ مهین لنفسه،وهولها مکرم،ألا یارب متخوض،متنعم،فیما أفاء ﷲعلیٰ رسوله،ماله عندﷲ من خلاق،ألاون''عمل الجنة''حَزْنة بربوة، ألاون'' عملالنار''سهلة بشهوة،ألایارب شهوة ساعةٍأورثت حزناًطویلا )( ۱ )
''پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ایک صحابی ابی بجیر کا بیان ہے کہ ایک روز آ نحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کوبے حد بھوک لگی تھی تو آپ نے اپنے شکم مبارک پر پتھر رکھ لیا اور فرمایا :
نعمتوں کے خواہشمندکتنے ایسے افرادہیںجنہیں دنیا میں نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن وہ قیامت کے دن بھوکے اور برہنہ ہونگے یا د رکھو! بظاہراپنے نفس کی عزت کرنے والے نہ جانے کتنے لوگ خودنفس کی توہین کرتے ہیں ۔اور نفس کو رسوا کرنے والے کتنے افراد ہیں جو دراصل نفس کی عزت
____________________
(۱)ذم الہویٰ لا بن الجوزی ص۳۸۔
افزائی کرتے ہیں۔یاد رکھو! کتنے لوگ ان نعمتوں سے سرشار ہیںجو خداوندعالم نے اپنے رسول کو عنایت فرمائی ہیں مگر خدا کے نزدیک ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے یادرکھو !کہ جنت والا عمل ''حزنہ بربوة' ( نا ہموار پہا ڑی پر چڑھنے کے مثل )ہے اور جہنمی اعمال خواہشات کے عین مطابق او ر آسان ہیں یا د رکھو! بسا اوقات ایک ساعت کی شہوت ،طویل حزن و ملال کاسبب ہوتی ہے۔''
اس روایت میں متعدد قابل توجہ فکر انگیز نکات پائے جاتے ہیں جن سے بیحد مفید نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں جیسے کتنے نفس ایسے ہیں کہ جب انہیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو انہیں وہ نعمت مل جاتی ہے مگر وہ اپنی خواہشات کی بناء پر حرام وحلال کی کوئی فکر نہیں کرتے ۔۔۔ایسے لوگ روز قیامت بھوکے اوربرہنہ لائے جائیں گے۔
اور اسی طرح بعض اپنی خواہشات اور آرزووں کو پورا کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنے نفس کی عزت و احترام میں اضافہ کررہے ہیں جب کہ در حقیقت وہ نفس کی توہین کرکے اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔
کچھ لوگ اپنے نفس کے ساتھ شدت اور سختی سے پیش آتے ہیں اورجب وہ کسی شہوت اور خواہش کی طرف آگے بڑھناچاہتاہے تو صرف اسے روکتے ہی نہیں بلکہ اسکے ساتھ ساتھ اسکی توہین و تذلیل بھی کرتے ہیںیہ عمل در حقیقت اپنے نفس کی عزت افزائی اور احترام ہے۔
اور کچھ ایسے ہیں جو بالکل اندھا دھنداپنی خواہشات میں ڈوبے رہتے ہیں انھیںصرف دنیاوی لذت سے مطلب ہے ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ ہاتھ آنے والانہیں ہے۔یہ لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔
حدیث کے ان الفاظ پرمزید توجہ فرمائیں :
(ألا ون عمل الجنةحَزْنة بربوة )
''حزنة ربو ة'' والاعمل جنت میں لے جاتا ہے۔''
''حزنہ'' ناہموار پتھریلی زمین اور'' ربوة'' اس پر چلنے کو کہا جاتا ہے۔جو شخص ناہمواراور پتھریلی پہاڑیوں پر چڑھتا ہے اسکا سانس پھول جاتا ہے اور ہمت جواب دینے لگتی ہے اور آخری منزل تک پہنچنے تک اسکو بیحد مشقتوں کا سامنا کر نا پڑتاہے جیسے دریا کے بہائو کے خلاف تیرنے میں انسان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے لیکن ہموار راستہ پر چلنا یا دریا کے رخ کے مطابق تیرنا نہایت ہی آسان کام ہے یہی حال جنت اور جہنم کے اعمال یعنی اطاعت و معصیت کا بھی ہے کہ گناہ کرتے وقت تو انسان آسانی کے ساتھ خواہشات کے بہائو میں بہتا رہتا ہے لیکن اطاعت خدا کرتے وقت اسے اپنے نفس کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرناپڑتا ہے۔
۲۔ نہج البلاغہ میں منقول ہے کہ مولائے کائنات نے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کایہ قول نقل کیا ہے کہ رسول ﷲصلىاللهعليهوآلهوسلم برابر یہ فرمایا کرتے تھے:
(ن الجنةحفت بالمکاره،ون النارحفت بالشهوات،واعلموا:نه مامن طاعة ﷲ شیٔ لایأتی فی کره،وما من معصیة ﷲ شیٔ لایاتی فی شهوة،فرحم ﷲامرأً نزع نفسه عن شهوته،وقمع هویٰ نفسه،فن هذه النفس أبعد شی منزعا،ونها لاتزال تنزع لی معصیة فی هویٰ )( ۱ )
'' جنت کے چاروں طرف مشکلات اور زحمتوں کا حصار ہے اور جہنم کے چاروں طرف شہوتوں (خواہشات )کا گھرائو ہے اور یہ یاد رکھو کہ خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ زحمت اور ناگواری کا پہلو نہ ہو اور اسکی کوئی معصیت ایسی نہیں ہے جس میں شہوت اور ہوی ٰوہوس شامل نہ ہو۔ ﷲ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو اپنے نفس کو ہویٰ وہوس سے دور کرلے اور اپنی ہوس کو بالکل اکھاڑ پھینکے کہ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ لے جانے والا ہے اور ہمیشہ
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ۱۷۶
گناہوں کی خواہش کی طرف ہی کھنچتا رہتا ہے''
یہ حدیث ہمارے اس نتیجہ کی بہترین دلیل ہے جسے ہم نے روایات سے اخذ کرکے یہاںپیش کیا ہے کیونکہ جنت و جہنم ہی ہر انسان کی آخری منزل ہے جوانسان خداوند عالم کی طرف محوحرکت ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو اسکی نافرمانی کرے گا وہ انتہائی پستیوں میں پہنچ کر جہنم کا نوالہ بن جائے گا۔
جنت کے چاروں طرف مشکلات اور ناگوار یوں کے حصار کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہونچنے کے لئے انسان کو ہر طرح کی مشکلات سے گذر ناپڑتا ہے یعنی خواہشات اور ہوی وہوس پر قابو پانے ،تسلط حاصل کرنے اوراسے کچلنے کے لئے سخت زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جبکہ جہنم کے ہر طرف خواہشات اور ہوی ٰو ہوس کا بسیراہے انسان خواہشات اور ہوی وہوس کے درمیان پھسل کرہی تنزلی اور پستیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی اس حدیث کی روشنی میں امیر المومنین نے ایک عام اصول ہمارے حوالے کردیا ہے:
(مامن طاعة ﷲ شیء لایاتیفی کره ،ومامن معصیة ﷲ شیء لایاتی فی شهوة )
'' ہر اطاعت خدا کے وقت کچھ نہ کچھ ناگواری ضرور محسوس ہوتی ہے اور ہر گناہ میں ہوس کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پایا جاتا ہے ''
اطاعت الٰہی کرتے وقت نفس کو اسکی خواہشات و لذات اور ہویٰ و ہوس سے دور رکھنے کے لئے انسان کو ناگواری کا احساس ہوتاہے جبکہ وہ گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے کیونکہ اس سے نفس کی ہوس اور خواہشات پوری ہوتی ہیں اور اسے کسی قسم کے اندرونی ٹکرائو کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔
ان تمام تفصیلات کے بعد یہ حقیقت بآسانی قبول کی جاسکتی ہے کہ انسان کے لئے خداوندعالم تک پہونچنے کی راہیں خواہشات اور لذتوں کی دشوار گذاروادیوں سے ہوکر ہی گذرتی ہیں اورانسان خواہشات کے زینہ سے ہی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا خداوند عالم تک پہونچتا ہے۔ اگرانسانی وجود میں یہ خواہشات نہ ہوتیں تو انسان کے لئے اس منزل معراج وکمال تک پہونچنا ہرگز آسان نہ ہوتا جس کااسے اہل قرار دیاگیا ہے۔
عمل اور رد عمل کا سلسلہ
خداوند عالم نے انسانی وجود میں خواہشات کو ودیعت فرماکر اسکے لئے درحقیقت ایک ایساذخیرہ فراہم کردیا جس سے انسان اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتاہے ۔جیسے پروردگار نے انسان کے لئے زمین کے اندر کھانے پینے اور لباس کی جملہ ضروریات ،سمندروں میں پینے اور سینچائی کے لئے پانی فضا میں ہوا اور سانس کے لئے مختلف اقسام کے ذخائر فراہم کردئیے کہ انسان ان تینوں عناصر سے حسب ضرورت آب و غذایا دوسرے خام مواد حاصل کرتاہے۔اسی طرح خداوند عالم نے ان خواہشات کے ضمن میں نفس انسانی کے اندر علم ومعرفت ،یقین اور بندگی کے خزانے بھی ودیعت فرمائے ہیں۔
نفسانی خواہشات در حقیقت حیوانی وجود کا مقدمہ ہیں اوران خواہشات کا اکثر حصہ حیوانات کے اندر پایا جاتا ہے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسکو خداوند عالم نے ''ارادہ''کے ذریعہ ان خواہشات پرغلبہ حاصل کرنے ،انہیں روکنے یامحدود رکھنے کی صلاحیت بھی عنایت فرمائی ہے اوراسی ارادہ کے ماتحت ہوجانے کے بعد یہ اڑیل اور خود سر حیوانی خصلتیں بھی بہترین روحانی اور اخلاقی فضائل و اقدار ،بصیرت ویقین، عزم واستقلال اور تقوی وپرہیزگاری جیسی حسین شکل اختیار کر لیتی ہیں۔
وہ خواہشات جن سے انسان کے اندر حیوانی اور جسمانی پہلو کی تشکیل ہوتی ہے یہ جب کنٹرول اور قابو میں رکھنے والے اسباب کے ماتحت آتی ہیں تو اخلاقی اقدار میں تبدیل ہوجاتی ہیںاور وہی خواہشات اس کے ''انسانی''پہلو کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ یہ خود سرحیوانی خواہشات تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعہ کس طرح ان بلندوبالا انسانی اقدار میں تبدیل ہوتی ہیں اور تقوی و پرہیز گاری کی بنا پر نفس کے اندرکس قسم کے تغیرات اورتبدیلیاںرونماہوتے ہیں جو اس حیوانی خصلت کو علم ویقین اور صبر و بصیرت میں تبدیل کردیتے ہیں؟اسکا جواب ہمیں نہیں معلوم ہے۔
بلکہ نہایت افسوس کے ساتھ کہناپڑتاہے کہ ایک تویہ کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اور مزیدافسوس یہ کہ علم ومعرفت کا یہ وسیع باب انسان کیلئے آج تک نہ کھل سکا اور قدیم وجدیدماہرین نفسیات یہاں تک کہ اسلامیات کے ماہرین میں سے کوئی بھی آج تک اس گتھی کو سلجھا نے میں کامیاب نہیں ہوسکاہے۔
لیکن جب ہم خود اپنے نفس کے اوپر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اسکے اندربڑے پیمانہ پر رونما ہونے والے عمل اور رد عمل کے سلسلہ کا صاف اشارہ ملتاہے جیسے حیا ئ،جنسی خواہشات پر غلبہ حاصل کرنے کا ''ذریعہ''ہی نہیں ہے بلکہ حیاء ان خواہشات کو کچلنے کا ''نتیجہ''بھی ہے۔چنانچہ انسان ادب،فن اور ذوق کے غیر اخلاقی مواقع پر جس حد تک جنسی خواہشات کو کچلتارہتاہے اس کی حیامیں اتنا ہی اضافہ ہوتاجاتاہے ۔
ادب سے ہمار ی مراد ،ہرگز بدکاری نہیںہے البتہ وہ بلندپایہ ادب ،فن اور ذوق جس کی بناء انسان حیوانیت سے ممتاز ہوتاہے وہ اسی قوت برداشت اور تقوی کی بناء پر حاصل ہوتا ہے۔
اس سلسلہ میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اسکے اندر بھی ہمیں واضح طورپر اشارے ملتے ہیں جو ہمیںاپنے نفس کے بارے میں غور کرنے سے حاصل ہورہے تھے ۔
خداوند عالم کا ارشاد ہے:
( واتقواﷲ ویعلمکم ﷲ ) ( ۱ )
____________________
(۱)سورئہ بقرہ آیت ۲۸۲۔
''یعنی تم پر ہیزگار اور متقی بن جائواور خداوند عالم تم کو دولت علم عطا فرمائے گا''
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آیت کا دوسرا جملہ( ویعلمکم ﷲ ) پہلے جملہ پر بغیرکسی رابطہ کے عطف کیا گیاہے اوران دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے؟ یا ایسا نہیں ہے بلکہ علم و تقویٰ میں گہرا رابطہ ہے اور یہ دونوں جملے در حقیقت ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں ۔ اور ایک ترازو کے دوپلڑوںکی طرح ہیں؟
جو شخص بھی قرآن مجید کے اسلوب سے باخبر ہے وہ اسمیں کوئی شک وشبہ نہیں کرسکتا اوروہ یقینی طورپر جانتاہے کہ یہ دونوں جملے ایک ہی ترازو کے دوپلڑوںکی مانند ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے بندوںکے لئے یہاں جس علم کاتذکرہ فرمایا ہے وہ علم تقویٰ کا ہی نتیجہ اور اثر ہے اور یہ علم اس علم سے بالکل مختلف ہے جسے ہم تعلیم کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ علم، نور ہے جو خداوند عالم اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عطا فرمادیتا ہے۔
اس نور کی طرف سورئہ حدید کی یہ آیۂ کریمہ بھی اشارہ کر رہی ہے:
( یاأیهاالذین آمنواا تقواﷲ وآمنوابرسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراً تمشون به ) ( ۱ )
''ایمان والو ﷲ سے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آو تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے حصے عطا کردے اور تمہارے لئے ایسا نور قرار دیدے جسکی روشنی میں چل سکو''
اس نور سے مراد علم ہے لہٰذا سورئہ بقرہ اور سورئہ حدید دونوں مقامات پرعلم اور تقویٰ کے درمیان ایک جیسارابطہ پایا جاتا ہے۔
تقویٰ خواہشات کے طوفان کے سامنے بند باندھنے کا نام ہے اور خواہشات کے سامنے
____________________
(۱)سورئہ حدید آیت۲۸۔
لگائی جانے والی یہی بندش ایک دن نور علم و بصیرت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔
جناب یوسف کے واقعہ کے ذیل میں ارشاد الٰہی ہے :
( ولمابلغ أشده آتیناه حکماً وعلماً وکذٰلک نجزی المحسنین ) ( ۱ )
''اور جب یوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہونچے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کردیا کہ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں''
جناب موسیٰ کے قصہ میں بھی بعینہ یہی تذکرہ موجودہے :
( ولمابلغ أشده واستویٰ آتیناه حکماً وعلماً وکذٰلک نجزی المحسنین ) ( ۲ )
''اور جب موسی جوانی کی توانائیوں کو پہونچے اور تندرست ہوگئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کردی اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں''
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب موسی اور جناب یوسف کو اس خاص انعام سے کیوں نواز ا دوسرے لوگوں کو یہ نعمت کیوں نہیں ملی؟کیاخدا یوں ہی بلاسبب اپنے بعض بندوں کو ایسے اعزاز سے نوازدیتاہے اور دوسروں کو محروم رکھتاہے؟یا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سب تبدیلیاں ثابت واستوار الٰہی سنتوں کے تحت انجام پاتی ہیں۔
جو لوگ قرآنی لہجہ سے واقف ہیں انھیں اس بات میں ذرہ برابر بھی شک وشبہ نہیں ہوسکتا کہ ان دونوں آیتوں میں علم وحکمت کا تعلق ''احسان ''سے قراردیا گیا ہے۔ ''( وکذٰ لک نجزی المحسنین ) ''اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزادیاکرتے ہیں''تو جب وہ علم وحکمت جو جناب مو سی اور جناب یوسف کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے وہ سنت الٰہی کی بناء پر احسان سے
____________________
(۱)سورہ یوسف آیت ۲۲
(۲)سورہ قصص آیت ۱۴
مربوط ہے تو اسکے معنی یہ ہوئے کہ محسنین اپنے احسان اور حسن عمل کی وجہ سے ہی رحمت الٰہی کے مستحق ہوتے ہیںاور اسی بناء پر ان کو اسکی بارگاہ سے علم وحکمت کی دولت سے نوازا جاتا ہے۔لہٰذا اس استدلال کی درمیانی کڑیوں کو چھوڑتے ہوئے ہم مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ'' درحقیقت وہ احسان،علم وحکمت میں تبدیل ہوگیا ہے۔''
اور اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ تقوی اور خواہشات نفس کی مخالفت،احسان کا واضح ترین مصداق ہیں۔
فی الحال ہم اس موضوع کو مزید طول نہیں دے سکتے کیونکہ اس اہم موضوع کے لئے ہمارے پاس مناسب مقدار میں علمی مواد موجودنہیں ہے۔خدا وند عالم سے یہی دعا ہے کہ کوئی ایسا صاحب علم و کمال پیدا ہوجائے جو بہترین انداز سے اس مسئلہ کی گتھیاں سلجھا دے۔ کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نفس کے اندرعمل اور رد عمل کا سلسلہ بالکل اسی طرح رونما ہوتارہتاہے جس طرح فیزکس،کیمسٹری اور زولوجی وغیرہ کے میدانوں میں دکھائی دیتاہے مثلاًحرارت حرکت میں تبدیل ہوجاتی ہے اور حرکت حرارت میں بدل جاتی ہے یا بجلی کی طاقت حرکت پیدا کردیتی ہے اور اسی حرکت سے بجلی بنائی جاتی ہے بالکل اسی طرح نفس کے اندربھی عمل اور رد عمل کا سلسلہ پایا جاتاہے جسکی طرف قرآن مجید کی بعض آیتوں میں سرسری اشارہ موجود ہے ،لہٰذااسلام سے تعلق رکھنے والے علم النفس کے ماہرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نفس کے اسرار سے پردہ ہٹاکر ان کے اصول وقوانین کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔
خواہشات کا تخریبی کردار
خواہشات اور طاغوت
انسانی زند گی میںبربادی کاایک مرکز انسانی ہویٰ و ہوس اور خواہشات ہیں اور دوسرا مرکز طاغوت ہے انکے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ ہویٰ وہوس نفس کے اندر رہ کر تخریبی کا رروائی کرتی ہے اور طاغوت یہی کام نفس کے باہرسے انجام دیتا ہے اس طرح یہ دونوں انسان کو فتنہ وفسا داورتباہی کی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔بس ان کاانداز جداہوتاہے۔
شیطان ان خواہشات کے ذریعہ انسان کے اندرداخل ہوکر اس پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے جبکہ سماج یا معاشرہ اور قوموں کے اوپر طاغوت کے ذریعہ اپنی گرفت مضبوط رکھتا ہے۔
اسی لئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں نفس کی پیروی کرنے سے بار بار منع کیا ہے اور اسکی مخالفت کی تاکید فرمائی ہے ۔نمونہ کے طورپرمندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں:
( فلا تتبعوا الهویٰ ) ( ۱ )
''لہٰذا ہوی وہوس کی پیروی نہ کرنا''
( ولاتتبع الهویٰ فیضلّک عن سبیل ﷲ ) ( ۲ )
''اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کردیں''
( ولاتتبع اهوائهم عماجائک من الحق ) ( ۳ )
''اور جوکچھ حق تمہارے پاس آیا ہے اسکے مقابلہ میں ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو''
ہویٰ و ہوس کی پیروی سے بچنے کی مانند خداوند عالم نے ہمیں ''طاغوت ''کا انکار کرنے اور اس سے دور رہنے کا بھی حکم دیا ہے:
( یریدون ان یتحاکموا لی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به ) ( ۴ )
____________________
(۱)سورئہ نساء آیت ۱۳۵۔
(۲)سورئہ ص آیت ۲۶۔
(۳)سورئہ مائدہ آیت ۴۸۔
(۴)سورئہ نساء آیت ۶۰۔
''وہ یہ چاہتے ہیں کے سرکش لوگوں (طاغوت)کے پاس فیصلہ کرائیں جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں''
( والذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها وأنابوا الی ﷲ لهم البشریٰ ) ( ۱ )
''اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے علیٰحدگی اختیار کی اور خدا کی طرف متوجہ ہوگئے ان کے لئے ہماری طرف سے بشارت ہے''
( ولقدبعثنافی کل أمةرسولاأن اعبدواﷲواجتنبواالطاغوت ) ( ۲ )
''اور یقینا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ ﷲ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو''
عقل اور دین
ہویٰ وہوس اور طاغوت کے مقابلہ میں انسان کو راہ راست پر ثبات قدم عطا کرنے کیلئے خداوند عالم نے دوراستے کھول دئے ہیں ایک عقل اور دوسرے دین۔عقل انسان کے اندر رہ کر اسکی اصلاح کرتی ہے اور دین باہرسے اسکی ہدایت کا کام انجام دیتا ہے۔
اسی لئے حضرت امیر المومنین نے فرمایا ہے:
(العقل شرع من داخل،والشرع عقل من خارج )( ۳ )
''عقل اندرونی شریعت ہے اورشریعت بیرونی عقل کا نام ہے''
امام کاظم کا ارشاد ہے:
____________________
(۱)سورئہ زمر آیت ۱۷۔
(۲)سورئہ نحل آیت ۳۶۔
(۳)مجمع البحرین للطریحی مادہ عقل۔
(ان للّٰه علی الناس حجتین حجة ظاهرة وحجة باطنة فأماالحجة الظاهرة فالرسل والانبیاء والائمة وأماالباطنة فالعقول )( ۱ )
''لوگوں کے اوپرخداوند عالم کی دو حجتیں اور دلیلیں ہیں جن میں ایک ظاہری اور دوسری پوشیدہ اور باطنی حجت ہے۔ظاہری حجت انبیاء ،مرسلین اور ائمہ ہیں اور پوشیدہ اور باطنی حجت''عقل'' ہے ۔ ''
عقل اور دین کے سہارے انسان داخلی وخارجی سطح پر بخوبی ہویٰ و ہوس اور طاغوت کا مقابلہ کرسکتاہے۔جیسا کہ مولائے کائنات نے فرمایا ہے:
(قاتل هواک بعقلک )( ۲ )
''اپنی عقل کے ذریعہ اپنی خواہشات سے جنگ کرو''
خواہشات کی تباہ کاریاں
یہ بے لگام قوت جسکے مطالبات کی بھی کوئی حد نہیں ہے یہ انسان کے اندر تخریب کا ری اور فسادوانحراف کی اتنی زیاد ہ قوت و طاقت رکھتی ہے کہ اس کی طاقت کے برابرشیطان اور طاغوت جیسی طاقتوں کے اندربھی قوت وطاقت نہیں پائی جاتی ہے۔
اور سب سے زیادہ خطرناک بات تو یہ ہے کے انسان کو نیست ونابود کرنے والی یہ طاقت انسان کے وجود میں ہی سمائی ہوئی ہے اور انسان کے پاس اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جن دوچیزوں کا خوف لاحق تھاان میں سے ایک'' خواہشات نفس'' ہے جیسا کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ارشادگرامی ہے :
____________________
(۱)بحارج۱ص۱۳۷۔اصول کافی ج۱ص۱۶۔
(۲)نہج البلاغہحکمت۴۲۴
(ن أ خوف ماأخاف علیٰ اُمتّی:الهویٰ وطول الأمل،أماالهویٰ فاِنه یصد عن الحق،وأماطول الأمل فینسی الآخرة )( ۱ )
''مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا سب سے زیادہ خوف لاحق رہتا ہے ہویٰ وہوس، لمبی لمبی آرزوئیں،کیونکہ خواہشات ، حق تک پہنچنے کے راستے بند کردیتی ہیں اور لمبی لمبی آرزوئیں آخر ت کا خیال ذہن سے نکال دیتی ہیں''
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہوی وہوس انسان کے اندر رہ کر اسے گمراہ کرتی ہے اسی لئے مولائے کائنات نے فرمایا ہے:
(اللذات مفسدات )( ۲ )
''لذتیں تباہ کن ہیں''
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۰ص۸۸حدیث ۱۹ ج۷۰ص۷۵ حدیث ۳وح۷۰ص۷۷ح۹و۷۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۱۳۔
تباہ کا ری کے مراحل
حیات انسانی میں خواہشات کے منفی اور تخریبی کردارپر بھی ہمیں غور کر نا چاہئے کہ ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ انسانی وجود میںکچھ ایسے بنیادی محرکات پائے جاتے ہیں جن کی بناپر علم و معرفت پیدا ہوتی ہے اورانہیں کے ذریعہ انسان کی مادی اور معنوی زندگی پروان چڑھتی ہے اسی طرح اسکے انسانی اور حیوانی دونوں پہلووں کی انہیں محرکات کے ذریعہ تکمیل ہوتی ہے ۔
مگر ان تمام محرکات کے درمیان خواہشات اور ہویٰ وہوس ایسا محرک ہے کہ اگر خواہشات اپنی رو میں ہوں اوران میں طغیانی آجائے تو پھریہ انسان کے اندر موجود دوسرے محرکات کو بالکل معطل اور ناکارہ بنا دیتے ہیں اور عقل،دل،ضمیر،فطرت اورارادہ کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔وسیع پیمانہ پر ۔۔۔ ان محرکات کی معطّلی کے بعد انسانی پہلو بالکل نیست و نابود ہوجاتاہے اور انسانی نفس میں محرک کی حیثیت سے خواہشات کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں رہتاہے جبکہ تمام حیوانی پہلووں کی تشکیل انہیں خواہشات سے ہوتی ہے۔
اس طرح انسانی زندگی کے اندر یہ مفیداور کارآمد عنصرہلاکت اور بربادی کا موجب ہوجاتا ہے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے :
(ولاتطع من أغفلناقلبه عن ذکرناواتبع هواه وکان أمره فرطا )( ۱ )
''اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کر نا جسکے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کردیا ہے اور وہ اپنے خواہشات کا پیرو کار ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے ''
فرط تفریط سے بنا ہے جسکے معنی ضائع و برباد کرنا ہیں۔
انسانی زندگی میںہو یٰ و ہوس کے تخریبی کردار کی طرف قرآن وحدیث میں خصوصی توجہ دلائی گئی ہے تا کہ لوگ خواہشات کے خطرات سے بخوبی آگاہ رہیں اور اسکی تباہ کا ریو ںکاشکار نہ ہو نے پائیں ۔
ذیل میںہم اسلامی نکتہ نظر سے خواہشات اورہویٰ و ہوس کی تباہیوں اور بربادیوں کا جائزہ پیش کررہے ہیں ۔
ہمیں آیات اورروا یا ت کے مطابق خواہشات کی تخریبی کار روائی کے دو مرحلے دکھائی دیتے ہیں پہلے مرحلہ میں توخواہشات ،انسان کے اندر علم ومعرفت اور خداوندعالم کی طرف لے جانے والے تمام ذرائع کو معطل اور نیست ونابود کرکے رکھ دیتی ہیں۔
دوسرے مرحلہ میں ان تمام ذرائع کومعطل کرنے کے بعدخواہشات انسان کو مکمل طورپر
____________________
(۱)سورئہ کہف آیت۲۸۔
اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور اس پر خواہشات کی حکمرانی ہوتی ہے انسان ہر اعتبار سے ان کی حکومت کے سا منے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اورخواہشات کا ا سیربن کررہ جاتاہے جسکے نتیجہ میں خداوندعالم نے انسان کو جو کچھ طاقتیں، صلاحیتیں اور فہم و فراست عطا فرمائی تھی وہ سب ہویٰ و ہوس کا آلۂ کار بن جاتی ہیں۔
اب آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں خواہشات کے ان دونوںمرحلوں کی تفصیل ملاحظہ فر ما ئیں۔
خواہشات کی تخریبی کارروائیوں کا پہلا مرحلہ
ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ پہلے مرحلہ میں ہویٰ و ہوس علم و عمل کی تمام خدا داد صلاحیتوں کو معطل کردیتی ہے۔اسکے علاوہ بھی یہ انسان کے اندربہت خرابیاں پیدا کرتی ہے آیات و روایات میں مختلف عناوین کے تحت ان خرابیوں کا تذکرہ موجودہے ہم موضوع کی مناسبت سے صرف چند نمونے پیش کررہے ہیں ۔
۱۔خواہشا ت ،قلب پر ہدایت کے در وازے بند کر دیتے ہیں۔
ﷲتعالیٰ کا ارشاد ہے :
(أفرأیت من اتخذ لٰهه هواه وأضله ﷲعلیٰ علم وختم علیٰ سمعه وقلبه وجعل علیٰ بصره غشاوةً فمن یهدیه من بعد ﷲ أفلا تذکّرون )( ۱ )
''کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑدیا ہے اور اسکے کا ن اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اسکی آنکھ پر پردے پڑے ہو ئے ہیں اور خدا کے بعد کو ن ہدایت کر سکتا ہے کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو''
دوسرے مقام پر خداوندعالم کا ارشاد ہے:
____________________
(۱)سورئہ جاثیہ آیت۲۳۔
( فن لم یستجیبوالک فاعلم أنمایتبعون أهوائهم ومن أضل ممن تبع هواه ) ( ۱ )
''پھر اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کرے ''
ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواہشات انسان کے دل کے اوپر خدا،رسول،خدائی آیات ودلائل اور ہدایت کے تمام راستے مکمل طورپر بندکر دیتے ہیں اورقلب سے خدا ورسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی صلاحیت کوسلب کر لیتے ہیں ۔
مزید تائید کے لئے مو لا ئے کا ئنات کے یہ ارشادات ملا حظہ فرما ئیے :
(من اتبع هواه أعماه،وأصمّه،وأذلّه )( ۲ )
''جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے گاخواہشات اس کو اندھا بہرابنادیں گی اوراس کوذلیل ورسواکردیں گی ۔''
٭(الهوی شریک العمی )( ۳ )
''خواہشیں نابینائی کے شریک کار ہوتی ہیں ۔''
٭(نک نْ أطعت هواک أصمّک وأعماک )( ۴ )
''اگرتم اپنے خواہشات کی پیروی کروگے تو وہ تم کو بہرا اور اندھا بنا دینگے ''
____________________
(۱)سورئہ قصص آیت۵۰۔
(۲)غررالحکم ج۲ص۲۴۲۔
(۳)نہج البلاغہ مکتوب ۳۱۔
(۴)غررالحکم ج ۱ص۲۶۰ ۔
(اوصیکم بمجا نبة الهویٰ،فن الهویٰ یدعولی العمی وهوالضلال فی الآخرةوالدنیا )( ۱ )
میں تم کوخواہشات سے دور رہنے کی وصیت کرتاہوں کیونکہ خواہشات اند ھے پن کی طرف لیجاتی ہیں اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی گمراہی ہے ۔''
۲۔خواہشات گمراہی کا ذریعہ
خدا وند عالم کا ارشادہے :
( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیّا ) ( ۲ )
''پھر ان کے بعد ان کی جگہ پر وہ لوگ آگئے جنھوںنے نماز کو برباد کردیا اور خواہشات کا اتباع کرلیا پس عنقریب یہ اپنی گمراہی سے جا ملیں گے''
اور ﷲتعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے :
( ولا تتبع الهویٰ فیضلک عن سبیل ﷲان الذ ین یضلون عن سبیل ﷲ لهم عذاب شدید ) ( ۳ )
''اور(اے دائود)! خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منصرف کردیں بیشک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کیلئے شدید عذاب ہے''
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ارشاد ہے :
(نّ أخوف ماأخاف علیٰ اُمتی،الهویٰ،وطول الأ مل،أماالهویٰ فنّه
____________________
(۱)مستدرک ومسائل الشیعہ ۳۴۵۲طبع قدیم ۔
(۲)سورئہ مریم آیت۵۹۔
(۳)سورئہ ص آیت ۲۶۔
یصد ُّعن الحق،وأماطول الأمل فینسی الآخرة )( ۱ )
''مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کا خوف ہے ۔خواہشات نفس اور لمبی لمبی آرزوئیں کیونکہ خواہشات اور ہویٰ و ہوس حق تک پہو نچنے کے راستے بند کردیتی ہیں اور لمبی لمبی آرزو ئیں آخرت کا خیا ل ذہن سے نکال دیتی ہیں ''
۳۔خواہشات ایک مہلک زہر
امیر المو منین حضرت علی کا ارشاد ہے:
(الشهوات سمومات قاتلات )( ۲ )
'' خواہشات مہلک زہر ہیں ''
۴۔خواہشات آفت اور بیماری
اس سلسلہ میں حضرت علی کے یہ اقوال ملا حظہ فرما ئیں :
(من تسرّع الیٰ الشهوات تسرّعت الیه الآفات )( ۳ )
''جو خواہشات کی طرف جتنی تیزی سے بڑھے گا اسکے اوپر اتنی ہی تیزی سے آفتیںآن پڑیں گی''
(احفظ نفسک من الشهوات،تسلم من الآفات )( ۴ )
''اپنے نفس کو خواہشات سے بچاکر رکھو تو آفتوں سے محفوظ رہوگے ''
____________________
(۱)خصال صدوق جلد ۱صفحہ ۲۷ ،بحارالانوارج۷۰ص۷۵حدیث۳وج۷۰ص۷۷حدیث۷وج۷۰ ص ۸۸ حدیث۱۹۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۴۴ ۔
(۳)غررالحکم ج۲ص۲۰۱۔
(۴)گذشتہ حوالہ۔
(رأس الآفات الوله باللذ ات )( ۱ )
''آفتوں کی اصل وجہ لذات و خواہشات کا دلدادہ ہوناہے۔''
(قرین الشهوة مریض النفس معلول العقل )( ۲ )
''شہوتوں اور خواہشوں کے دلد اد ہ کا نفس مریض اور عقل بیمار ہو تی ہے ''
(الشهوات أعلال قاتلات،وأفضل دوائهااقتناء الصبرعنها )( ۳ )
''خواہشات مہلک بیماریاں ہیں اور ان سے پرہیز کر نا ہی ان کی بہترین دوا ہے''
(أول الشهوةطرب وآخرهاعطب )( ۴ )
''خواہشات کاآغاز لطف انگیز اور انجام زحمت خیز ہوتاہے۔''
۵۔خواہشات آزمائشوں کی بنیاد
حضرت علی کا ارشاد ہے:
(الهویٰ اُسّ المحن )( ۵ )
''ہوس آزمائشوں کی بنیاد ہے ''
۶۔خواہشات فتنوں کی چر اگاہ
حضرت علی کا ارشادہے:(الهویٰ مطیّةالفتن )( ۶ )
____________________
(۱)غررالحکم ج۱ص۳۷۲۔
(۲)غررالحکم ج۲ص۷۷و۷۸۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۹۰۔
(۴)غررالحکم ج۱ص۱۹۵۔
(۵)غررالحکم ج۱ص۵۰ ۔
(۶)غررالحکم ج۱ص۵۱۔
''خواہشات فتنوں کی چر اگاہ ہیں ۔''
آپ ہی کا ارشاد ہے:
(انّمابدء وقوع الفتن أهواء تُتّبع )( ۱ )
''فتنوں کے واقع ہو نے کی ابتدا ان خواہشات سے ہوتی ہے جنکی پیروی کی جائے ۔ ''
(ایاکم وتمکّن الهویٰ منکم،فان أوّله فتنة،وآخره محنة )
''ذرا سنبھل کر ،کہیں تمہار ی خواہشات تم پر حاوی نہ ہو جائیں کیونکہ انکی ابتداء فتنہ اور انتہا آزمائش طلب ہوتی ہے ۔''
۷۔خواہشات ایک پستی
حضرت علی :
(الهویٰ یُردی )( ۲ )
''ہویٰ و ہوس پستی میں گرادیتی ہے ۔''
آپ ہی کا یہ ارشاد بھی ہے :
(الهویٰ هوّی الیٰ اسفل السافلین )( ۳ )
''انسانی ہوس ،پستیوں کی آخری تہوں میں گرا دیتی ہے ''
امام جعفر صادق کا قول ہے :
(لاتدع النفس وهواها،فان هواها رداها )( ۴ )
____________________
(۱)نہج البلا غہ خطبہ ۵۰ ۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۱۲۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۶۵۔
(۴)بحارالانوار ج۷۰ص۸۹حدیث۲۰۔
''نفس کو اس کی خو اہشات کے اوپر نہ چھوڑ دو کیونکہ اس کی خو اہشات ہی اس کی پستی ہیں ''
۸۔خو اہشات موجب ہلا کت
حضرت علی کا ارشادہے:
(أهلک شیٔ الهویٰ) ( ۱ )
''سب سے زیادہ مہلک چیز خو ا ہشات ہیں''
(الهویٰ قرین مهلک )( ۲ )
''خو اہشات مہلک سا تھی ہیں ''
۹۔خو اہشات انسان کی دشمن
حضرت امام جعفر صادق کا ارشادہے:
(أحذروا اهوائکم کماتحذرون أعدائکم،فلیس شی ء أعدیٰ للرجال من اتّباع أهوائهم )( ۳ )
''اپنی خو اہشات سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو کیونکہ لو گوں کے لئے ان کی خو ا ہشات سے بڑا کو ئی دشمن نہیں ہے''
۱۰۔عقل کی بربادی
حضرت علی کا ارشادہے:(آفة العقل الهویٰ )( ۴ )
____________________
(۱)غرر الحکم ج ۱ ص ۱۸۰۔
(۲)غرر الحکم ج ۱ ص۴۷۔
(۳)بحا رالانوار ج ۷۰ ص ۸۲ حدیث ۱۲۔
(۴)غرر الحکم ج ۱ ص۲ ۲۷۔
''خواہشات عقل کو برباد کرنے والی آفت ہیں۔''
(من لمیملک شهوته لم یملک عقله )( ۱ )
''جس کا اپنی خواہشوں کے او پر اختیار نہیں رہتا وہ اپنی عقل کا اختیار بھی کھو بیٹھتا ہے ''
(زوال العقل بین دواعی الشهوةوالغضب )
'' عقل دو چیزوں میں زائل ہو تی ہے :شہوت اور غضب''
ہویٰ و ہوس اور خواہشات کا عالم یہ ہے کہ جب ان میں طغیانی پیداہوتی ہے تو یہ مفید اورکار آمد عنصر،تعمیر کے بجائے تخریب اور دوسرے اہم بنیادی منابع و محرکات کی بربادی کا سبب بن جاتاہے
یہ تھا خواہشات کی کارروائی کا پہلا مرحلہ ،جس میں انسانی زندگی پر خواہشات کا منفی اور تخریبی کردار بخوبی واضح ہوگیا۔
خو ا ہشات کی تباہ کاری کا دو سرا مر حلہ
خو اہشات کی جن تباہ کا ریوں کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے بات اسی مرحلہ پر تمام نہیں ہوتی بلکہ خواہشات فتنہ و فساد بر پا کر نے میں دو چار قدم اور آگے نظر آتے ہیں چنا نچہ پہلے مر حلہ میں یہ خواہشات انسان کے ارا دہ ،عقل ،ضمیر ،دل اور فطرت کونا کارہ اور معطل کر دیتی ہیں اس مرحلہ کو قرآن مجید نے'اغفال قلب '(دل کو غافل بنا دینے )کا نام دیا ہے ۔
لیکن جب خواہشات ان تمام اہم محرکات کو نیست و نا بود کر دیتے ہیں اور انسان کو ہر لحاظ سے اپنی گرفت میں لے کر اس پر غلبہ اور تسلط حاصل کر لیتے ہیں تو پھر انسان خواہشات کا تا بع اور فرماں بردار ہو کر رہ جاتا ہے اس مرحلہ کو قرآن مجید نے''اتباع ہویٰ'' کا نا م دیا ہے ۔مندرجہ ذیل آیۂ کریمہ میں آپ دونوں مراحل بخوبی ملاحظہ کرسکتے ہیں :
____________________
(۱)مستد رک و سائل الشیعہ ج ۲ ص ۲۸۷ طبع قدیم ۔
(ولاتطع من أغفلناقلبه عن ذکرنا واتّبع هواه وکان أمره فُرطا )( ۱ )
''اور ہر گز اسکی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے۔ وہ اپنے خواہشات کا پیر و کا ر ہے ۔اور اسکا کام سراسر زیادتی کر نا ہے ''
پہلے مر حلہ میں خواہشات نے انسانوں کے دل کو بالکل غافل بنادیااور اسمیں علم ومعرفت اور ہدایت وبصیرت کا کو ئی امکان باقی نہیں رہ گیااور دوسرے مرحلہ میں ہویٰ و ہوس نے اسے مکمل طورپراپنی گرفت میں لے لیا نتیجتاًانسان خواہشات کا تابع محض بن کر رہ گیا اور جب یہ سب کچھ ہوجائے کہ ایک طرف اسکا دل غافل رہے اور دو سری جانب وہ ہوس کاغلام بن جائے تو اسکا آخر ی انجام واقعاً وہی تلخ حقیقت ہے جسکی طرف قرآن مجیدنے اشارہ کیاہے۔( ''وکان أمره فرطا'' )
خواہشات کا قیدی
دوسرے مرحلہ میں انسان ہر اعتبار سے خواہشات کے قبضہ میں چلا جاتا ہے اورواقعاً ''خواہشات'' کااسیر بن کر رہ جاتاہے بلکہ اپنے اسیر پر خواہشات کا اختیارو تسلط جنگی قیدی کے بالمقابل کہیں زیادہ ہوتاہے کیونکہ قیدی پر فاتح کااختیار و تسلط محدودحد تک ہوتاہے ۔مثلاًوہ اسے فرارنہیں ہونے دیتایا مقابلہ سے معذور کردیتاہے ،اسے کسی خاص راہ و روش کا پابند بنادیاجاتاہے ، اوراسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑدیا جاتاہے اسے اپنی مرضی کے مطابق بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی مگر ان تمام باتوں کے باوجود یہ قیدی تین اعتبار سے بالکل آزاد رہتاہے۔
۱۔اپنے احساسات اورسماعت و بصارت میں آزاد ہوتاہے اور دوسروں کے احساسات سے قطع نظر وہ اپنے طورپر مسقتل سنتاہے دیکھتا ہے اور کسی بھی چیز کا احساس کر سکتا ہے اور قید کرنے والا چاہے جتنی بڑی حکومت اور اقتدار کا مالک ہو پھر بھی وہ اسکے احساسات پر پابند ی نہیں لگاسکتا جیسے
____________________
(۱)سورئہ کہف آیت۲۸۔
اسکے اوپر یہ پابندی نہیں لگا سکتا کہ وہ اچھی چیز کو برا دیکھنے لگے ۔یا بری چیز کو اچھا محسوس کرے۔
۲۔اسکی عقل بھی بالکل آزاد رہتی ہے اوروہ جس طرح چا ہے سوچ سکتا ہے اور اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے نہ کہ قید کرنے والوں کی عقل کے مطابق اسے اسیرکر نے والے اسکی عقل کو قیدی بنا کر اپنی مرضی کے مطابق اسکے لئے کوئی خاص طرز تفکر معین نہیں کر سکتے ہیں ۔
۳۔اسی طرح اسکا دل بھی بالکل آزادہو تا ہے یعنی اس کا دل جس سے چاہے محبت یا نفرت کر سکتا ہے یہ اسے اختیار ہے اور اسے قیدی بنا نے والے اسمیں کو ئی مد اخلت نہیں کرسکتے بلکہ وہ جن کی قید میں ہوتا ہے انھیں سے نفرت کرتا ہے اور انکے دشمنوں سے محبت کر تا ہے کیونکہ اسکے دل پران کا کوئی اختیار نہیں ہوتاہے۔
بقول شاعر
''مجھے اسیر کرو یا مری زباں کاٹو
مرے خیال کو بیڑی پنہا نہیں سکتے ''
لیکن خو اہشات کے قیدیوں میں معا ملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کیونکہ خواہشات اپنے اسیر کے احساسات اسکی عقل اور دل سب کومکمل طورپر اپنے قابومیں کرلیتی ہیں اوران کے اندر اپنے مطابق مداخلت کرتی ہیں اور اسیر پر ان کی مکمل حکمرانی ہوتی ہے۔
اب وہ خواہشات ہی کے مطابق فیصلہ کرتاہے برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی، نیک و طیب کو خبیث اور خبیث کوطیب سمجھتا ہے۔
اور ہر چیز کے بارے میں اسکا انداز فکر وہی ہوجاتا ہے جواس کے خواہشات چاہتے ہیں گویا اسکی عقل و منطق اور فہم و ادراک سب تبدیل ہوجاتے ہیں۔
پھریہ خواہشات انسان کے قلب پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے بھی اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور پھر اسکا انداز محبت ونفرت خواہشات کے اشاروں پر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔چنانچہ خداوند عالم کے جن دشمنوں سے نفرت ضروری ہے وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے اور خدا کے جن محبوب بندوں سے محبت ضروری ہے ان سے اسے نفرت ہوجاتی ہے۔
ان خواہشات کا آخری حملہ انسان کے ضمیرکے او پرہوتا ہے کیونکہ انسانی وجودمیںضمیر ہی ان کے مقابلہ میں سب سے زیادہ ثبات قدم کا مظاہر ہ کرتا ہے اور آخرکار اس جنگ میں انسان کا ضمیر بھی پیچھے ہٹنے لگتاہے اور جب یہ خواہشات انسان سے اسکا ضمیر بھی چھین لیتے ہیں تو پھر انسان اپنی خواہشات، شیاطین اورطاغوت کے مقابلہ میں بالکل بے یارومددگارہوکرہتھیار ڈال دیتا ہے۔
اس سے بخوبی اندازہ ہوجاتا ہے کہ خواہشات کی زنجیریںبدن کوقیدکرنے والی زنجیروں اور سلاخوں سے کتنی زیادہ مؤثر اور کاری ہوتی ہیں ،ایک انسان کی قید اور خواہشات کی اسیری کے اس فرق کی جانب مولائے کائنات کی اس حدیث میں بھی اشارہ موجود ہے :
(عبدالشهوة أذل من عبدالرق )( ۱ )
'' خواہشات کا اسیر ہونا کسی انسان کے ہاتھوں اسیر ہونے سے کہیںزیادہ ذلت و رسوائی کا باعث ہے''
اگر چہ بظاہر ان دونوں کو ہی اسیری کہا جاتا ہے اور دونوںطرح کی اسیری میں انسان ذلیل ہوتا ہے اوردونوں صورتوں میںقیدی دوسرے کا محکوم ہوتاہے لیکن پھر بھی کسی انسان کی قید میں رہنا اتنا دشوارنہیں ہے جتنی دشوار اور باعث ذلت خواہشات کی اسیری ہوتی ہے۔
خواہشات کی قیدقرآن و حدیث کی روشنی میں
مندرجہ ذیل آیۂ کریمہ کے بارے میں غوروفکر کرنے کے بعد انسانی وجودپر قابض اس اسیری کی گہرائیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔خداوند عالم کا ارشاد ہے:
(أفرأیت من اتخذالٰهه هواه وأضله ﷲ علیٰ علم وختم علیٰ سمعه وقلبه
____________________
(۱) غرر الحکم ج۲ص۴۰۔
وجعل علیٰ بصره غشا وةفمن یهدیه من بعد ﷲ أفلا تذکّرون )( ۱ )
''کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنالیا ہے اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑدیا ہے اور اسکے کان اوردل پر مہر لگادی ہے اور اسکی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے بعد کون ہدایت کرسکتا ہے کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو؟''
اس طرح خداوند عالم ایسے انسان سے سماعت ،بصارت اور دل سب کچھ چھین لیتاہے اور وہ دوسروں کے اشاروں پر اس طرح حرکت کرتاہے کہ اس کو اپنے اوپر ذرہ برابر اختیار نہیں رہ جاتااور وہ ہر معاملہ میں خواہشات کا ہی تابع رہتا ہے یہاں تک کہ اسکے خواہشات ہی اسکا خدا بن جاتے ہیں جو کہ خواہشات کی غلامی کی آخری منزل ہے ۔
مزید وضاحت کے لئے مولائے کائنات کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیے:
(مَن ملک نفسه علا امره،ومن ملکته نفسه ذل قدره )( ۲ )
''جو اپنے نفس کا مالک ومختار ہووہ باوقار اور بلند مرتبہ ہے اور جس کا مالک ومختار اسکا نفس ہے وہ ذلیل اورر سوا ہوتاہے''
(أزری بنفسه من ملکته الشهوة واستعبدته المطامع )( ۳ )
''اس نے اپنے نفس کو معیوب بنا لیاجو شہوت کا محکوم ہوگیااورلالچوں نے اسے غلام بنا لیا''
(عبدالشهوةأسیرلا ینفک أسره )( ۴ )
''خواہشات کا غلام ایک ایسا قیدی ہے جو کبھی آزاد نہیں ہوسکتا ہے''
____________________
(۱)سورئہ جاثیہ آیت۲۳۔
(۲)مستدرک الو سائل ج۲ص۲۸۲۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۱۹۵۔
(۴)غررالحکم ج۲ص۴۰۔
(کم من عقل أسیرتحت هویٰ أمیر )( ۱ )
''کتنی عقلیں ،خواہشات کی فرما نروائی میں اسیر ہیں''
(الشهوات تسترق الجهول )( ۲ )
''خواہشات جاہلوں کو غلام بناکر رکھتی ہیں''
یہ بہترین تعبیر ہے کہ جاہل جب خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اسے نفس کے اختیار سے نکال کر اپنی سلطنت کے ماتحت لے لیتی ہیں اور انسان اپنی عقل ،ارادہ اورضمیر کے دائرئہ اختیار سے باہر نکل کر خواہشات کی حکومت اور اختیار میں چلا جاتا ہے جس طرح چورتاریکی میںبڑی خاموشی کے ساتھ گھر کے سامان کا صفایاکردیتا ہے اسی طرح جہالت کی تاریکی میں خاموشی سے انسان پر اسکے خواہشات کی حکمرانی ہوجاتی ہے اوراسے خبر بھی نہیں ہوپاتی ہے۔
انسان اور خواہشات کی غلامی
جب اس حد تک انسان کے اوپر خواہشات کی حکمرانی ہوجاتی ہے توانسان خواہشات کا غلام بن جاتاہے کیونکہ خواہشات کاایسا غلبہ ایک قسم کی بندگی ہے۔
قرآن مجیدکی یہ دونوںآیتیںہمیں بیحد غوروفکر کی دعوت دیتی ہیں :
( أفرأیت من اتخذالٰهه هواه وأضله ﷲعلیٰ علم وختم علیٰ سمعه وقلبه وجعل علیٰ بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد ﷲ أفلا تذکّرون ) ( ۳ )
''کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑدیاہے اور اسکے کان اوردل پر مہر لگادی ہے اور اسکی آنکھ پر
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت ۲۱۱۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۴۵۔
(۳)سورئہ جاثیہ آیت۲۳۔
پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے بعد کون ہدایت کرسکتا ہے کیا تم اتنا بھی غور نہیںکرتے ہو ''
( أرأیت من اتخذلٰهه هواه أفأنت تکون علیه وکیلا ) ( ۱ )
''کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے کیا آپ اسکی بھی ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہیں''
بات اگر چہ بہت عجیب وغریب محسوس ہوتی ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب انسان پر وردگار عالم کو چھو ڑکر اپنی خواہشات کو خدا بنالیتا ہے اور انھیں کی عبادت کرتا ہے۔' '
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے منقول ہے :
(ماتحت ظل السماء من الٰه یعبد من دون ﷲأعظم عندﷲ من هویً متّبع )( ۲ )
''اس آسمان کے نیچے خداوندعالم کے بعد سب سے زیادہ جس معبود کی عبادت کی گئی ہے وہ خواہشات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے''۔
حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے:
(الجاهل عبد شهوته )( ۳ )
''جاہل اپنی خواہش کا غلام ہوتاہے''
اللہ نے بھی اسے نظر انداز کردیا
جب انسان خداوندعالم کی بندگی اور عبودیت سے نکل کر خواہشات نفس سے رشتہ جوڑدیتا ہے اور اطاعت الٰہی کے بجائے اپنے نفس کا تابع ہو جاتاہے تو پھر وہ عملی اعتبار سے اس حدتک پستی
____________________
(۱)سورئہ فرقان آیت ۴۳۔
(۲)درمنثور ج۵ص۷۲۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۲۸۔
میں چلا جاتا ہے کہ رب العالمین کی اطاعت وبندگی چھوڑکر اپنے خواہشات نفس کی پرستش شروع کردیتا ہے ۔
لہٰذاایسے افراد کے بارے میں یہ کہنا بالکل بجا ہے( نسواﷲ فنسیهم ) کہ
'' انھوں نے خداوندعالم کو بھلا دیا تو اس نے انھیں فرامو ش کردیا ۔''اسکی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کیونکہ جب وہ خود خدا کی عبودیت وبندگی اوراسکی اطاعت کے حدود سے باہر نکل گئے اور انھوں نے خدا سے اپنا رابطہ توڑکر اسے بھلا دیا تو پروردگار عالم نے بھی ان کو بھلادیا ۔۔۔ان کے بھلادینے کا جواب انہیں بھلاکردیااور انہیں ان کے حوالہ کردیا اورجس لمحہ بھی خداوند عالم کسی بندے سے اپنی نظر کرم موڑکر اسے اسکے نفس کے حوالہ کر دیتا ہے اسی لمحہ وہ شیطان کا شکار بن جاتاہے ۔
خواہشات کی تباہیاں قرآن مجید کی روشنی میں
بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم ''بلعم بن باعورا'']۱[کا قصہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :
( واتل علیهم نبأالذی آتیناه آیاتنافانسلخ منهافأتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولوشئنالرفعناه بها ولکنه أخلد لیٰ الارض واتّبع هواه فمثله کمثل الکلب ن تحمل علیه یلهث أوتترکْه یلهث ذلک مثل القوم الذین )
____________________
(۱)مشہورروایات کی بنیادپر ان آیات میں بلعم باعورا کی ہی مذمت کی گئی ہے۔اگر چہ دیگر اقوال بھی موجود ہیں جن کے مطابق وہ شخص صیفی راہب تھا جس نے پیغمبر اکرم کو فاسق کہا تھا ۔بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد امیہ بن ا بی الصلت ہے وغیرہ وغیرہ ۔
( کذّبوا بآیاتنافاقصص القصص لعلهم یتفکّرون ) ( ۱ )
''اور انھیں اس شخص کی خبرسنا ئیے جسکو ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں پھر وہ ان سے بالکل الگ ہوگیا اور شیطان نے اسکا پیچھاپکڑلیا تو وہ گمراہوں میں ہو گیااور ہم چاہتے تو اسے انھیں آیتوں کے سبب بلند کردیتے لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی تو اب اسکی مثال اس کتّے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑدو تو بھی زبان نکالے رہے یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی،تواب آپ ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور وفکر کر نے لگیں ''
ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ '' بلعم بن باعور ا'' بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی بڑا اور مشہور عالم تھا اسکو خداوندعالم نے اپنی روشن آیات نیز علم ومعرفت سے اس حد تک نوازاتھا کہ اسے مستجاب الدعوات قرار دے دیا تھا اور جناب موسیٰ بعض معاملات میں اس سے مدد لیتے تھے۔۔۔مگر وہ اپنی ہویٰ وہوس کا اسیر ہو گیا۔
چنا نچہ ایسے افراد جب اپنی خواہشات کا شکار ہو تے ہیں تو عام طور سے اسکے دوہی اسباب ہو تے ہیں یا تو وہ اپنے علم کو ذاتی فا ئدہ کیلئے استعمال کر نے لگتے ہیں مثلاً علم کے ذریعہ شہرت وعزت یا عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیںاور لوگوںکے درمیان علم کے ذریعہ اپنی شخصیت کا اظہار کرتے ہیں یا یہ کہ دولت کی لا لچ میں اپنے علم سے اہل حکومت اورطاغوت کی خدمت شروع کردیتے ہیں اور علم کے بدلہ مال دنیا کماتے ہیںاس طرح دونوں صورتوں کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ علم ہویٰ وہوس اور خواہشات کا شکا ر ہو جا تا ہے ۔
کیونکہ کسی بھی عالم کی اہمیت کا معیار در اصل اسکے علم کی کثرت نہیں ہے ،جیسے اکثر کتب
____________________
(۱)سورئہ اعراف آیت۱۷۵۔۱۷۶۔
خانوں میں اتنی زیادہ کتابیں ہوتی ہیں کہ علماء کی ایک کثیر تعداد مل کربھی انہیں نہ اٹھا سکے مگر اسکی کوئی اہمیت نہیں ہے ۔ علم کی قدروقیمت در اصل صاحب علم اور اس علم کے مصرف اور محل استعمال کو دیکھ کر لگا ئی جا تی ہے ۔ اگر عالم انبیاء کے دین اوراخلاق سے مزین ہو اور اس کاعلم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی نیز انکی خدمت میں کام آئے تو یہ اس عالم کی قدروقیمت کاسبب ہے اور اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھراس عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے ۔
مو لا ئے کا ئنات نے خطبہ شقشقیہ میں عالم کی منزلت اور اسکی ذمہ دار یاں ان الفاظ میں بیان فرمائی ہیں:
(وما أخذ ﷲعلی العلماء أن لایقارّوا علی کظة ظالم ولاسغب مظلوم )
'' ﷲکا اہل علم سے یہ عہدہے کہ خبردار ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گر سنگی پر چین سے نہ بیٹھنا۔۔۔''
لہٰذااگرعالم خدا سے کئے ہوئے عہد کو پوار کر نے کیلئے اٹھ کھڑا ہو تو اسکی قدر ومنزلت اور مقام ومرتبہ میںاضافہ ہوتاہے ۔
بلعم بن باعور(اگر ان آیات کی تفسیربیان کرنے والی روایات کے مطابق بلعم باعوراہی مراد ہو)ان لوگو ں میں سے تھا جنھوں نے اپنے علم کی لگام خواہشات کے سپردکر دی اور انھیں کے پیچھے چل پڑے اب قرآن مجید کے الفا ظ میں اس شخص کا انجام ملاحظہ فرما ئیے :
اگران روایات کو تسلیم کر لیا جائے تو آیۂ کر یمہ میں اگر چہ بلعم باعور کے قصہ کی طرف ہی اشارہ ہے لیکن یہ باتیں ہراس شخص کیلئے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر اپنے خواہشات کو حاکم بنادے۔
جیسا کہ امام محمد باقر کا ارشاد گرامی ہے :
(ن الاصل فی ذلک بلعم،ثم ضرب ﷲمثلاًلکل مؤثرهواه علی هدیٰ ﷲ،من أهل القبلة )( ۱ )
''یعنی یہ تذکرہ تو در اصل بلعم کا ہی ہے لیکن خداوندعالم نے اسمیں ہر اس مسلمان کی مثال بیان کر دی ہے جو اپنی خواہشات کو ﷲ تعالیٰ کی ہدایت پر ترجیح دیتا ہو ''
ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتاہے ہمیں قرآنی بیانات کی روشنی میں اس پر بھی غور کرنا چاہئے۔
۱۔زمین کی جانب رغبت
زمین کی طرف رغبت ،دنیاوی زندگی سے دلبستگی کو کہتے ہیں یعنی انسان دنیا کا ہو کر رہ جائے۔کیونکہ زمین دنیاہی کا دوسرا نام ہے اور زمین کی طرف جھکا ئو ،رغبت اس سے بیزاری کے ذریعہ رفعت و بلندی کے مقابلہ میں ہے جیسا کہ آیۂ کریمہ میں اللہ تعا لیٰ کا ارشاد ہے :
( ولوشئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الیٰ الارض )
'' اگر ہم چا ہتے تو اسے انھیں آیات کے ذریعہ بلند کردیتے لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا ''
یعنی اس نے خود دنیا وی ذلت کو گلے لگا لیا ۔کیونکہ جس طرح سطح زمین سے بلندی کی طرف اوپر جا تے ہوئے زمین کی قوت جاذبہ اور کشش کا مقابلہ کر نے میںزحمت ومشقت ہوتی ہے مگر اس کے برعکس اوپر سے زمین کی طرف آتے وقت زمین کی کشش کا سہار ا مل جاتاہے ۔۔۔بالکل یہی حال زندگانی دنیا کی پستی اور بلندی کابھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بلندیوں کا خواہاں ہے تو اسے اتنی ہی مشقتیں برداشت کرنا ہو نگی لیکن اگر کوئی پستیوںمیں جانا چاہتاہے تو اس میں کوئی زحمت نہیں ہے ۔
۲۔آیات خدا سے محرومی
(فانسلخ منہا )آیات الٰہیہ سے ''انسلاخ'' یعنی اسکے پاس آیات کی جومعرفت اورعلم
____________________
(۱)مجمع البیان تفسیرسورئہ اعراف آیت ۱۷۵۔۱۷۶۔
و حکمت و بصیرت کی جو دولت تھی وہ اس سے واپس لے لی گئی۔
''انسلاخ'' ''ا لتصاق'' کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے التصاق اس وقت کہا جاتاہے کہ جب دوچیزیں آپس میں ملی ہوئی یاچپکی ہوتی ہیں اور جب ان کے در میان مکمل علاحدگی یابالکل جدا ئی ہو جائے تو اہل عرب اسکو'' انسلاخ ''کہتے ہیں لہٰذا جو لوگ اپنی شہو توں اور خواہشات کے تحت ،قدم اٹھا تے ہیں انکا ر ابطہ علم ومعرفت اور آیات الٰہیہ سے با لکل ختم ہو جاتا ہے اور جس طرح کسی مریض کا معدہ کھانے کوقبول کرنے کے بجائے اسے رد کردیتا ہے اسی طرح انکا نفس علم وحکمت جیسی پا کیزہ اورنفیس اشیا ء کوقبول نہیں کر پاتا ہے ۔
کیونکہ اگراسکا وجود ہو س اور خواہشات کا دلدا دہ ہو جائے تو پھر اسمیں آیات الٰہیہ ،علم و حکمت اوربصیرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اور نہ ہی اسکے وجود میں اخلاقی اقدار وفضائل کا گذر ہوسکتا ہے ۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے منقول ہے :
(حرام علیٰ کل قلب متولّه بالشهوات أن یسکنه الورع )( ۱ )
''یعنی جو دل بھی خواہشات کا دلداد ہ ہو اسکے اندر ورع و پرہیزگاری کا بسیرا حرام ہے '' آپ کا ہی ارشاد ہے :
(حرام علیٰ کل قلب اُغری بالشهوات أن یحل فی ملکوت السمٰوات )( ۲ )
''جودل خواہشات کا فریب خوردہ ہو اس کیلئے ''ملکوت السمٰوات''کی سکونت حرام ہے ' '
____________________
(۱)مجمو عہ ورا م تنبیہ خواطرص ۳۶۲۔
(۲)گذشتہ حوالہ۔
(حرام علی کل قلب مغلول بالشهوة أن ینتفع بالحکمة )( ۱ )
''جو دل خواہشات کی زنجیروں سے جکڑاہو اسکے لئے حکمت سے استفادہ کر ناحرام ہے ۔''
کیونکہ دل ایک ظرف کی مانند ہے اور ایک ظرف میں خواہشات نفس اوریاد الٰہی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذااسکے اندریا ذکر الٰہی رہے گا یا خواہشات رہیں گے کیونکہ( مَاجعل ﷲ لرجل من قلبین فی جوفه ) ( ۲ )
'' خداوندعالم نے ایک انسان کے جسم میں دو قلب نہیں بنا ئے ہیں ''
لہٰذا جب انسان اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے تو پھر خود بخود اسکے دل سے یا دخدا نکل جاتی ہے اور اگر اسمیں یاد خدا آجا تی ہے تو پھر خواہشات کاامکان نہیں رہ جاتاہے۔
لہٰذا جس دل سے یاد خدا نکل جا ئے وہ خواہشات کے راستے پر چل پڑتا ہے جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
( ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتّبع هواه وکان أمره فرطا ) ( ۳ )
''اور ہر گز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یادسے محروم کردیا ہے وہ اپنی خواہشات کا پیرو کار ہے اور اسکا کام سراسر زیادتی کرنا ہے ۔ ''
خواہشات کی پیروی کایہ دوسرا انجام ہے۔
۳۔شیطان کا تسلط
ارشاد رب العزت ہے :(فأتبعہ الشیطان )''اور شیطان نے اسکا پیچھا پکڑلیا ۔'' پہلے
____________________
(۱)غرر الحکم ج۱ص۳۴۴۔
(۲)سورئہ ا حزاب آیت ۴۔
(۳)سورئہ کہف آیت۲۸۔
شیطان اس تک پہنچنے یا اس پر قبضہ کر نے سے عاجزتھا مگرخواہشات کی پیروی انسان پر شیطان کے قبضہ کو مستحکم بنادیتی ہے اور انسان جتنی زیادہ خواہشات کی پیروی کرے گا اس پر شیطان کا تسلط اور غلبہ بھی اتنا ہی زیادہ مستحکم ہو جائے گا اور یہ خواہشات کی پیروی کا تیسرا نتیجہ ہے ۔
۴۔ضلا لت و گمراہی
(فکان من الغاوین)''تو وہ گمراہوں میں ہوگیا ''ایسے لوگوں کے سلسلہ میں یہ ایک فطری چیز ہے کیونکہ جب انسان ہویٰ وہوس میں مبتلا ہو جاتاہے اور اس کے دل سے یاد الٰہی نکل جاتی ہے اس پر شیطان کا تسلط قائم ہوجاتاہے تو پھر اسکی ہدایت کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا اور اسکی زندگی میںاصلاح کا امکان نہیں ہے لہٰذا وہ جس مقدار میں ہاتھ پیرمارتا ہے اتنا ہی پستیوں میں اترتا چلا جاتا ہے ۔اوریہ خواہشات کی پیروی کا چوتھا نتیجہ ہے۔
۵۔لالچ
ان لوگوں کے بارے میں ارشادا لٰہی ہے :
( فمثلُه کمثل الکلب اِنْ تحملْ علیه یَلْهَثْ او تترکه یلهثْ )
''تو اب اسکی مثال اس کتّے جیسی ہے کہ اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے اور چھوڑدو تو بھی زبان نکالے رہے''
زبان باہر نکلی رہنا یہ کتوں کی ایک مشہور بیماری ہے اور اسمیں کتے کو ہر وقت پیا س لگی رہتی ہے چنانچہ اسے چاہے جتنا پانی پلا یا جائے اسکی پیاس نہیں بجھ پاتی اور اسی لئے وہ ہمیشہ اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے اورچاہے کوئی اس پر حملہ کرے یا اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے ہر وقت اسکا ایک ہی حال رہتا ہے چنانچہ بالکل اسی صور تحال سے اہل ہوس بھی دوچار رہتے ہیں کہ دنیاوی لذتوں اور رنگینیوں میں غرق ہو نے کے باوجود انکی پیاس نہیںبجھتی چاہے وہ ما لدارہوں یا فقیر انہیں دنیا مل گئی ہو یانہ ملی ہو ان سب کا حال پیاس کے مریض اس کتے کی طرح رہتا ہے جسکی پیاس بہتے دریا بھی نہیں بجھا پاتے ہیں ۔
اسی بارے میں رسول ﷲصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا ہے :
( لوکان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغیٰ وراء هما ثالثاً ) ( ۱ )
''اگر فرزند آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تب بھی اسے تیسری وادی کی خواہش رہتی ہے''
امام جعفر صادق سے جب ایک آدمی نے اپنے اندر دنیا کی لا لچ اور اسکی طرف توجہ رہنے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا :جو چیز تمہا رے لئے کافی ہے اوروہ تمھیں مستغنی بنادے تو اسکی معمولی مقدار بھی تمہیں مستغنی بنا سکتی ہے لیکن جو چیز تمہارے لئے کا فی ہے اگروہ تمہیں مستغنی نہ بنا سکے تو پھر پور ی دنیا بھی تمھیں مستغنی نہیں بنا سکتی ہے اور یہ اس کا پا نچواں نتیجہ ہے ۔( ۲ )
____________________
(۱)مجمو عہ وارم تنبیہ خوا طرص ۱۶۳۔
(۲)اصول کافی ج۲ص۱۳۹
خواہشات کا علاج
ہوس کی تخریبی طاقت
انسانی خو اہشات اس کیلئے جس مقدار میں مفید ہیں اس کے مطا بق انکے اندر قدرت اور طاقت بھی پا ئی جاتی ہے چنانچہ اگر یہ غلط راستے پر لگ جائیں تو پھر یہ اپنی طاقت کے اعتبار سے ہی انسانی زندگی کو تہہ وبالا کر کے رکھ دیتی ہیں ۔۔۔انسانی نفس کے اندر اسکے یہ دونوں (مثبت اورمفید منفی اورمضر )پہلو بالکل طے شدہ ہیں اور اس میں کسی شک وشبہ کی گنجا ئش نہیں ہے کیونکہ خواہشات ہی دراصل انسان کی زندگی کے پہیوںکو گردش دینے والی قوت ہیں اور اگر خداوندعالم نے انسان کے
نفس میں جنسیات ،مال ،خود ی (حب ذات )،کھا نے پینے اور اپنے دفاع کی محبت نہ رکھی ہوتی تو قافلۂ انسانی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتاتھا ۔لہٰذا خواہشات کے اندر جتنے فا ئد ے ہیں انکے اندر اتنی ہی طاقت موجود ہے اور انکے اندر جتنی طاقت پائی جاتی ہے انکے بہک جانے کی صورت میں انکے نقصانات بھی اسی کے مطابق ہونگے جیسا کہ مولا ئے کا ئنات نے ارشاد فرمایا ہے:
(الغضب مفسد للالباب ومبعد عن الصواب )( ۱ )
''غصہ عقلوں کو برباد اور راہ حق سے دور کر دینے والی چیز ہے ''
آپ نے یہ بھی فرما یا ہے :
(أکثرمصارع العقول تحت بریق المطامع )( ۲ )
''عقلوں کی اکثر قتل گاہیں طمع کی جگہوںکی چمک دمک کے آس پاس ہیں''
خواہشات کی پیروی پر روک اور انکی آزادی کے درمیان
یہی وجہ ہے کہ خواہشات کو ایکدم کچل کر رکھ دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ خواہش انسانی زندگی کیلئے ایک مفید طاقت ہے جس کے سہار ے کا روان حیات انسانی رواں دواںہے اور اس کو معطل اور نا کارہ بنا دینا یا اسکی مذمت کرنا اور اسکی اہمیت کا اعتراف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے ایک بڑے حصہ کا انکار کردیا جائے اور اسکو نقل و حرکت میں رکھنے والی اصل طاقت کو نا کار ہ قرار دیدیا جائے ۔
اسی طرح خواہشات اور ہوس کی لگام کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا اور انکے ہر مطالبہ کی تکمیل کرنا اور ان کی ہر بات میںہاں سے ہاں ملا نا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ان کی رسی ڈھیلی چھو ڑدی جائے تو
____________________
(۱)غرر الحکم ج۱ص۶۷ ۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۱۹۸۔
یہ فائد ہ مند ہو نے کے بجائے انسان کیلئے مضر بن جاتے ہیں ۔
لہٰذا ہمیں یہ اعتراف کر نا پڑیگا کہ شرعی اعتبار سے خواہشات کی محدود تکمیل کی بہت اہمیت ہے اور جس طرح انکو بالکل آزاد چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے اسی طرح ہر بات میں انکی تکمیل بھی صحیح نہیں ہے ۔
اسی معیار پر اسلام نے خواہشات کے بارے میں اپنے احکام بنائے ہیں یعنی پہلے وہ خواہشات کو انسان کیلئے ضروری سمجھتا ہے اور اسے فضول چیز قرار نہیں دیتا جیسا کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم کاارشاد ہے :
( زُیّن للناسِ حبُّ الشهواتِ من النسائِ والبنینَ والقناطیرِالمقنطرةِمن الذهبِ والفضة ِوالخیلِ المسوّمةِ والأنعام والحرثِ ) ( ۱ )
''لوگوں کے لئے خواہشات دنیا ،عورتیں،اولاد،سونے چاندی کے ڈھیر،تندرست گھوڑے یا چوپائے کھیتیاںسب مزین اور آراستہ کردی گئیں ہیں ''
دوسری آیت میں ارشاد ہے :
(ا( ٔلمالُ والبنونَ زینة الحیاةِ الدنیا ) ( ۲ )
''مال اور اولاد، زندگانی دنیا کی زنیت ہیں ''
ان آیات میں نہ صرف یہ کہ خواہشات کی مذمت نہیں ہے بلکہ اسکو زینت اور جمال زندگانی قرار دیا گیاہے اور اسی اہم نکتہ سے خواہشات کے بار ے میں اسلام کا واضح نظر یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے ۔
دوسر ے مرحلہ پر اس نے ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کر نے اور دنیاوی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کا حکم دیا ہے :
____________________
(۱)آل عمر ان آیت۱۴۔
(۲) سورئہ کہف آیت۴۶ ۔
( کلوا من طیبات مارزقناکم ) ( ۱ )
''تم ہمارے پاکیزہ رزق کو کھائو ''
یایہ ارشاد الٰہی ہے :
( ولا تنس نصیبک من الدنیا ) ( ۲ )
''اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جائو''
اور اسی طرح یہ بھی ارشاد ہے :
( قل من حرّم زینة ﷲ التی أخرج لعبادهِ والطیبات من الرزق ) ( ۳ )
''پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کردیا ہے''
خواہشات کے بارے میں اسلام نے یہ دوسرا نظریہ پیش کیا ہے جس کے اندر نہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی کھلی چھوٹ ہے کہ جس کا جس طرح دل چاہے وہ اپنی خواہشات کی پیاس بجھاتا رہے اور کسی قاعد ہ وقانون کے بغیر سر جھکا کر انھیں کے پیچھے چلتا رہے ۔
امام جعفر صادق نے فرما یا ہے :
(لاتدع النفس وهواها فن هواها رداها )( ۴ )
''اپنے نفس کو اسکے خواہشات کے اوپر نہ چھو ڑدو کیونکہ اسکے خواہشات میں اسکی پستی اور
____________________
(۱)سورئہ طہ آیت۸۱ ۔
(۲)سورئہ قصص آیت۷۷ ۔
(۳)سورئہ اعراف آیت ۳۲ ۔
(۴)اصول کافی ج۲ص۳۳۶۔
ذلت ہے ''
ان تمام پا بند یوں اور سختیوں کے باوجود اسلام نے انسانی خواہشات کی تسلی کیلئے ایک نظام بنا کر خود بھی اس کے بیحد موا قع فراہم کئے ہیں جیسے اسلام نے جنسیات کو حرام قرار نہیں دیا ہے اور نہ اس سے منع کیا ہے اور نہ ہی اسے کوئی بر ایا پست کام کہا ہے بلکہ خود اسکی طرف رغبت دلا ئی ہے اور اسکی تاکید کی ہے البتہ اسکے لئے کچھ شرعی قواعد و ضوابط بھی بنائے ہیں اسی طرح مال سے محبت کرنے کونہ اسلام منع کر تاہے اور نہ اسے بر اکہتا ہے بلکہ یہ تمام انسانو ں کیلئے مباح ہے البتہ اسکے لئے بھی کچھ قو اعد وقوانین مرتب کردئے گئے ہیں تا کہ مالی یا جنسی خواہشات وغیرہ کی تسلی کیلئے ہر شخص کے سامنے مواقع موجود رہیں اور کوئی شخص بھی بے راہ رو ی کا شکار نہ ہو نے پا ئے یہ خواہشات کے بارے میں اسلامی نظر یہ کا تیسر ا نکتہ ہے۔
خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لئے ''عقل ''کا کردار
خواہشات کو بغاوت اور سر کثی سے روکنے اور ہرلحاظ سے انکی تکمیل سے منع کرنے اور اسی طرح انکی تسلی کی معقول حدبندی کیلئے انسانی عقل میدان عمل میں ہمیشہ فعال رہتی ہے اور شاید اسی لئے عربی زبان میں عقل کو عقل کہا جاتا ہے کہ عقل کسی کو لگام لگانے یا پھند ے کو کہتے ہیںاور خدا نے عقل کو یہی ذمہ دار ی سونپی ہے کہ وہ خواہشات کو لگام لگا کر اپنے قابو میں رکھے جیسا کہ رسول اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم نے ارشاد فرما یا ہے :
(ن العقل عقال من الجهل،والنفس مثل أخبث الدواب )( ۱ )
''عقل جہالت سے بچانے والی لگام ہے اور نفس خبیث ترین چو پائے کی طرح ہے ''
روایات میں اسی مضمون کی طرف کثر ت سے اشارے موجود ہیں بطورنمونہ حضرت علی
____________________
(۱)بحارالانوار ج۱ص۱۱۷ ۔
کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرما ئیں :
٭(فکرک یهدیک لی الرشاد )( ۱ )
''تمہار ی فکر تمہیں رشدو ہدایت کی طرف رہنما ئی کرتی ہے ''
٭ (للنفوس خواطرللهویٰ،والعقول تزجر وتنهی ٰ)( ۲ )
''نفس کے اندر مختلف قسم کی خواہشات ابھرتی رہتی ہیں اور عقل ان سے منع کرتی رہتی ہے ''
٭ (للقلوب خواطر سوء والعقول تزجر منها )( ۳ )
''دلوں کے اندر برے خیالات پید ا ہو تے ہیں اور عقل ان سے بازر کھتی ہے ''
٭ (النفوس طلقة،لکن أیدی العقول تمسک اعنتها )( ۴ )
''نفس تو با لکل آزاد ہوتے ہیں لیکن عقلوں کے ہاتھ انکی لگام تھامے رہتے ہیں ''
٭ (ثمرةالعقل مقت الدنیا وقمع الهویٰ) ( ۵ )
''عقل کا پھل دنیا کی نا راضگی اور خو اہشات کی تا راجی ہے ''
مختصر یہ کہ انسانی زندگی میں اسکی عقل کا کار نامہ یہ ہے کہ وہ خواہشات کواپنے محدود تقاضو ں کے تحت کنٹرول کر تی ہے اور اس کی ہوس کو سر کشی اور بغا وت سے رو کتی رہتی ہے اور انسان کو اس کی خو اہشات کی تکمیل میں بے لگام نہیں رہنے دیتی لہٰذا جس کی عقل جتنی کامل اور پختہ ہو تی ہے وہ اپنی خو اہشات پر اتنی ہی مہارت اور آسانی سے غلبہ حا صل کر لیتا ہے ۔
____________________
(۱)غررالحکم ج۲ص۵۸۔
(۲)تحف العقول ص۹۶۔
(۳)غررالحکم ج۲ص۱۲۱۔
(۴)غررالحکم ج۱ص۱۰۹۔
(۵)غررالحکم ج۲ص۳۲۳۔
حضرت علی :
(العقل الکامل قاهرالطبع السوئ )( ۱ )
''عقل کا مل بری طبیعتوں پر غالب رہتی ہے ''
اور یہی نہیں بلکہ خواہشات پر کنڑول ہی انسان کی عقل سلیم کی پہچان ہے ۔
حضرت علی :
(حفظ العقل بمخالفة الهویٰ والعزوف عن الدنیا )( ۲ )
''خواہشات کی مخالفت اور دنیاسے بے رغبتی کے ذریعہ عقل محفوظ رہتی ہے ''
امام محمد باقر :
(لاعقل کمخالفة الهویٰ )( ۳ )
''خواہشات کی مخالفت سے بہتر کوئی عقل نہیں ہے''
حضرت علی :
(من جانب هواه صح عقله )( ۴ )
''جس نے اپنی خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کرلی اسکی عقل صحیح وسالم ہو جا ئے گی ''
ان احادیث سے بھی یہ روشن ہوتا ہے کہ عقل اور خواہشات دونوں ہی انسان کی زندگی کے دو اہم ستون ہیں ان میںسے خواہشات، انسانی حیات کے سفینہ کی نقل وحرکت اور اسکی تعمیرو ترتی میں پتوار کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور عقل اسکو بغاوت وسر کشی اور فتنہ وفساد کے خطرناک نشیب وفرازسے
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۸ص۹۔
(۲)غرر الحکم ج۱ص۳۴۵۔
(۳)بحارالانوار ج۷۸ص۱۶۴۔
(۴)بحارالانوار ج۱ص۱۶۰۔
نکال کر ساحل تک پہنچا نے کی اہم ذمہ داری ادا کرتی ہے ۔۔۔لہٰذا ہر انسان کے لئے جس طرح جسم وروح ضردری ہیں اسی طرح اس کے لئے ان دونوں کاوجودبھی ضروری ہے ۔
عقل اور دین
انسانی زندگی میں دین بھی وہی کردار ادا کرتا ہے جو عقل کا کر دار ہے یعنی جس طرح عقل ، خواہشات کو مختلف طریقوں سے اپنے قابو میں رکھتی ہے اسی طرح دین بھی انھیں بہکنے سے بچاتا رہتا
ہے یعنی عقل اور دین کے اندرہر طرح کی فکری اور عملی یکسانیت اور مطابقت پائی جاتی ہے کیونکہ دین ایک الٰہی فطرت ہے جیسا کہ آیۂ کر یمہ میں ارشاد ہے :
( فطرةﷲ التی فطرالناس علیهالاتبدیل لخلق ﷲذلک الدین القیم ) ( ۱ )
''دین وہ فطرت الٰہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الٰہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی ہے یقینا یہی سید ھا اور مستحکم دین ہے ''
وہ فطرت جو انسان کے اوپر حکمراں ہو تی ہے اور عقل بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ ''دین' 'ہے جسکے ذریعہ ﷲ تعالی نے حیات بشری کو دوام بخشا اور حیات بشری کے ذریعہ اسے قائم ودائم فرمایا لہٰذا دین بھی خواہشات کو کنڑول کر نے کے سلسلہ میں عقل کی امداد کرتاہے اور خود بھی اسی ذمہ داری کو ادا کرتاہے مختصر یہ کہ عقل اور دین ایک ہی سکے کے دورخ ہیں ۔
حضرت علی :
(العقل شرع من داخل،والشرع عقل من خارج )( ۲ )
''عقل بدن کی اندرونی شریعت اور شریعت بدن کے باہر موجود عقل کا نام ہے ''
____________________
(۱)سورئہ روم آیت ۳۰۔
(۲)کتاب جوان :آقا ئے محمد تقی فلسفی ج۱ص۲۶۵۔
امام مو سیٰ کا ظم :
(ﷲ علی الناس حجتین :حجة ظاهرة وحجة باطنة، فاماالظاهرة فالرسل والانبیاء والائمة عليهالسلام واماالباطنة فالعقول )( ۱ )
''لوگوں پر خدا وندعالم کی دوحجتیں (دلیلیں )ہیں ایک ظاہر ی حجت اور دوسری پوشیدہ اور باطنی حجت و دلیل۔ ظاہر ی دلیل انبیاء اور ائمہ ہیں جبکہ باطنی حجت عقل ہے ''
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :
(حجة ﷲعلیٰ العبادالنبی،والحجة فیما بین العباد وبین ﷲ العقل )( ۲ )
''بندوں کے اوپر خدا وندعالم کی حجت اسکے انبیاء ہیں اور خداوندعالم اور اسکے بندوں کے درمیان ،عقل حجت ہے ''
____________________
(۱)بحارالانوار ج۱ص۱۳۷۔
(۲)اصول کافی ج۱ص۲۵۔
عقل کے تین مراحل
انسانی زندگی میں عقل کے تین اہم کردار ہوتے ہیں :
۱۔ معرفت الٰہی۔
۲۔خداوندعالم نے جو کچھ اپنے بندوں پر واجب کیا ہے اسکی اطاعت کرنا کیونکہ ﷲتعالیٰ کی صحیح معرفت کا نتیجہ اسکی اطاعت اور بندگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
۳۔تقوائے ا لٰہی: یہ خداوندعالم کی اطاعت وبندگی کا دوسرا رخ ہے کیونکہ خداوندعالم کی اطاعت وبندگی کی بھی دوقسمیں ہیں ۔
۱۔واجبات کو بجالانا اور محرمات سے پر ہیز کرنا اور تقویٰ درحقیقت نفس کو محرمات سے باز
رکھنے کا نام ہے ۔اور شاید مندرجہ ذیل روایت میں بھی عقل کے مذکورہ تینوں مرحلوں کی وضاحت موجود ہے:
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :
(قُسّم العقل علیٰ ثلاثة أجزائ،فمن کانت فیه کمل عقله،ومن لم تکن فیه فلا عقل له:حسن المعرفة بﷲعزوجل،و حسن الطاعة ﷲ،وحسن الصبرعلیٰ أمره )( ۱ )
''عقل کے تین حصے کئے گئے ہیں لہٰذا جسکے اندر یہ تینوں حصے موجود ہوں اسکی عقل کامل ہے اور جسکے اندر یہ موجود نہ ہوں تواسکے پاس عقل بھی نہیں ہے !
۱۔حسن معرفت الٰہی (خداوندعالم کی بہتر ین شناخت ومعرفت اور حجت آوری)۔
۲۔ﷲکی بہترین اطاعت وبندگی ۔
۳۔اسکے احکامات پر اچھی طرح صبر کرنا ''
خدا کے احکام پر صبر کرنے کا دوسرا نام خواہشات پر قابو پانا ہے اور اس کو تقویٰ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ خواہشات پر قابو پانا اور انھیں اپنے کنڑول میں رکھنے کیلئے جتنا زیادہ صبر درکار ہے اتنا صبر کسی اور کام کیلئے درکار نہیں ہوتا ہے ۔
اب ان تینوں مراحل کی تفصیل ملا حظہ فرمائیں :
۱۔معر فت اور حجت آوری
عقل کی پہلی ذمہ داری معرفت اور شناخت ہے ۔کیونکہ اس دنیا کے حقائق اور اسرار سے پر دہ اٹھا نے کا ذریعہ(آلہ )عقل ہی ہے اگرچہ اہل تصوف اسکے مخالف ہیں اور وہ عقل کی معرفت اور
____________________
(۱)بحارالانوارج۱ص۱۰۶۔
شناخت کے قائل ہی نہیں ہیں انکا کہنا ہے کہ اس دنیا کے حقائق اور خداوندعالم اور اسی طرح غیب کی معرفت کے بارے میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتاہے ۔جبکہ اسلام عقل کی قوت تشخیص کا قائل ہے اور وہ اسے علم ومعرفت کا ایک آلہ قراردیتا ہے اور دنیا کے مادی یا غیر مادی تمام مقامات پریا اس دنیا کے خالق یا واجبات اور محرمات جیسے تمام مسائل میں اس کی مز ید تا ئید کرتا ہے ۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے :
(نمایدرک الخیرکله فی العقل )( ۱ )
'' ہرخیر کو عقل میں تلاش کیا جاسکتا ہے ''
آپ ہی کا یہ ارشاد بھی ہے :
(استرشدوا العقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا )( ۲ )
''عقل سے رہنمائی حاصل کرو تو راستہ مل جائے گا اوراسکی نافرمانی نہ کرنا ورنہ شرمندگی اٹھانا پڑے گی ''
حضرت علی :
(العقل أصل العلم وداعیة الفهم )( ۳ )
''عقل ،علم کی بنیاد اور فہم (غوروفکر)کی طرف دعوت دینے والی ہے''
امام جعفر صادق :
(العقل دلیل المؤمن )( ۴ )
____________________
(۱)تحف العقول ص۵۴ ۔ بحارالانوا ر ج ۷۷ ص۱۵۸۔
(۲)اصول کافی ج۱ص۲۵۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۱۰۲۔
(۴)اصول کافی ج۱ص۲۵۔
''عقل مومن کی رہنما ہے''
دنیا کے حقائق اور اسرار ورموز کی معرفت کیلئے عقل کی قدروقیمت اور اہمیت کیا ہے؟ اسکو روایات میں یوں بیان کیا گیا ہے:''خداوند عالم اپنے بندوں پر عقل کے ذریعہ ہی احتجاج (دلیل) پیش کریگا اور اسی کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائیگی ''اس مختصر سے جملہ کے ذریعہ انسانی زندگی میں عقل کی قدروقیمت اور دین خدا میں اسکی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
امام موسی کاظم :
(أن ﷲ علیٰ الناس حجتین حجة ظاهرة وحجة باطنة،فأماالظاهرة فالرسل والانبیاء والائمة عليهالسلام ،وأما الباطنة فالعقول )( ۱ )
''بندوں پر خداوند عالم کی دوحجتیں (دلیلیں)ہیں ایک کھلی ہوئی اور ظاہر ہے اور دوسری پوشیدہ ہے ظاہری حجت اسکے رسول، انبیاء اور ائمہ ہیں اور پوشیدہ حجت کا نام عقل ہے''
آپ ہی کا یہ ارشاد گرامی ہے:
(ان ﷲ عزوجل أکمل للناس الحجج بالعقول،وأفضیٰ لیهم بالبیان،ودلّهم علیٰ ربوبیته بالادلة )( ۲ )
''خداوند عالم نے عقلوں کے ذریعہ لوگوں پر اپنی سب حجتیں تمام کردی ہیں اوربیان سے ان کی وضاحت فرمادی اور دلیلوں کے ذریعہ اپنی ربوبیت کی طرف ان کی رہنمائی کردی ہے''
لہٰذاعقل ،انسان کے اوپر خداوند عالم کی حجت اور دلیل ہے جسکے ذریعہ وہ اپنے بندوں کا فیصلہ کرتا ہے اوراگر فہم وادراک کی اسی صلاحیت کی بناء پر اسلام نے عقل کو اس اہمیت اور عظمت سے
____________________
(۱)بحارالانوار ج۱ ص ۱۳۷۔
(۲)بحارالانوار ج۱ص۱۳۲۔
نہ نوازا ہوتا تو وہ کبھی بھی حجت اور دلیل نہیں بن سکتی تھی اور اسکے مطابق فیصلہ ممکن نہیں تھا۔
یہی وجہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ خداوند عالم عقل کے مطابق ہی جزا یا سزا دیگا۔
۲۔اطاعت خدا
جب فہم وادراک اورنظری معرفت کے میدان میں عقل کی اس قدر اہمیت ہے۔۔۔تو اسی نظری معرفت کے نتیجہ میں عملی معرفت پیدا ہوتی ہے جسکی بنا پر انسان کیلئے کچھ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز واجب ہوجاتا ہے ۔
چنانچہ جس نظری معرفت کے نتیجہ میںعملی معرفت پیدا ہوتی ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کے مقام ربوبیت والوہیت کو پہچان لے اور اس طرح اسکی عبودیت اور بندگی کے مقام کی معرفت بھی پیدا کرلے اورجب انسان یہ معرفت حاصل کرلیتاہے تو اس پر خداوند عالم کے احکام کی اطاعت وفرمانبرداری واجب ہوجاتی ہے۔
یہ معرفت ،عقل کے خصوصیات میں سے ایک ہے اور یہی وہ معرفت ہے جو انسان کو خدا کے اوامر کی اطاعت اور نواہی سے پرہیز (واجبات و محرمات )کا ذمہ دار اور انکی ادائیگی یا مخالفت کی صورت میں جزاوسزا کا مستحق قرار دیتی ہے اور اگر معرفت نظری کے بعد یہ معرفت عملی نہ پائی جائے تو پھر انسان کے اوپر اوامر اور نواہی الٰہیہ نافذ(لاگو)نہیں ہوسکتے یعنی نہ اسکے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور نہ ہی اسکو جزااور سزا کا مستحق قرار دیا جاسکتا ہے۔
اسی بیان کی طرف مندرجہ ذیل روایات میں اشارہ موجود ہے:
امام محمد باقر نے فرمایا ہے:
(لماخلق ﷲ العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل،ثم قال له أدبرفأدبر،ثم قال له:وعزّتی وجلا لی ماخلقت خلقاً هوأحب لیّ منک،ولااکملک الافیمن احبأمانی یّاک آمرو یّاکأنهیٰ ویّاک اُعاقب ویّاک أثیب )( ۱ )
''یعنی جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق فرمایا تو اسے گویا ہونے کاحکم دیا پھر اس سے فرمایا سامنے آ،تو وہ سامنے آگئی اسکے بعد فرمایا پیچھے ہٹ جا تو وہ پیچھے ہٹ گئی تو پروردگار نے اس سے فرمایا کہ میری عزت وجلالت کی قسم میں نے تجھ سے زیادہ اپنی محبوب کوئی اور مخلوق پیدا نہیں کی ہے اور میں تجھے اسکے اندر کامل کرونگا جس سے مجھے محبت ہوگی۔یاد رکھ کہ میں صرف اور صرف تیرے ہی مطابق کوئی حکم دونگا اور تیرے ہی مطابق کسی چیز سے منع کرونگا اور صرف تیرے مطابق عذا ب کرونگا اور تیرے ہی اعتبار سے ثواب دونگا''
امام جعفر صادق نے فرمایا:
(لماخلق ﷲ عزوجل العقل قال له ادبرفادبر،ثم قال اقبل فاقبل،فقال وعزتی وجلالی ماخلقت خلقاً احسن منک،یّاک آمرویّاک انهی،یّاک اُثیب ویّاکاُعاقب )( ۲ )
''جب ﷲ تعالی نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا واپس پلٹ جا تو وہ واپس پلٹ گئی اسکے بعد فرمایا سامنے آ ،تو وہ آگئی تو ارشاد فرمایا کہ میری عزت وجلالت کی قسم : میں نے تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے لہٰذا صرف اور صرف تیرے ہی مطابق امرونہی کرونگا اور صرف اورصرف تیرے ہی مطابق ثواب یا عذاب دونگا''
بعینہ یہی مضمون دوسری روایات میں بھی موجود ہے ۔( ۳ )
ان روایات میں اس بات کی طرف کنایہ واشارہ پایا جاتا ہے کہ عقل، خداوند عالم کی مطیع
____________________
(۱)اصول کافی ج۱ص۱۰۔
(۲)بحارالانوارج۱ص۹۶۔
(۳)بحارالانوار ج۱ ص ۹۷ ۔
وفرمانبردار مخلوق ہے کہ جب اسے حکم دیا گیا کہ سامنے آ، تو سامنے آگئی اور جب کہا گیا کہ واپس پلٹ جا تو وہ واپس پلٹ گئی ۔
روایات میں اس طرح کے اشارے اورکنائے ایک عام بات ہے۔
علم وعمل کے درمیان رابطہ کے بارے میں حضرت علی کا یہ ارشاد ہے:
(العاقل اذا علم عمل،واذا عمل اخلص )( ۱ )
'' عاقل جب کوئی چیز جان لیتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے اور جب عمل کرتا ہے تو اسکی نیت خالص رہتی ہے''
ﷲ تعالیٰ کی اطاعت وبندگی اور اسکے احکامات کی فرمانبرداری میں عقل کیا کردار ادا کرتی ہے اسکے بارے میں اسلامی کتابو ں میں روایات موجود ہیں جنمیں سے ہم نمونے کے طورپر صرف چند روایات ذکر کر رہے ہیں۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :
(العاقل من أطاع ﷲ )( ۲ )
''عاقل وہ ہے جو خدا کا فرمانبردار ہو''
روایت ہے کہ نبی اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے سوال کیا گیا کہ عقل کیا ہے؟
قال :(العمل بطاعة الله،ان العمال بطاعة الله هم العقلاء )
''فرمایا :حکم خدا کے مطابق عمل کرنا، بیشک اطاعت خدا کے مطابق چلنے والے ہی صاحبان عقل ہیں''( ۳ )
____________________
(۱)غررالحکم ج۱ص۱۰۱۔
(۲)بحارالانوارج۱ص۱۶۰۔
(۳)بحارالانوار ج۱ص۱۳۱۔
امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا کہ عقل کیا ہے؟تو آپ نے فرمایا :
''جس سے خداوند عالم (رحمن)کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کی جائے''راوی کہتا ہے کہ میںنے عرض کیا کہ پھر معاویہ کے اندر کیا تھا؟فرمایا:وہ چال بازی اور شیطنت تھی''( ۱ )
حضرت علی :(اعقلکم اطوعکم )( ۲ )
''سب سے بڑا عاقل وہ ہے جو سب سے زیادہ اطاعت گذار ہو''
امام جعفر صادق :
(العاقل من کان ذلولاً عند اجابة الحق )( ۳ )
''عاقل وہ ہے جو دعوت حق کو لبیک کہتے وقت اپنے کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھے''
۳۔خواہشات کے مقابلہ کے لئے صبروتحمل(خواہشات کا دفاع)
یہ وہ تیسری فضیلت ہے جس سے خداوند عالم نے انسانی عقل کو نوازا ہے ۔اور یہ عقل کی ایک بنیادی اور دشوار گذار نیزاہم ذمہ داری ہے جیسا کہ ہم پہلے عرض کرچکے ہیں کہ اسکی یہ ذمہ داری اطاعت الٰہی کا ہی ایک دوسرا رخ تصور کی جاتی ہے بلکہ در حقیقت(واجبات پر عمل اور محرمات سے پرہیز)ہی اطاعت خدا کے مصداق ہیں اور ان کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ پہلی صورت میں واجبات پر عمل کرکے اسکی اطاعت کی جاتی ہے اور دوسری صورت میں اسکی حرام کردہ چیزوں سے پر ہیز کرکے خواہشات سے اپنے نفس کو روک کر اوران پر صبرکر کے اسکی فرمانبرداری کیجاتی ہے اس بنا پر عقل کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ خواہشات نفس کواپنے قابو میں رکھے اورانھیں اس طرح اپنے ماتحت رکھے کہ وہ کبھی اپنا سر نہ اٹھا سکیں۔
____________________
(۱)بحارالانوارج۱ص۱۱۶۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۱۷۹۔
(۳)بحارالانوار ج۱ص۱۳۰۔
خواہشات نفس کوکنڑول کرنے کے بارے میں عقل کی اس ڈیوٹی کے سلسلہ میں بیحد تاکید کی گئی ہے۔نمونہ کے طور پر حضرت علی کے مندرجہ ذیل اقوال حاضر خدمت ہیں:
٭(العقل حسام قاطع )( ۱ )
''عقل (خواہشات کو)کاٹ دینے والی تیز شمشیر ہے''
٭ (قاتل هواک بعقلک )( ۲ )
''اپنی عقل کے ذریعہ اپنی خواہشات سے جنگ کرو''
٭ (للنفوس خواطرللهویٰ،والعقول تزجر وتنهیٰ )( ۳ )
''نفس کے اندر ہویٰ وہوس کی بنا پر مختلف حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور عقل ان سے منع کرتی ہے''
٭ (للقلوب خواطر سوء والعقول تزجرمنها )( ۴ )
''دلوں پر برے خیالات کا گذر ہوتا ہے تو عقل ان سے روکتی ہے''
٭ (العاقل من غلب هواه،ولم یبع آخرته بدنیاه )( ۵ )
''عاقل وہ ہے جو اپنی خواہش کا مالک ہو اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے عوض فروخت نہ کرے''
٭ (العاقل من هجرشهوته،وباع دنیاه بآخرته )( ۶ )
''عاقل وہ ہے جو اپنی شہوت سے بالکل دور ہوجائے اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت کے عوض
____________________
(۱)نہج البلاغہ ۔
(۲)گذشتہ حوالہ۔
(۳)تحف العقول ص۹۶۔
(۴)غررالحکم ج۲ص۱۲۱۔
(۵)غررالحکم ج۱ ص ۰۴ ۱ ۔
(۶)غررالحکم ج۱ص۸۶۔
فروخت کرڈالے''
٭ (العاقل عدولذ ته والجاهل عبد شهوته )( ۱ )
''عاقل اپنی لذتوں کا دشمن ہوتا ہے اور جاہل اپنی شہوت کا غلام ہوتا ہے''
٭ (العاقل من عصیٰ هواه فی طاعة ربه )( ۲ )
''عاقل وہ ہے جو اطاعت الٰہی کے لئے اپنی خواہش نفس (ہوس)کی مخالفت کرے''
٭ (العاقل من غلب نوازع أهویته )( ۳ )
''عاقل وہ ہے جو اپنے خواہشات کی لغزشوں پر غلبہ رکھے''
٭ (العاقل من أمات شهوته،والقوی من قمع لذته )( ۴ )
''عاقل وہ ہے جو اپنی شہوت کو مردہ بنادے اور قوی وہ ہے جو اپنی لذتوں کا قلع قمع کردے''
لہٰذا عقل کے تین مرحلے ہیں:
۱۔معرفت خدا
۲۔واجبات میں اسکی اطاعت
۳۔جن خواہشات نفس اور محرمات سے ﷲ تعالی نے منع کیا ہے ان سے پرہیز کرنا۔
اس باب (بحث)میں ہماری منظور نظر عقل کا یہی تیسراکردارہے یعنی اس میں ہم خواہشات کے مقابلہ کا طریقہ ان پر قابو حاصل کرنے نیز انھیں کنٹرول کرنے کے طریقے بیان کرینگے ۔لہٰذا اب آپ نفس کے اندر عقل اور خواہشات کے درمیان موجود خلفشار اور کشمکش کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں:
____________________
(۱)غررالحکم ج۱ص۲۸۔
(۲)غررالحکم ج۲ص۸۷۔
(۳)غررالحکم ج۲ص۱۲۰۔
(۴)غررالحکم ج۲ص۵۸۔
عقل اور خواہشات کی کشمکش اور انسان کی آخری منزل کی نشاندہی
عقل اور خواہشات کے درمیان جو جنگ بھڑکتی ہے اس سے انسان کے آخری انجام کی نشاندہی ہوجاتی ہے کہ وہ سعادت مند ہونے والا ہے یا بد بخت ؟
یعنی نفس کی اندرونی جنگ دنیاکے تمام لوگوں کو دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کردیتی ہے :
۱۔متقی
۲۔فاسق وفاجر
اس طرح بشری عادات و کردار کی بھی دوقسمیں ہیں:
۱۔تقویٰ وپرہیزگاری(نیک کردار)
۲۔فسق وفجور ( بد کردار)
تقویٰ یعنی خواہشات کے اوپر عقل کی حکومت اورفسق وفجور اور بد کرداری یعنی عقل کے اوپر خواہشات کا اندھا راج ،لہٰذا اسی دوراہے سے ہر انسان کی سعادت یا بدبختی کے راستے شمال و جنوب کے راستوں کی طرح ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوجاتے ہیںاور اصحاب یمین (نیک افراد) اور اصحاب شمال (یعنی برے لوگوں)کے درمیان یہ جدائی بالکل حقیقی اور جوہری جدائی ہے جس میں کسی طرح کا اتصال ممکن نہیں ہے۔اور یہ جدائی اسی دو راہے سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ اپنی خواہشات پر اپنی عقل کو حاکم رکھتے ہیں لہٰذا وہ متقی،صالح اور نیک کردار بن جاتے ہیں اور کچھ اپنی عقل کی باگ ڈوراپنی خواہشات کے حوالہ کردیتے ہیں لہٰذا وہ فاسق وفاجر بن جاتے ہیں اس طرح اہل دنیا دوحصوں میں بٹے ہوئے ہیں کچھ کا راستہ خدا تک پہنچتا ہے اور کچھ جہنم کی آگ کی تہوں میں پہونچ جاتے ہیں۔
امیر المومنین نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے:
(من غلب عقله هواه افلح،ومن غلب هواه عقله افتضح )( ۱ )
''جس کی عقل اسکی خواہشات پر غالب ہے وہ کامیاب وکامران ہے اور جسکی عقل کے اوپر اسکے خواہشات غلبہ پیدا کرلیں وہ رسواو ذلیل ہوگیا''
آپ نے ہی یہ ارشاد فرمایا ہے:
(العقل صاحب جیش الرحمٰن،والهویٰ قائد جیش الشیطان والنفس متجاذبة بینهما،فأیهمایغلب کانت فی حیّزه )( ۲ )
''عقل لشکر رحمن کی سپہ سالارہے اور خواہشات شیطان کے لشکر کی سردار ہیں اور نفس ان دونوں کے درمیان کشمکش اور کھنچائو کا شکاررہتا ہے چنانچہ ان میں جو غالب آجاتا ہے نفس اسکے ماتحت رہتا ہے''
اس طرح نفس کے اندر یہ جنگ جاری رہتی ہے اور نفس ان دونوں کے درمیان معلق رہتا ہے جب انمیں سے کوئی ایک اس جنگ کو جیت لیتا ہے تو انسان کا نفس بھی اسکی حکومت کے ماتحت چلاجاتا ہے اب چاہے عقل کامیاب ہوجائے یا خواہشات۔
حضرت علی :
(العقل والشهوة ضدان، مؤید العقل العلم،مزین الشهوة الهویٰ،والنفس متنازعة بینهما،فأیهما قهرکانت فی جانبه )( ۳ )
''عقل اور شہوت ایک دوسرے کی ضد ہیں عقل کا مددگار علم ہے اور شہوت کو زینت بخشنے والی چیز
____________________
(۱)غررالحکم ج۲ص۱۸۷۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۱۱۳۔
(۳)گذشتہ حوالہ ۔
ہوس اور خواہشات ہیں اور نفس ان دونوں کے درمیان متذبذب رہتا ہے چنانچہ انمیں سے جوغالبآجاتا ہے نفس بھی اسی کی طرف ہوجاتا ہے''
یعنی نفس کے بارے میں عقل اور خواہشات کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے ۔چنانچہ انمیں سے جوغالب آجاتا ہے انسان کا نفس بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے۔
ضعف عقل اورقوت ہوس
شہوت(خواہشات)اور عقل کی وہ بنیادی لڑائی جسکے بعد انسان کی آخری منزل (سعادت وشقاوت) معین ہوتی ہے اس میں خواہشات کا پلڑاعقل کے مقابلہ میں کافی بھاری رہتا ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ عقل فہم وادراک کا ایک آلہ ہے جبکہ خواہشات جسم کے اندر انسان کو متحرک بنانے والی ایک مضبوط طاقت ہے۔
اور یہ طے شدہ بات ہے کہ عقل ہرقدم سوچ سمجھ کر اٹھاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسکو نفس کی قوت محرکہ نہیں کہاجاتا ہے۔
جبکہ خواہشات کے اندر انسان کو کسی کام پر اکسانے بلکہ بھڑکانے کے لئے اعلیٰ درجہ کی قدرت وطاقت وافرمقدار میں پائی جاتی ہے۔
حضرت علی نے فرمایا:
(کم من عقل اسیرعند هویٰ امیر )( ۱ )
''کتنی عقلیں خواہشات کے آمرانہ پنجوںمیں گرفتار ہیں''
خواہشات انسان کو لالچ اور دھوکہ کے ذریعہ پستیوں کی طرف لیجاتی ہیں اور انسان بھی ان کے ساتھ پھسلتا چلا جاتا ہے ۔جبکہ عقل انسان کو ان چیزوںکی طرف دعوت دیتی ہے جن سے اسے نفرت ہے اور وہ انھیں پسند نہیں کرتا ہے۔
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت۲۱۱
امیر المومنین فرماتے ہیں:
(اکره نفسک علی الفضائل،فان الرذائل انت مطبوع علیها )( ۱ )
''نیک کام کرنے کے لئے اپنے نفس کے اوپر زور ڈالو،کیونکہ برائیوں کی طرف تو تم خود بخودجاتے ہو''
کیونکہ خواہشات کے مطابق چلتے وقت راستہ بالکل مزاج کے مطابق گویاڈھلان دار ہوتا ہے لہٰذاوہ اسکے اوپر بآسانی پستی کی طرف اتر تا چلاجاتا ہے لیکن کمالات اور اچھائیوں میں کیونکہ انسان کا رخ بلند یو ںکی طرف ہوتا ہے لہٰذا اس صورت میںہر ایک کو زحمت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ عقل اور شہوت کے درمیان جو بھی جنگ چھڑتی ہے اس میں شہوتیں اپنے تمام لائو لشکر اور بھر پور قدرت وطاقت اور اثرات کے ساتھ میدان میں اترتی ہیں اوراسکے سامنے عقل کمزور پڑجاتی ہے۔
اور اکثر اوقات جب عقل اور خواہشات کے درمیان مقابلہ کی نوبت آتی ہے تو عقل کو ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں کیونکہ وہ اسکے اوپر اس طرح حاوی ہوجاتی ہیں کہ اسکو میدان چھوڑنے پر مجبور کردیتی ہیں اور اسکا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیکر اسے بالکل لاچار بنادیتی ہیں۔
____________________
(۱)مستدرک وسائل الشیعہ ج ۲ ص۳۱۰۔
عقل کے لشکر
پروردگار عالم نے انسان کے اندر ایک مجموعہ کے تحت کچھ ایسی قوتیں ، اسباب اور ذرائع جمع کردئے ہیں جو مشکل مرحلوں میں عقل کی امداد اور پشت پناہی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور نفس کے اندر یہ خیروبرکت کا مجموعہ انسان کی فطرت ،ضمیر اورنیک جذبات (عواطف)کے عین مطابق ہے اور اس مجموعہ میں خواہشات کے مقابلہ میں انسان کو تحریک کرنے کی تمام صلاحیتیں پائی جاتی ہیں
اور یہ خواہشات اور ہوس کو روکنے اور ان پر قابو پانے اور خاص طور سے ہوی وہوس کو کچلنے کے لئے عقل کی معاون ثابت ہوتی ہیں۔
کیونکہ(جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیںکہ) عقل تو فہم وادراک اور علم ومعرفت کا ایک آلہ ہے۔ جو انسان کو چیزوں کی صحیح تشخیص اور افہام وتفہیم کی قوت عطا کرتا ہے اور تنہااسکے اندر خواہشات کے سیلاب کو روکنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔لہٰذا ایسے مواقع پر عقل خواہشات کو کنٹرول کرنے اور ان پر قابو پانے کے لئے ان اسباب اور ذرائع کا سہارا لیتی ہے جوخداوند عالم نے انسان کے نفس کے اندر ودیعت کئے ہیںاور اس طرح عقل کیلئے خواہشات کا مقابلہ اورانکا دفاع کرنے کی قوت پیدا ہوجاتی ہے لہٰذاان اسباب کے پورے مجموعہ کو اسلامی اخلاقیات اور تہذیب و تمدن کی زبان میں عقل کے لشکروں کا نام دیا گیا ہے۔جو ہر اعتبار سے ایک اسم بامسمّیٰ ہے۔
نمونہ کے طور پر اسکی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:
کبھی کبھی انسان مال و دولت کی محبت کے جذبہ کے دبائو میں آکر غلط اور نا جا ئز راستوں سے دولت اکٹھا کرنے لگتا ہے ۔کیونکہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی حد تک مال و دولت کی محبت پائی جاتی ہے مگر بسا اوقات وہ اس میں افراط سے کام لیتا ہے ۔ایسے مواقع پر انسانی عقل ہر نفس کے اندر موجود ''عزت نفس ''کے ذخیرہ سے امداد حا صل کرتی ہے چنا نچہ جہاں تو ہین اور ذلت کا اندیشہ ہو تا ہے عزت نفس اسے وہاں سے دولت حاصل کرنے سے روک دیتی ہے اگر چہ اس میں کو ئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جس جگہ بھی تو ہین اور ذلت کا خطرہ ہو تا ہے عقل اسکو اس سے اچھی طرح آگاہ کر دیتی ہے لیکن پھر بھی ایسے مو اقع پر مال و دو لت سمیٹنے سے روکنے کے لئے عقل کی رہنما ئی تنہا کا فی نہیں ہے بلکہ اسے عزت نفس کا تعا ون درکارہوتاہے جسکو حاصل کرکے وہ حب مال کی ہوس اور جذبہ کا مقابلہ کرتی ہے ۔
۲۔جنسی خو ا ہشات انسان کے اندر سب سے زیادہ قوی خو ا ہشات ہو تی ہیں اوران کے دبائو کے بعد انسان اپنی جنسی جذبات کی تسلی کے لئے طرح طرح کے غلط اور حرام راستوں پردوڑتا چلا جاتا ہے اور اس میں بھی کو ئی شک و شبہہ نہیں ہے کہ ایسے اکثر حالات میں عقل جنسی بے راہ روی کے غلط مقامات کا بخوبی مقابلہ نہیں کر پاتی اور اسے صحیح الفطرت انسان کے نفس کے اندر مو جود ایک اور فطری طاقت یعنی عفت نفس (پاک دامنی )کی مدد حا صل کرنا پڑتی ہے ۔چنانچہ جب انسان کے سامنے اس کی عفت اور پاکدا منی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس بری حرکت سے رک جاتا ہے ۔
۳۔کبھی کبھی انسان کے اندرسربلندی ،انانیت اور غرور وتکبر کا اتنا مادہ پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے سامنے دوسروں کو بالکل ذلیل اور پست سمجھنے لگتا ہے اور یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو عقل ہر اعتبار سے برا سمجھتی ہے اسکے باوجود جب تک عقل، نفس کے اندر خداوند عالم کی ودیعت کردہ قوت تواضع سے امداد حاصل نہ کرے وہ اس غرور و تکبر کا مقابلہ نہیں کرسکتی ہے۔
۴۔کبھی کبھی انسان اپنے نفس کے اندر موجود ایک طاقت یعنی غیظ وغضب اور غصہ کا شکار ہوجاتا ہے جسکے نتیجہ میں وہ دوسروں کی توہین اور بے عزتی کرنے لگتا ہے۔چنانچہ یہ کام عقل کی نگاہ با بصیرت میں کتنا ہی قبیح اور براکیوں نہ ہواسکے باوجود عقل صرف اورصرف اپنے بل بوتے پر انسان کے ہوش وحواس چھین لینے والی اس طاقت کا مقابلہ کرنے سے معذور ہے لہٰذا ایسے مواقع پر عقل، عام طور سے انسان کے اندر موجود ،رحم وکرم کی فطری قوت وطاقت کو سہارا بناتی ہے۔کیونکہ اس صفت (رحم وکرم)میں غصہ کے برابر یا بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی قوت اور صلاحیت پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان غصہ کی بنا پر کوئی جرم کرنا چاہتا ہے تو رحم وکرم کی مضبوط زنجیر یں اسکے ہاتھوں کو جکڑلیتی ہیں۔
۵۔اسی طرح انسان اپنی کسی اور خواہش کے اشارہ پر چلتا ہواخداوند عالم کی معصیت اور گناہ کے راستوں پر چلنے لگتا ہے تب عقل اسکو''خوف الٰہی''کے سہارے اس گناہ سے بچالیتی ہے۔
اس قسم کی اور بے شمار مثالیں موجود ہیں جن میں سے مذکورہ مثالیں ہم نے صرف وضاحت کے لئے بطور نمونہ پیش کردی ہیں ان کے علاوہ کسی وضاحت کے بغیر کچھ اورمثالیں ملاحظہ فرمالیں۔
جیسے نمک حرامی کے مقابلہ میں شکر نعمت، بغض و حسد کے مقابلہ کے لئے پیار ومحبت اورمایوسی کے مقابلہ میں رجاء وامید کی مدد حاصل کرتی ہے۔
لشکر عقل سے متعلق روایات
معصومین کی احادیث میں نفس کے اندر موجود پچھتّر صفات کو عقل کا لشکر کہا گیا ہے جن کا کام یہ ہے کہ یہ ان دوسری پچھتّر صفات کا مقابلہ کرتی ہیں جنہیں خواہشات اور ہوس یاحدیث کے مطابق جہل کا لشکر کہا جاتا ہے ۔
چنانچہ نفس کے اندر یہ دونوں متضاد صفتیں درحقیقت نفس کے دو اندرونی جنگی محاذوں کی صورت اختیار کرلیتے ہیں جن میں ایک محاذ پر عقل کی فوجوںاور دوسری جانب جہل یا خواہشات کے لشکروں کے درمیان مسلسل جنگ کے شعلے بھرکتے رہتے ہیں۔
علامہ مجلسی (رح)نے اپنی کتاب بحارالانوار کی پہلی جلدمیں اس سے متعلق امام جعفرصادق اور امام موسی کاظم سے بعض روایات نقل کی ہیںجن کو ہم ان کی سند کے ساتھ ذکر کررہے ہیں تاکہ آئندہ ان کی وضاحت میں آسانی رہے۔
پہلی روایت
سعد اور حمیری دونوں نے برقی سے انھوں نے علی بن حدید سے انھوں نے سماعہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ :میں امام جعفر صادق کی خدمت موجود تھا اور اس وقت آپ کی خدمت میں کچھ آپ کے چاہنے والے بھی حاضر تھے عقل اور جہل کا تذکرہ درمیان میں آگیا تو امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایاکہ: عقل اور اسکے لشکر کواور جہل اور اسکے لشکر کو پہچان لو تو ہدایت پاجائوگے۔ سماعہ کہتے ہیں کہ:میںنے عرض کی میں آپ پر قربان، جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنی روحانی مخلوقات میں اپنے نور کے عرش کے دائیں حصہ سے جس مخلوق کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ عقل ہے۔پھر اس سے فرمایا سامنے آ:تو وہ سامنے حاضر ہوگئی پھر ارشاد فرمایا:واپس پلٹ جا تو وہ واپس پلٹ گئی ،تو ارشاد الٰہی ہوا، میں نے تجھے عظیم خلقت سے نوازا ہے اور تجھے اپنی تمام مخلوقات پر شرف بخشا ہے پھر آپ نے فرمایا:کہ پھر خداوند عالم نے جہل کو ظلمتوں کے کھار ی سمندرسے پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ پلٹ جا تو وہ پلٹ گیا پھر فرمایا : سامنے آ:تو اس نے اطاعت نہیں کی تو خداوند عالم نے اس سے فرمایا : تو نے غرور وتکبر سے کام لیا ہے؟پھر(خدانے) اس پر لعنت فرمائی ۔
اسکے بعد عقل کے پچھتّر لشکر قرار دئے جب جہل نے عقل کے لئے یہ عزت و تکریم اور عطا دیکھی تو اسکے اندر عقل کی دشمنی پیدا ہوگئی تو اس نے عرض کی اے میرے پروردگار، یہ بھی میری طرح ایک مخلوق ہے جسے تو نے پیدا کرکے عزت اور طاقت سے نوازا ہے۔اور میں اسکی ضد ہوں جبکہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے لہٰذا جیسی فوج تو نے اسے دی ہے مجھے بھی ایسی ہی زبردست فوج عنایت فرما۔تو ارشاد الٰہی ہوا :بالکل ( عطاکرونگا)لیکن اگر اسکے بعد تونے میری نا فرمانی کی تومیں تجھے تیرے لشکر سمیت اپنی رحمت سے باہر نکال دونگا اس نے کہا مجھے منظور ہے تو خداوند عالم نے اسے بھی پچھتّر لشکر عنایت فرما ئے ۔چنانچہ عقل اورجہل کو جو الگ الگ پچھتّر لشکر عنایت کئے گئے انکی تفصیل یہ ہے:
خیر، عقل کا وزیرہے اور اسکی ضد شر کو قرار دیا جو جہل کا وزیر ہے ۔
ایمان کی ضد کفر
تصدیق کی ضد انکار
رجاء (امید)کی ضد مایوسی
عدل کی ضد ظلم وجور
رضا(خشنودی )کی ضد ناراضگی
شکرکی ضد کفران(ناشکری)
لالچ کی ضد یاس
توکل کی ضدحرص
رافت کی ضدغلظت؟
رحمت کی ضد غضب
علم کی ضد جہل
فہم کی ضد حماقت
عفت کی ضد بے غیرتی
زہد کی ضد رغبت(دلچسپی)
قرابت کی ضدجدائی
خوف کی ضد جرائت
تواضع کی ضد تکبر
محبت کی ضدتسرع (جلد بازی)؟
علم کی ضد سفاہت
خاموشی کی ضد بکواس
سر سپردگی کی ضد استکبار
تسلیم(کسی کے سامنے تسلیم ہونا)کی ضدسرکشی
عفوکی ضد کینہ
نرمی کی ضد سختی
یقین کی ضد شک
صبر کی ضدجزع فزع (بے صبری کا اظہار کرنا)
خطا پر چشم پوشی (صفح)کی ضد انتقام
غنیٰ کی ضد فقر
تفکر کی ضد سہو
حافظہ کی ضد نسیان
عطوفت کی ضد قطع(تعلق)
قناعت کی ضد حرص
مواسات کی ضد محروم کرنا (کسی کا حق روکنا)
مودت کی ضد عداوت
وفا کی ضد غداری
اطاعت کی ضد معصیت
خضوع کی ضد اظہارسر بلندی
سلامتی کا ضد بلائ
حب کی ضد بغض
صدق کی ضد کذب
حق کی ضد باطل
امانت کی ضد خیانت
اخلاص کی ضد ملاوٹ
ذکاوت کی ضد کند ذہنی
فہم کی ضد ناسمجھی
معرفت کی ضد انکار
مدارات کی ضد رسوا کرنا
سلامت کی ضد غیب
کتمان کی ضد افشا(ظاہر کر دینا)
نماز کی ضد اسے ضائع کرنا
روزہ کی ضد افطار
جہاد کی ضد بزدلی(دشمن سے پیچھے ہٹ جانا)
حج کی ضد عہد شکنی
راز داری کی ضدفاش کرنا
والدین کے ساتھ نیکی کی ضد عاق والدین
حقیقت کی ضد ریا
معروف کی ضد منکر
ستر(پوشش)کی ضد برہنگی
تقیہ کی ضد ظاہر کرنا
انصاف کی ضدحمیت
ہوشیاری کی ضد بغاوت
صفائی کی ضدگندگی
حیاء کی ضد بے حیائی
قصد (استقامت )کی ضد عدوان
راحت کی ضدتعب(تھکن)
آسانی کی ضد مشکل
برکت کی ضدبے برکتی
عافیت کی ضد بلا
اعتدال کی ضد کثرت طلبی
حکمت کی ضد خواہش نفس
وقار کی ضد ہلکا پن
سعادت کی ضد شقاوت
توبہ کی ضد اصرار (برگناہ)
استغفار کی ضداغترار(دھوکہ میں مبتلارہنا)
احساس ذمہ داری کی ضد لاپرواہی
دعا کی ضدیعنی غرور وتکبر کا اظہار
نشاط کی ضد سستی
فرح(خوشی)کی ضد حزن
الفت کی ضد فرقت(جدائی)
سخاوت کی ضد بخل
پس عقل کے لشکروں کی یہ ساری صفتیں صرف نبی یا نبی کے وصی یا اسی بندئہ مومن میں ہی جمع ہوسکتی ہیں جس کے قلب کا اللہ نے ایمان کے لئے امتحان لے لیا ہو!البتہ ہمارے بقیہ چاہنے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جسمیںان لشکروں کی بعض صفتیںنہ پائی جائیں یہاں تک کہ جب وہ انہیں اپنے اندر کامل کرلے اور جہل کے لشکر سے چھٹکارا پا لے تو وہ بھی انبیاء اوراوصیاء کے اعلیٰ درجہ میں پہونچ جائے گا ۔بلا شبہ کامیابی عقل اور اسکے لشکر کی معرفت اور جہل نیز اس کے لشکر سے دوری کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے ۔
خداوند عالم ہمیں اور خصوصیت سے تم لوگوں کو اپنی اطاعت اور رضا کی توفیق عطا فرمائے ۔( ۱ )
دوسری روایت
ہشام بن حکم نے یہ روایت امام موسیٰ کاظم سے نقل کی ہے اور شیخ کلینی (رہ)نے اسے اصول کافی میں تحریر کیا ہے اور اسی سے علامہ مجلسی (رہ)نے اپنی کتاب بحارالانوار میں نقل کیاہے۔( ۲ )
یہ روایت چونکہ کچھ طویل ہے لہٰذا ہم صرف بقدر ضرورت اسکااقتباس پیش کر رہے ہیں:
امام موسی کاظم نے فرمایا :اے ہشام عقل اور اسکے لشکروں کو اور جہل اور اسکے لشکروں کو پہچان لو اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوجائو:ہشام نے عرض کی ہمیں تو صرف وہی معلوم ہے جوآپ نے سکھادیا ہے تو آپ نے فرمایا :اے ہشام بیشک خداوند عالم نے عقل کو پیدا کیا ہے اور ﷲ کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔۔۔پھر عقل کے لئے پچھتّر لشکر قرار دئے چنانچہ عقل کو جو پچھتّر لشکر دئے گئے وہ یہ ہیں:
خیر ،عقل کا وزیر اور شر، جہل کا وزیر ہے
ایمان، کفر
تصدیق، تکذیب
اخلاص ،نفاق
رجا ئ،ناامیدی
عدل،جور
خوشی ،ناراضگی
____________________
(۱)بحار الانوار ج۱ ص۱۰۹۔۱۱۱ کتاب العقل والجہل۔
(۲)اصول کافی جلد۱ص۱۳۔۲۳،بحارالانوار جلد۱ص۱۵۹۔
شکر، کفران(ناشکری)
طمع رحمت ،رحمت سے مایوسی
توکل،حرص
نرم دلی،قساوت قلب
علم، جہل
عفت ،بے حیائی
زہد،دنیا پرستی
خوش اخلاقی،بد اخلاقی
خوف ،جرائت
تواضع ،کبر
صبر،جلدبازی
ہوشیاری ،بے وقوفی
خاموشی،حذر
سرسپردگی، استکبار
تسلیم،اظہار سربلندی
عفو، کینہ
رحمت، سختی
یقین ،شک
صبر،بے صبری (جزع)
عفو،انتقام
استغنا(مالداری) ، فقر
تفکر،سہو
حفظ،نسیان
صلہ رحم، قطع تعلق
قناعت ،بے انتہالالچ
مواسات ،نہ دینا (منع)
مودت ،عداوت
وفاداری ،غداری
اطاعت، معصیت
خضوع ،اظہار سربلندی
صحت ،(سلامتی )بلائ
فہم ،غبی ہونا(کم سمجھی)
معرفت، انکار
مدارات،رسواکرنا
سلامة الغیب ،حیلہ وفریب
کتمان (حفظ راز)،افشائ
والدین کے ساتھ حسن سلوک ،عاق ہونا
حقیقت،ریا
معروف ،منکر
تقیہ،ظاہر کرنا
انصاف ،ظلم
خود سے دور کرنا،حسد
صفائی، گندگی
حیاء ،وقاحت
میانہ روی، اسراف
راحت وآسانی،زحمت(تھکن)
سہولت ،مشکل
عافیت ،بلا
اعتدال، کثرت طلبی
حکمت ،ہویٰ
وقار ،ہلکا پن
سعادت ،شقاوت
توبہ،اصراربرگناہ
اصرار ،خوف
دعا،غروروتکبر کی بناپر (دعاسے)دور رہنا
نشاط ،سستی
خوشی، حزن
الفت ،جدائی
سخاوت ،بخل
خشوع ،عجب
سچائی ،چغلخوری
استغفار،اغترار(دھوکہ میں مبتلارہنا)
زیرکی ،حماقت
اے ہشام! یہ خصلتیں صرف اور صرف کسی نبی یا وصی اور یا اس بندئہ مومن کے دل میں ہی جمع ہوسکتی ہیں جس کے قلب کو خداوند عالم نے ایمان کے لئے آز ما لیا ہولیکن دوسرے تمام مومنین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس میں عقل کے لشکروں کے بعض صفات نہ پائے جاتے ہو ں اوراگر وہ اپنی عقل کوکامل کرلے اور جہل کے لشکروں سے چھٹکارا حاصل کرلے تو پھر وہ بھی انبیاء اور اوصیا ئے الٰہی کے درجہ میں پہونچ جائے گا ﷲ ہم اور تم کو بھی اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے۔
روایت کی مختصر وضاحت:
عقل وجہل کی مذکورہ روایات میں متعدد غورطلب نکات پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض نکات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔
۱۔ان روایات کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن واحادیث کی طرح ان روایات میں بھی کنایہ دار اور رمزیہ زبان استعمال ہوئی ہے خاص طور سے انسان کی خلقت کے بارے میں کنایات واشارات کا پہلو بہت ہی زیادہ روشن ہے لہٰذا روایات اور ان کے معانی ومفاہیم کو سمجھنے کے لئے حدیث فہمی کے ذوق سلیم کی ضرورت ہے۔
۲۔دونوں روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم نے واپس پلٹنے (ادبار) کا حکم دیا تو عقل و جہل دونوں نے اسکی اطاعت کرلی ۔لیکن جب خداوند عالم نے سامنے آنے کا حکم دیا تواس موقع پر صرف اور صرف عقل نے اطاعت کی اور جہل نے حکم خدا سے سرپیچی کرتے ہوئے سامنے آنے سے انکار کردیا۔
اِن روایات میںجہل سے مراد خواہشات نفس ہیں جیسا کہ ان دونوںروایات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں میں ہی جہل کو عقل کی ضد قرار دیا گیا ہے۔
میرا خیال تو یہ ہے(اگر چہ خدا بہتر جانتا ہے)کہ یہاں(ادبار)واپس جانے کے حکم سے مراد حکم تکوینی ہے جس کی طرف اس آیۂ کریمہ میں اشارہ موجود ہے:
( واذا قضیٰ أمراً فانما یقول له کن فیکون ) ( ۱ )
''اور جب کسی امر کا فیصلہ کرلیتا ہے تو صرف '' کن'' کہتا ہے اور وہ چیز ہوجاتی ہے ''
اس حکم الٰہی کی پیروی اور پابندی میں عقل اور خواہشات حتی کہ پوری کائنات سبھی اس
اعتبار سے مشترک ہیںکہ جب خداوند عالم کوئی حکم دیتا ہے تو وہ سبھی اسکی اطاعت کرتے ہیں۔
( إنما قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون ) ( ۲ )
''ہم جس چیز کا ارادہ کرلیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہوجا اوروہ ہوجاتی ہے ''
( سبحانه إذا قضیٰ أمراً فإنّما یقول له کن فیکون ) ( ۳ )
''دہ پاک وبے نیاز ہے جب کسی بات کا فیصلہ کرلیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہوجا اور وہ چیز ہوجاتی ہے ''
چنانچہ جس طرح عقل اوراسکے لشکر خداوند عالم کے حکم تکوینی کی اطاعت کرتے ہیں اسی طرح خواہشات نفس نے بھی اسکے حکم کے مطابق عمل کیا ہے۔لیکن سامنے آنے کا حکم اوراسکے مقابلہ میں ادبار (واپس جانے)کا حکم اور ہوائے نفس کا اس معاملہ میں عقل کی مخالفت کرنا یہ دونوں اس بات کا قرینہ ہیں کہ اس حکم سے احکام(اوامر)تشریعی مراد ہیں اور یہی وہ احکام شرعی ہیںجن میں عقل
____________________
(۱)سورئہ بقرہ آیت ۱۱۷۔
(۲)سورئہ نحل آیت۴۰۔
(۳)سورئہ مریم آیت۳۵۔
اطاعت کرتی ہے اور ہوائے نفس انکی مخالفت کرتی ہے۔
۳۔ان دونوں روایا ت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عقل اور خواہشات کو دو الگ الگ مادوں سے بنایا گیا ہے ۔
جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ عقل خدا کی روحانی مخلوق ہے جس کو خداوند عالم نے اپنے نور اور عرش کے دائیں حصہ سے خلق کیا ہے جبکہ جہل (خواہشوں)کو خداوند عالم نے تاریکیوں کے کھاری سمندر سے پیدا کیاہے اگر چہ حتمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عقل اور خواہشات کا پہلا مادہ (عنصراولیہ) کیا ہے۔کیونکہ اسکا علم تو صرف انھیں ہستیوں کے پاس ہے جنھیں خداوند عالم نے تاویل احادیث کا علم ودیعت فرمایا ہے۔لیکن پھر بھی ان دونوں روایات کے مطابق اس بات میں کوئی شک وشبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ عقل کا اصل مواد اور عنصر (پہلا میٹیریل) فہم وادراک اور معرفت سے مشتق ہے جو کہ ﷲتعالی کا ہی ایک نو ر ہے خواہشات کا اصل مواد اور عنصر اس فہم وادراک اور معرفت سے خالی ہے۔بلکہ خواہشات تو حاجتوں اور مطالبات کی تاریکیوں کا ایک ایسا مجموعہ ہیں جن کے درمیان سے فہم وادراک کا گذر نہیں ہوپاتا جبکہ عقل تہ درتہ فہم اور فراستوں کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ دونوں خداوند عالم کی طرف سے انسان کی شخصیت کے بنیادی محور قرار دئے گئے ہیں؟
۴۔روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب عقل نے دونوں احکام کی اطاعت کرلی تو خداوند عالم نے اسکا احترام کیا اور اسے عزت بخشی لیکن جہل نے کیونکہ خدا کے حکم کی مخالفت کی تھی لہٰذا اللہ تعالی نے اس پر لعنت فرمائی اور لعنت یعنی رحمت خدا سے دور ہوجانا اور اسکی بارگاہ سے جھڑک دیا جانا ،گویا روایت یہ بتارہی ہے کہ انسان کی شخصیت کے دو بنیادی محور اور مرکز ہیں انمیں سے ایک اسے خداوند عالم سے قریب کرتا ہے تو دوسرا محور اسکو خدا سے دور کردیتا ہے اور یہ دونوں محور اور مرکز یعنی عقل اور خواہشات انسان کو بالکل دو متضاد زاویوں (راستوں اورمقاصد )کی طرف کھینچتے ہیں کیونکہ خدا نے انکو اسی طرح پیداکیا ہے ۔چنانچہ عقل انسان کو خدا کی طرف لیجاتی ہے ۔اور خواہشات اسے خداوند عالم سے دور کرتے رہتے ہیں ۔
۵۔دونوں روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب خداوند عالم نے عقل کو ۷۵لشکر عنایت فرمائے اور جہل نے بارگاہ الٰہی میں اپنی کمزور ی کی فریاد کی تو خداوند عالم نے اسے بھی اتنے ہی لشکر عنایت فرمادئے لیکن اس کے بعد اس سے یہ فرمایا :
(فانْ عصیت بعدذلک أخرجتک وجندک من رحمتی )
''اب اگر اسکے بعد تو نے میری نافرمانی کی تو میں تجھے تیرے لشکر سمیت اپنی رحمت کے دائرہ سے باہر نکال دونگا''
ہم اپنے قارئین کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان روایات میں اشارہ اور کنایہ کی زبان استعمال ہوئی ہے ۔لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ یہ گفتگو واقعاً خداوند عالم اور عقل وجہل کے درمیان ہوئی ہو بلکہ ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت اسلامی نظریہ کے مطابق خواہشات کی قدروقیمت اور اہمیت پر عمیق روشنی ڈالتی ہے ۔یعنی روایت میں جہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عقل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خداوند عالم سے قریب کرتی ہے اور خواہشات خدا سے دور کرتے ہیں۔۔۔وہیں روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ اگر خواہشات، خدا کی معصیت نہ کریں تو وہ خدا کی رحمت کے مستحق رہتے ہیں لیکن جب یہ انسان کو خدا کی نافرمانی اور معصیت پر لگادیتے ہیں تو رحمت خدا سے محروم ہوجاتے ہیں ۔
لہٰذا اسلام تمام خواہشات کو برا نہیں سمجھتا ہے ۔اور نہ ان کو انسان کے اوپر عذاب الٰہی قرار دتیا ہے بلکہ جب تک انسان خداوند عالم کی نافرمانی اور گناہ نہ کرلے یہ بھی عقل کی طرح انسان کے لئے ایک رحمت الٰہی ہے ۔البتہ جب یہ انسان کو خداوند عالم کی اطاعت کے حدود سے باہر نکال دیں اوراسے اسکی معصیت پر لگادیں تو پھر یہی رحمت اسکے لئے عذاب زندگی میں تبدیل ہوجاتی ہے ۔
چنانچہ دین کی طرف جو یہ نسبت دی جاتی ہے کہ وہ خواہشات ،لذتوں اور شہوتوں کا مخالف ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کے بالکل برعکس اسلام نے ہویٰ(خواہشات ) اور اسکے لشکر کو اس عظمت اور شرف سے نوازا کہ انہیں رحمت الٰہی کا مستحق قرار دیدیا ہے اور جب تک انسان گناہ کا مرتکب نہ ہو اسکے لئے اپنے خواہشات کی تسلی اور ان کی تکمیل جائز ہے اور یہ کوئی قبیح چیز نہیں ہے ۔بلکہ اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ اگر شرافت کے دائرے کے اندراور قاعدہ و قانون کے تحت رہ کران شہوتوں اور خواہشات کو پورا کیا جاتارہے تو یہی انسانی زندگی کی ترقی اور کمال کا بہترین ذریعہ بن جاتے ہیں ۔
۶۔روایات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجو د ہے کہ عقل کے دورخ (مرحلے )ہیں۔
پہلے مرحلے میں وہ کسی چیز کا ادراک کرتی ہے ۔اور دوسرے مرحلے میں اس کو عملی جامہ پہناتی ہے لہٰذا جتنی زیادہ مقدار میں عقل کے ساتھ اسکے لشکر اور صفات جمع ہوتے رہتے ہیں اسکی عملی شکل میں اضافہ ہوتارہتا ہے لیکن جو ں جوںاسکے خصائل اور لشکروں کی تعداد گھٹتی رہتی ہے اسکے عمل کی رفتار بھی اسی طرح کم ہوجاتی ہے ۔اور خواہشات پر اسکا کنٹرول بھی ڈھیلا پڑجاتا ہے ۔
روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ''یہ تمام صفات ایک ساتھ صرف کسی نبی ،وصیِ نبی یا اس مومن کے اندر جمع ہو سکتے ہیں جس کے دل کا امتحان خدا لے چکا ہے ۔لیکن دوسرے تمام مومنین کرام کے اندر انمیں سے کچھ نہ کچھ صفات ضرور پائے جاتے ہیں مگر ان بعض صفات سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جب تک وہ اپنے کو ان تمام صفات کا حامل نہ بنالیں اور جہل کے لشکر وںسے مکمل نجات حاصل نہ کرلیں تب تک وہ مومن کا مل نہیں ہو سکتے ہیں اور جس دن وہ اسمیں کامیاب ہوجائیں گے توانھیں بھی انبیاء واولیاء کے ساتھ جنت کے ا علی درجات میں سکونت نصیب ہوگی ''
اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ عقل کے تنفیذ ی ر خ کی تکمیل کا اثر اسکے دوسرے رخ پر پڑتا ہے اور اسکی فہم وفراست اور بصارت وبصیرت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔
اس طرح اس سلسلہ کی تینوں کڑیاں مکمل ہو جا ئینگی کہ:
جب انسان اپنے اندر عقل کے تمام لشکر اور صفات جمع کر لے تو پھر عقل عملی منزل میں قدم رکھنے اور خواہشات کا مقابلہ کر نے کی قوت پیدا کرلیتی ہے اور اسی سے اسکی فہم وفراست اور بصارت وبصیرت بھی کامل ہوجاتی ہے ۔اور نتیجہ ً انسان انبیاء اور اولیاء کے درجہ میں پہونچ جاتا ہے( جسکی طرف روایت نے اشارہ کیا ہے )اور یہی راستہ اور طریقہ جسکو روایت نے محدود اور مشخص کر دیا ہے یہی اسلام کی نگاہ میں تربیت کی بہترین اساس اوربنیاد نیز کردارو عمل کی تقویت کا باعث ہے ۔کیونکہ عقل،بصیرت اور تنفیذ کا نام ہے اور بصیرت کی کمزوری عقل کی تنفیذی قوت کی بنا پر پیدا ہوتی ہے اور یہ (قوت تنفیذ) عقل کی خصلتوں کی کمزوری کی وجہ سے کمزور رہتی ہے لہٰذا جب انسان اپنے نفس کے اندر ان تمام خصلتوں کو مکمل کر لیتا ہے تو بصیرت اور تنفیذ دونوں ہی لحاظ سے اسکی شخصیت مکمل ہوجاتی ہے۔
۷۔ان روایات نے بشری کرداروں کو دو مشخص اور معین حصوں میں تقسیم کردیا ہے :
۱۔تقوی(باعمل)
۲۔فسق وفجور(بے عملی)
تقویٰ اسے کہتے ہیں جس میں عقل کی پیروی کی جائے اور ہر قدم اسی کی مرضی کے مطابق اٹھے،اور فسق وفجور کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات اور جہل کے لشکروں کے اشاروں پر ہر عمل انجام پائے اور اسکے اوپر انہیں کا قبضہ ہو ،لہٰذا قرب خداکی منزل تک پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جہالت کے لشکروں سے نجات حاصل کرلے اور خواہشات کی سرحدوں کو روند کر عقل کی حکومت میں داخل ہوجائے اور اسکے ہر طرز عمل اور رفتار وکردار پر عقل کی حکمرانی ہو۔
۸۔مذکورہ فہرست میں بشری طرز عمل اور کردار کے طورطریقہ کے پچھترجوڑوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سے ہر جوڑا دو متضاد اعمال سے مل کر بناہے ۔یعنی ان میں سے ایک عقل کے طرز عمل کی فہرست میں شامل ہے اور دوسرا شہوت کے طریقۂ کار کی فہرست کے دائرہ میں آتا ہے ۔لہٰذا اس فہرست میں پچھتر عقل کے طریقۂ کار اور پچھتر شہوت کے کرتوت ذکر ہیں جن میں پہلے باترتیب عقل کے لشکر کے صفات ذکر ہوئے ہیں اور اسکی ہر صفت کے بعد اسی کی مخالف ،جہل کی صفت کا تذکرہ ہے
۹۔بشریت کے طرز عمل اور آداب وکردار کے صفات کی ان دونوں فہرستوں کو دیکھنے کے بعدیہ اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے انسان کے نفس میں ہر آرزو کو پورا کرنے کے لئے اور اسے ہویٰ و ہوس سے بچانے کے لئے ایک دفاعی طاقت بھی رکھی ہے ۔اور کیونکہ انسان کے تکامل اور تحرک کے لئے اسکے نفس میں خواہشات کا وجود ضروری ہے اسی لئے خداوندعالم نے ہر خواہش کو روکنے اور اسکا مقابلہ کرنے کے لئے اسمیں ایک صفت (قوت مدافعت) ودیعت فرمائی ہے تاکہ ان کا تعادل ہمیشہ برقرار رہ سکے۔
۱۰۔ایسا نہیں ہے کہ بشری طرز عمل کے جویہ ایک سو پچاس صفات ہیں یہ ایک عام اور معمولی صفت یا سر سری خصوصیات ہوں جو کبھی کبھی اسکے نفس پرطاری ہوجاتے ہوں بلکہ انسان کے تمام اعمال کی بنیادیں بہت گہری اور انکی جڑیں بہت وسیع حد تک پھیلی ہوئی ہیں لہٰذا انسان جو اچھائی یا برائی کر تا ہے اسکا تعلق نفس کے باطن سے ضرورہوتا ہے ۔جس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے :
( فا ٔلهمها فجورها وتقواها ) ( ۱ )
''اور پھر اسے بدی اور تقوی کی ہدایت کردی''
لہٰذا تقوی اور بدی میں سے ہر ایک کا سر چشمہ نفس ہی ہے اور یہ انسان کے طرز عمل میں کہیں باہر سے نہیں آتا ہے
۱ ۔ عقل کے لشکر (صفات )کی فہرست میں غورو فکرسے کام لینے والا شخص بآسانی ان کی دو قسمیں کر سکتا ہے :
____________________
(۱)سورئہ شمس آیت۸۔
۱۔اکسا نے اور مہمیز کرنے والی صفات ۔
۲۔روکنے والے قواعد(ضوابط )
اکسانے والے صفات ،نفس کو نیک اعمال پر ابھارنے اور مہمیز کر نے والے صفات کوکہا جاتا ہے ۔جیسے ایمان ،معرفت ،رحمت اورصداقت ۔
ضوابط وہ اسباب ہیں جن کے ذریعہ نفس کے اندر رکنے اور بازر ہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ۔ جیسے عفت ،زہد ،صبر ،قناعت اورحیاء ۔
اکسانے والے صفات ان تمام عادات وصفات کا مجموعہ ہیںجو انسان کی شخصیت میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور کسی بھی کارخیریا رحمت ومعرفت میں اسے جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کوپورا کرتے ہیں
لیکن ضوابط (قواعد )انسان کی شخصیت کو پستی میں گر نے سے محفوظ رکھتے ہیں اسطرح یہ مہمیز کرنے اور بچانے والے صفات ایک ساتھ مل کر ہی انسان کی شخصیت کی تعمیر اوراسکی حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں اور اس سلسلہ میں عقل کے مدد گار ثابت ہوتے ہیں ۔
اب اسکی مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیں :
انسانی زندگی میں عقل دوقسم کے عمل انجام دیتی ہے ۔
۱۔انسان کو ان مقاصد اور منزلوں کی طرف تحریک اور مہمیز کرنا جو اس کی ترقی اورتکامل کے لئے ضروری ہیں ۔
۲۔پرخطر جگہوں پر انسان کو لغزشوں سے محفوظ رکھنا ۔مثال کے طور پر انسان خدا وندعالم کی طرف سیر وسلوک کی منزلیں طے کرتاہوامنزل سعادت وکمال تک پہونچتا ہے ایسے مرحلہ میں عقل کا اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ذکرو عبادت الٰہی اور اسکی محبت کی دعوت دیتی ہے اور اپنی انا نیت سے خدا وندعالم کی طرف یہ سفر اور حرکت انسانی زندگی کی ایک اہم بنیادی ضرورت ہے۔
اس طرح مو منین کی آپسی محبت اور اخوت وبرادر ی کے ذریعہ انسان کی شخصیت کو چار چاند لگ جاتے ہیں جس کو اسلام نے ولاء ،اخوت و برادری اورپیار ومحبت کا نا م دیاہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشر ے میں تمام مومنین ایک دوسرے سے میل محبت رکھیں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ہر شہروالے دوسرے شہروالوںکے کام آئیں تنہائی اور انفرادیت سے سما جیات اور معاشرہ کی طرف قدم اٹھا نا بھی انسان کی ایک اہم ضرورت ہے ۔
یہ دونوں مثالیں تو عقل کے مثبت کاموں کے بارے میں تھیں مگر انسان ان دونوں راستوں میں خطا ولغزش کا شکار ہوتا رہتا ہے ۔چنا نچہ وہ انانیت (ذاتیات )سے خدا کی طرف بلند پر وا زی کے دوران اچانک اوپر سے نیچے کی طرف یعنی (خدا سے ذاتیات )کی طرف گرنا شروع کردیتا ہے اور یہ سب گناہ کرنے نیزخواہشات اور شیطانی وسوسو ں اور ہوس کے جال میں پھنسنے کی وجہ سے ہوتا ہے
اسی طرح کبھی کبھی انسان اپنے ذاتی مفادجیسے خود پسند ی یادوسروں سے بغض وحسد یا کسی چیز کی لالچ کی بنا پر سماج اورمعاشر ے پر فدا رہنے اورا سکے لئے بے شمار قربانیاں پیش کرنے کے باوجودقوم اور معاشرے پر اپنی ذات کو فوقیت دینے لگتا ہے ،ایسے مواقع پر عقل بہت موثر کردارکرتی ہے یعنی:
۱۔ ذاتیات اورانانیت سے اللہ کی طرف اور انفرادیت (تنہائی)سے سماج اور معاشرے کی طرف انسانی حرکت اور سفر میں ۔
۲۔اللہ سے انانیت کی طرف اور امت اورقوم میں غرق رہنے کے بجائے ذاتیات (شخصی فوائد )کی جانب اسی طرح ایثار سے استیثارو خود پسندی کی طرف واپسی کے تمام مراحل میں بھی عقل انسان کو خواہشات کی پیروی اور ان کے ساتھ پھسل جانے اور گمراہ ہونے سے روکتی رہتی ہے ۔
جب انسان آزاد انہ طورپر خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے ان کے دھارے میں بہہ کر خدا کی طرف جانے کے بجائے انانیت کی طرف جاتاہے،قوم کے لئے قربانی پیش کرنے کے بجائے ذاتی مفادات اور ایثار کے بجائے اپنی ذات کی طرف واپس پلٹنے لگتا ہے تبھی عقل اسکا راستہ روک لیتی ہے اگرچہ یہ دوسری بات ہے کہ تنہا عقل کے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا اور قوم وملت کی طرف انسانی حرکت یا انانیت اورذاتیات کی وجہ سے گمراہ ہوتے وقت اپنے بل بوتے پر تنہا ان دونوں مرحلوں کو سر کرلے لہٰذاوہ مجبوراً ان صفات اور عادات کا سہارا لیتی ہے جن کو خداوند عالم نے انسان کی عقل کی پشت پناہی اور امداد کے لئے نفس کے اندر ودیعت فرمایا ہے ۔
ان صفتوں اور عادتوں کی دو قسمیں:ہیں کچھ صفات وہ ہیں جو انانیت سے خدا کی طرف اور ذاتی مفادات سے قوم وملت پر فدا ہونے تک انسانی سفراور حرکت کے دوران اس کی شخصیت کی معاون ومددگار ہوتی ہیں اوربعض دوسرے صفات اس کو خواہشات نفس کا مقابلہ کرنے اور ان پر قابو پانے کی قوت وطاقت عطا کرتے ہیں ۔ جیسے خدا سے فطری لگائو اسی طرح محبت خدا اور ذکرو عبادت الٰہی سے فطری لگائو اوریہ جذبہ انسان کو خدا کی طرف اسی طرح کھینچتا ہے جس طرح سماجیات اور قوم وملت سے دلچسپی اور ان کی محبت اور بھائی چارگی کاجذبہ انسان کو قوم وملت کی طرف لیجاتا ہے ۔
عقل کی ان عادتوں کوکسی کام پر ''ابھارنے یااکسا نے اور مہمیز کرنے والی طاقت ''کہا جاتا ہے جبکہ ان کے علاوہ کچھ ایسی صفات بھی ہیں جو انسان کی عقل کو ان معاملات میں کنٹرول کرنے اور اسے باز رکھنے والی طاقتیں کہی جاتی ہیں۔جیسے حیاء انسان کو بد کرداری سے روکتی ہے یا علم و برد باری اسے غصہ سے باز رکھتا ہے تو عفت اور پاکدامنی ،جنسی بے راہ روی کا سد باب کرتی ہے ۔اور قناعت ، حرص اور لالچ سے محفوظ رکھتی ہے ۔وغیرہ غیرہ ۔۔۔
انہیں صفات کے مجموعہ کو انسانی حیات کے آداب (رفتار وگفتار اورکردار)میں ضوابط کانام دیا جاتا ہے ۔
یہی ضوابط ،عصم (بچا نے اور محفوظ کرنے والے ) صفات بھی کہے جاتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو گمراہی وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں اور اگر یہ عصمتیں (بچا نے والی قوتیں )انسان کے اندر نہ ہوتیں تو عقل کسی طرح بھی اپنے بل بوتے پر خواہشات نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور ان عصم (بچانے والی صفات )کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کی قوتیں اور صلاحتیں مختلف ہیں جن کے متعدد اسباب ہیں اسکی تفصیل ہم انشاء ﷲآئندہ بیان کر ینگے ۔
۱۲۔جن صفات اور خصوصیات کو ہم نے عقل کا لشکر قرار دیا ہے اور وہ عقل کی پشت پناہی کا کردار کرتے ہیں ان کاصحیح فائدہ اسی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب یہ عقل اور دین کے تابع ہوں لیکن اگر خدا نخواستہ یہ عقل اور دین کی حکومت سے باہر نکل جائیں تو پھر یہ انسان کے لئے مفید ہونے کے جائے نقصان دہ ہوجاتے ہیں جیسے رحم دلی انسان کے لئے ایک اچھی اور بہترین صفت ہے لیکن جب یہی صفت عقل اور دین کے دائرہ سے باہر نکل جائے تو یہی نقصان دہ ہوجاتی ہے جیسے مجرمین کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنے کو عقل اور دین دونوں نے منع کیا ہے جیسا کہ ارشا دالٰہی ہے :
( ولا تأخذکم بهما رأفة ) ( ۱ )
'' اور تمہیں ان کے اوپر ہر گز ترس نہ آئے ''
اسی طرح ا نفاق ایک اچھی صفت ہے مگرجب یہ عقل اور دین کے راستے سے منحرف ہوجا تی ہے تو تعمیر کے بجائے تخریب کرنے لگتی ہے اسی لئے دین اور عقل دونوں نے ہی ایسے مواقع پر اس سے منع کیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے :
( ولا تبسطهاکل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) ( ۲ )
''اور نہ اپنے ہا تھوں کو بالکل کھلا ہواچھوڑدوکہ آخر میں ملول اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جائو''
۱۳۔جہل کے لشکر چاہے جتنے قوی کیو ں نہ ہوں مگر اسکے باوجود وہ انسان کے اراد ہ کے او پر
____________________
(۱)سورہ نورآیت۲۔
(۲)سورہ اسراء آیت ۲۹۔
غلبہ حاصل نہیں کرسکتے ہیں اورا س سے اسکی قوت اراد ی نہیں چھین سکتے ہیں اور بالآ خر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے فیصلہ کا اختیار اسکے ارادہ کے ہی اختیار میں رہتا ہے البتہ کل ملا کرجہل کی فوجیںاتنا کر سکتی ہیںکہ وہ انسان کے ارادہ کے اوپر کسی طرح کا دبائو ڈال دیں اور وہ دبائو اتنا زیادہ ہو
جو اس اراد ہ کو عمل کے لئے تحریک کردے ، لیکن پھر بھی یہ انسان سے اس کی قوت ارادہ اوراسکی آزاد ی واختیارکو سلب نہیں کرسکتے ہیں ۔۔۔اگر چہ اس میں بھی کوئی شک وشبہہ نہیں ہے کہ عقل یا جہل کے صفات سے ارادہ کسی حدتک متاثر ضرور ہوتا ہے ۔
۱۴۔یہ ایک بنیاد ی مسئلہ ہے کہ عقل کے لشکر وں کی قوت وطاقت یا کمزوری کا تعلق انسان کی اچھی یا بری تربیت سے ہوتا ہے اگر واقعاً کسی کی اچھی تربیت ہو اور وہ متقی انسان ہوجائے تو عقل کی یہ خصلتیں قوی ہوجاتی ہیں اور خواہش نفس اورشہوتیں خود بخود کمزور پڑجاتی ہیں ۔
اسی طرح اسکے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ خواہشات کی اندھی پیر و ی اور غلط تربیت یا سماج کی وجہ سے جب انسان بگڑ جاتاہے توشہوتوںمیںمزیداضافہ ہوتا ہے اور عقل کے لشکر(صفات) کمزور پڑجاتے ہیں ۔
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بعض حلال خواہشات کی تکمیل سے بھی اکثر منع کیا ہے تا کہ انسان ان لذ تو ں (اور خواہشات)کے بہائو کے ساتھ غلط راستوں پر نہ بہنے پائے جیسا کہ رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اسی بارے میں یہ ارشادفرما یا ہے:
(من أکل مایشتهی لم ینظرﷲ الیه حتیٰ ینزع أویترک )( ۱ )
''جو شخص اپنی دل پسندچیز کھاتا رہے تو جب تک اسے ترک نہ کر دے یا اس سے دور نہ ہو جائے خداوند عالم اسکی طرف نظر بھی نہیںکرتا ہے''
اسکی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کھانے پینے میں اپنی ہر خواہش پوری کرتا رہے اور اپنے پیٹ
____________________
(۱)بحارالانوارج ۷۰ ،ص ۷۸۔ ح ۱۰۔
کے اوپر کنڑ ول نہ رکھے تو حلال کھاتے کھاتے ایک نہ ایک دن وہ حرام کھانا شروع کر دیگا۔(کیونکہ وہ اپنی پسند کا بندہ ہے )اور حرام خوری کرنے والے انسان پر رحمت الٰہی نازل نہیں ہوتی اور خدا اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے ۔
علما ء اخلاق نے خواہشات کو لطیف اور سبک بنانے کے لئے کچھ طریقے بیان کئے ہیں جیسا کہ ابراھیم خو اص نے کہا ہے کہ دل کی پانچ دوائیں ہیں :
ا۔ قرآت قرآن ۔ ۲۔خالی پیٹ (رہنا ) ۳۔نماز شب ۔
۴۔سحرکے ہنگام گریہ وبکا (تضرع ) ۵۔صالحین کی ہم نشینی ۔
کسی اور کا یہ قول ہے کہ خداوندعالم نے دلوں کو اپنے ذکر کا مسکن (گھر )بنا یاتھا ۔مگر وہ شہوتوںکا اڈہ بن گئے اور دلوں کے اندر سے یہ خواہشات انسان کوہلاکر رکھ دینے والے خوف یا تڑپادینے والے شوق کے بغیر نہیں نکل سکتی ہیں۔( ۱ )
خواہشات کو نرم ولطیف اور کمزور کرنے اور عقل کے لشکر وں کی امداد کرنے والی اس صفت کی طرف امیر المو منین نے خطبہ ٔ متقین میں یہ ارشاد فرمایا ہے:(قدأحیا عقله وأمات نفسه )
''اس نے اپنی عقل کوزندہ کر دیا اور اپنے نفس کومردہ بنا دیا''
اسلام میں تربیت وہی ہے جس کی طرف مولائے کائنات نے اشارہ فرمایا ہے کہ: اس کے ذریعہ خواہشات کی بڑی سے بڑی خصلتیں مختصراور لطیف ہوجاتی ہیں جن کی تعداد روایات میں ۷۵ بیان کی گئی ہے ۔ اسکے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وقت ضرورت یہ عقل کی ۷۵ صفتوں اور خصلتوں کی امداد اور پشت پناہی بھی کرتی رہتی ہے ۔
۱۵۔جب عقل کو اپنی خصلتوں کی جانب سے مکمل پشت پناہی حاصل ہوجاتی ہے تو پھر
____________________
(۱)ذم الہویٰ لابن الجوزی ص۷۰ ۔
خواہشات کے اوپر عقل کا کنٹرول اور حکومت قائم ہوجاتی ہے اور وہ ان کے اوپر اچھی طرح تسلط قائم کرلیتی ہے اور انسان کو محفوظ کر کے خواہشات کی طاقت کو بالکل ناکارہ بنادیتی ہے جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے :
(العقل الکامل قاهرللطبع السوئ )( ۱ )
''عقل کامل بری طبیعتوں پر غالب رہتی ہے''
اس طرح عام لوگوں کے خیالات کے بر خلاف انسان در حقیقت صرف اپنی خواہشوں پر کنٹرول کر کے ہی قوی اور طاقتور ہوتا ہے جبکہ عام لوگ تو خواہشات اور ہویٰ و ہوس کی حکومت اور غلبہ کو طاقت اور قوت سمجھتے ہیںمگر اسلام کی نگاہ میںخواہشات کو اپنے ماتحت رکھنے کا نام غلبہ اورقوت و طاقت ہے اور خواہشات کی حکومت اور اسکی ماتحتی میں چلے جانے کو طاقت اور غلبہ نہیں کہا جاتا۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :
(لیس الشدید من غلب الناس،ولکن الشدید من غلب نفسه )( ۲ )
''طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کرلے بلکہ طاقتور وہ ہے جو نفس کو اپنے قابو میں رکھے''
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم ہی کا یہ ارشاد گرامی ہے :
(لیس الشدید بالصرعة،انما الذی یملک نفسه عندالغضب )( ۳ )
''کشتی اور پہلوانی کے ذریعہ انسان طاقتور نہیں بنتا ہے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر اختیار رکھے''
____________________
(۱)بحارالانوارج۷۸ص۹۔
(۲)ذم الہوی ۳۹۔
(۳)مسنداحمد وبیہقی۔
آپ ہی کا یہ ارشاد گرامی ہے :
(أشجع الناس من غلب هواه )( ۱ )
''سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غلبہ حاصل کرلے''
____________________
(۱)بحار الانوار ج۷۰ ص ۷۶ ح۵۔
عقل کامل کے فوائداور اثرات
جب خواہشات کے اوپر ہر اعتبار سے عقل کا تسلط قائم ہوجاتا ہے اوراسے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے تمام اختیارات حاصل ہوجاتے ہیں تویہی عقل بے شمار فوائد اور برکتوں کے سرچشمہ میں تبدیل ہوجاتی ہے اور یہیں سے انسانی زندگی میں بے شمارانقلابات پیدا ہوتے ہیں اب انسانی حیات میں عقل کے فوائدکیا ہیںان کو ہم یہاں روایات کے ذیل میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور ان کی تفصیلات کو ترک کر رہے ہیں ۔
۱۔حق کے اوپر استقامت
حضرت علی :(ثمرة العقل الاستقامة )( ۲ )
''عقل کا پھل استقامت (ثابت قدمی )ہے''
(ثمرةالعقل لزوم الحق )( ۳ )
''عقل کا پھل حق کے ساتھ دائمی وابستگی ہے ''
۲۔دنیا سے دشمنی رکھناکامل عقل کا ثمر ہے
حضرت علی :
____________________
(۲)غررالحکم ج۱ص۳۲۰۔
(۳)گذشتہ حوالہ۔
(ثمرة العقل مقت الدنیا،وقمع الهویٰ )( ۱ )
''عقل کا پھل دنیا کو نا پسندرکھنااور خواہشات کو اکھاڑ پھینکنا ہے''
۳۔خواہشات پر مکمل تسلط
حضرت علی :
(اذاکمل العقل نقصت الشهوة )( ۲ )
''جب عقل کامل ہوجاتی ہے تو خواہشیں مختصر ہوجاتی ہیں ''
(من کمل عقله استهان بالشهوات )( ۳ )
''جسکی عقل مکمل ہوجاتی ہے وہ خواہشوں کو حقیر بنادیتا ہے ''
(العقل الکامل قاهرللطبع السوئ )( ۴ )
''عقل کامل بری طبیعتوں پر کنٹرول رکھتی ہے ''
۴۔حسن عمل اورسلامتی کردار
(من کمل عقله حسن عمله )( ۵ )
''جسکی عقل مکمل ہوگئی اسکا عمل حسین ہوگیا''
عصمتیں
روایات کے ذیل میں عقل کے صفات (لشکروں)کی وضاحت کے بعد اب ہم خواہشات
____________________
(۱)غررالحکم ج۱ص۳۲۳۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۲۷۹۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۱۸۰۔
(۴)بحارالانوار ج۷۸ص۹۔
(۵)گذشتہ حوالہ۔
کا مقابلہ کرنے کے طریقہ کے علاوہ ان کے علاج کا طریقہ بھی بیان کرینگے ۔
جیسا کہ ہم عرض کرچکے ہیں کہ عقل کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ تن تنہاخواہشات کا مقابلہ کرسکے۔اور اگر کبھی ایسا موقع آجائے تو عقل کو ان کے سامنے بہر حال گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑیگا۔لیکن چونکہ خداوند عالم نے خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لئے عقل کو اسکے معاون ومددگار صفات (اور لشکروں)سے نوازا ہے لہٰذا عقل کو ان کا مقابلہ کرنے یا انہیں کنٹرول کرنے میں کسی قسم کی زحمت کا سامنا نہیں ہوتا ہے اور یہ لشکر خود بخود بڑھ کر خواہشات کا راستہ روک لیتے ہیں اور ان کو بے راہ روی سے بچائے رکھتے ہیں ۔
جن صفات اور لشکروں کی امداد کے سہارے عقل خواہشات پر کنٹرول کرکے انہیں اپنے قابو میں رکھتی ہے انھیں اخلاقی دنیا میں عصم (محافظین عقل) کہا جاتا ہے ۔ لہٰذا عقل کے ان صفات کی صحیح تعلیم وتربیت اور پرورش اور نفس کے اندر ان کی بقاء و دوام ہی خواہشات نفس کے مقابلہ اور علاج کا سب سے بہترین اسلامی ،اخلاقی اورتربیتی طریقۂ کار ہے ۔
کیونکہ ان عصمتوں (محافظوں)کا فریضہ یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں میں آلودہ نہ ہونے دیں اور اسے حتی الامکان خواہشات کے چنگل سے محفوظ رکھیں۔ چنانچہ اگر نفس کے اندر خداوند عالم کے عطا کردہ یہ محافظ (عصمتیں)نہ ہوتے تو عقل تن تنہا کبھی بھی خواہشات کے حملوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھی،لیکن اب چونکہ اسکے ساتھ ان محافظین کی کمک اورپشت پناہی موجود ہے لہٰذا وہ آسانی کے ساتھ انسانی خواہشات کے اوپر ہر لحاظ سے قابو پالیتی ہے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے ۔
یہ عصمتیں (محافظین عقل) مختلف حالات سے گذرتی رہتی ہیں یعنی کبھی یہ قوی ہوجاتی ہیں اور کبھی بالکل کمزور پڑجاتی ہیں ۔چنانچہ جب یہ بالکل طاقتور ہوتی ہیں تو انسان کو ہر قسم کی برائی سے بچائے رکھتی ہیں اور اسے گناہ نہیں کرنے دیتیں لیکن اگر خدا نخواستہ یہ کمزور ہوجائیں تو پھر انسان کی ہوس اور خواہشات نفسانی اس پر غالب آجاتے ہیں اور وہ انھیں کا ہوکر رہ جاتا ہے ۔
یہ عصمتیں تقویٰ کے ذریعہ مضبوط ہوتی ہیں اور گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے کمزور پڑجاتی ہیں بلکہ گناہوں کا اثر ان کے اوپر اس حدتک ہوتا ہے کہ یہ بالکل چاک چاک اور پارہ پارہ ہوکر رہ جاتی ہیں جسکے بعدانسانی خواہشات اسکے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ بالکل بے یارومددگار ہوجاتاہے اور کوئی اسکا بچانے والا محافظ اور نگہبان باقی نہیں رہ جاتا ۔جیساکہ دعائے کمیل کے اس جملہ میں اسکی طرف اشارہ موجودہے :
(اللّهم اغفر لی الذنوب التی تهتک العصم )
''بارالٰہا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عصمتوں کو چاک چاک کردیتے ہیں ''
دوسری بات یہ کہ تقویٰ اور عصمتوں کے درمیان جو آپسی رابطہ ہے وہ طرفینی (دوطرفہ رابطہ)ہے یعنی اگر تقویٰ سے ان عصمتوں کو مدد ملتی ہے تو دوسری جانب یہ عصمتیں تقویٰ کی تقویت میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔
اس طرح گناہوں اور عصمتوں کے درمیان بھی دو طرفہ اثرات پائے جاتے ہیں یعنی جس طرح گناہ ،عصمتوں کوکمزور یا پارہ پارہ کردیتے ہیں اسی طرح اگر عصمت باقی نہ رہ جائے تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ خواہشات کے چنگل میں گرفتار ہوجاتا ہے ۔
یہ عصمتیں نفس کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں اور ان کی بنیادیں اور جڑیں فطرت کی تہوں میں اتری ہوتی ہیں اور خداوند عالم نے انسان کے نفس اور اسکی فطرت کے اندر ان (عصمتوں)کے خزانے جمع کر رکھے ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے معین کردہ فریضہ کی ادائیگی میں عقل کو سہارا دیتے ہیں ۔
جبکہ کچھ ماہرین سماجیات کا یہ خیال ہے کہ یہ عصمتیں نفس کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھیں بلکہ جس سماج اور معاشرے میں انسان زندگی بسر کرتا ہے وہ انہیں سے یہ عصمتیں بھی سیکھتا ہے اور درحقیقت یہ سماج ہی کے ذریعہ اسکے نفس کے اندر منتقل ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے سماج اور معاشروں کے اعتبار سے انکی قوت وطاقت اورمقدار کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے ۔
اس نظریہ میں اتنی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جن کا کوئی بھی جواب ممکن نہیں ہے ۔کیونکہ ذاتی خصلتوں ( اور اعمال)کا تعلق فطرت کی گہرائیوں سے ہوتا ہے البتہ ان کے اوپرمعا شرتی اور سماجی ماحول اثر انداز ضرور ہوتا ہے ا ور ان کو معاشرہ یا سماج سے جدا کردینا ممکن نہیں ہے ۔مگریہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ ذاتی عادات و اطوار سماجیات سے بالکل الگ ہوتے ہیںیعنی ہم دوسری قسم کو سماج پر اثر انداز ہونے والے کے عنوان سے قبول کرلیں اور انھیں کے لئے پہلی خصلت کو چھوڑدیں کیونکہ ذاتی خصوصیات کو بالکل کالعدم قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ ہی کسی بھی اچھے یا برے معاشرے سے ان کو جدا کیا جاسکتا ہے ۔
ان دونوںصلاحتیوں اور صفات (اور طرز تفکر)کے درمیان یہ فرق ہے کہ ذاتی صلاحتیں ہر دوراورہر تمدن میں تمام انسانوں کے درمیان بالکل یکساں طورپر دکھائی دینگی جبکہ سماجی رسم ورواج ہرروز پیدا ہوتے رہتے ہیں اورمختلف اسباب کی بنا پر کچھ دن کے بعد ختم ہوجاتے ہیں حتی کہ بعض علاقوںیاملکوں میں کچھ ایسے رسم ورواج پائے جاتے ہیں جن کو دوسرے ممالک میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے ۔
مثال کے طورپر خداوند عالم پر ایمان رکھناہر انسان کے اندر ایک ذاتی اور فطری چیز ہے جبکہ کفر والحاد ایک سماجی پیداوار ہے جو فطرت ایمان اور حتی خداوند عالم کے خلاف سرکشی اور بغاوت کے بعدپیدا ہوتاہے ۔
اگر چہ ایما ن اور کفر دونوں ہی کا وجود تقریباتاریخ انسانیت کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے۔لیکن اسکے باوجود ان کے درمیان بے حد فرق ہے کیونکہ ایمان خدا کا وجود تو انسانی تمدن ،تاریخ اور زندگی میں ہر جگہ مل جائے گااور کوئی بشری تاریخ بھی اس سے ہرگز خالی نہیں ہے ۔حتی کے سورج،چاند ،اور بتوںکی عبادت کا سرچشمہ بھی در اصل یہی ایمان ہے ۔یہ اور بات ہے کہ ان کا رخ صحیح فطرت کی طرف ہونے کے بجائے کسی دوسری طرف ہوگیا ہے ۔
لیکن الحاد کاوجود کسی تہذیب یافتہ سماج کے اندر نہیں دکھائی دیتا چنانچہ نہ جانے انسان کے اوپر ایسے کتنے دور گذرے ہیں جن میںالحا دکا باقاعدہ کہیں کوئی وجود اورسراغ نہیںپایا جاتا جس کو کسی تہذیب و تمدن اور عقل و منطق کی پشت پناہی بھی حاصل رہی ہو۔
لیکن ایمان کا وجود آپ کو پوری کائنات میں ہر جگہ نظر آئے گا مگرالحاد کبھی کبھی کچھ عرصہ تک ادھر ادھر اپنا سر ابھارتا ہے اور ایک دن خود بخود نابود ہوجاتا ہے ۔جیسا کہ سیاست اور تہذیب و تمدن نیز فکر انسانی کی تاریخ میں اس کا سب سے زیادہ عروج مارکسیسم کے دور میں ہوا جب باقاعدہ ایک سپر پاور حکومت کی پشت پناہی نے اس نظریہ کو عام کرنے کی کوشش کی مگر دنیا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اچانک اس کے غبارے کی ہوانکل گئی اور اب کوئی شخص مارکس کا نام لینے والا بھی نہیں ہے ۔
لیکن خداوند عالم پر ایمان کی صورتحال ایسی نہیں ہے ۔لہٰذا جو شخص خداوند عالم پر ایمان اور الحاد(اسکے انکار)کے درمیان فرق محسوس نہ کرسکے اس نے خود اپنے نفس کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ۔
عصمتوں کے بارے میں مزید گفتگو
کچھ عرصہ پہلے میں نے عصمت کے بارے میں چند صفحات قلمبند کئے تھے جو ہماری اس بحث سے مربوط ہیں لہٰذا مناسب سمجھا کہ اسکے کچھ مفید اقتباسات اس مقام پر شامل کردئے جائیں تاکہ گذشتہ گفتگو تشنہ ٔ تشریح نہ رہ جائے ۔
ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اوپر اسکی خواہشات کی حکومت بہت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے جسکی وجہ سے اسکے نقصانات بھی بیحد خطرناک ہوتے ہیں لہٰذا جب تک انسان اپنی خواہشات کو اچھی طرح اپنے قابو میں کرکے متعادل اور محدود نہ بنادے وہ زندگی میں خواہشات کے خطرات سے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے چنانچہ ہر انسان کے سرپر یہ خطرات ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا اخلاقی اور تربیتی نظام درکار ہے جو انسان کو اسکی انفرادی اور سماجی زندگی میں ہر جگہ خواہشات کے طوفان کا مقابلہ کرنے اور انہیں قابو میں رکھنے نیزاسکے نقصانات سے بچنے کی صلاحیت عطا کردے ۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نظام تربیت کیا ہے ؟جسکی پابندی کے بعد انسان اپنے خواہشات کے فریب سے محفوظ رہ سکتا ہے؟
اہل دنیا کے درمیان اس بارے میں چند نظریات پائے جاتے ہیں :
پہلا نظریہ رہبانیت کا ہے جس میں خواہشات کے مقابلہ کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ خواہشات کو نفس کے اندر اس طرح کچل دیا جائے کہ وہ اس میں گھٹ کر رہ جائیں اور اسکے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی کے حصول کی خاطر فتنہ انگیز اور بھڑکانے والی باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرلی جائے ۔ رہبانیت میں یہ نظریہ بالکل عام ہے اور اسکی جڑیں ان کی قدیم تاریخ کے اندر دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں ۔
اس مکتب فکر (نظریہ)کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہشات کوہر قسم کے فتنہ سے دور رکھاجائے اور دنیاوی لذت وآرام سے پرہیز کرکے ان سے دوری اختیار کی جائے ۔کیونکہ انسان کاخاصہ یہ ہے کہ وہ برائی پر اصرارکرتاہے اورچونکہ خواہشات اور فتنوں کے درمیان رابطہ پایا جاتاہے اور انسان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اسے فتنوں سے دور کردیا جائے ۔
لہٰذا خواہشات سے دوری اور دنیاکے فریبوں اور لذتوں سے کنارہ کشی میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے اور اس نظام کا ماحصل یہ ہے کہ خواہشات اور لذتوں کو بالکل ترک کرکے دنیا سے ایک دم کنارہ کشی اختیار کرلی جائے اور اسے ترک کئے بغیر اس مقصدتک رسائی ممکن نہیں ہے ۔
تہذیب و تمدن کے افکار کے درمیان یہ ایک مشہور و معروف نظریہ ہے جس کے اثرات موجودہ دور کی باقی ماندہ مسیحیت میں بھی پائے جاتے ہیں ۔
لیکن اسلام نے اس طرز تفکر کی بہت سختی سے مخالفت کی ہے کیونکہ اسکی نگاہ میں خواہشات کو کچل دینا یا دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیارکرلیناانسانی مشکلات کا حل نہیں ہے ۔
بلکہ خداوند عالم نے اسکی خلقت کے وقت اسکی جو فطرت بنادی ہے وہ اسی کے مطابق آگے قدم بڑھاتا ہے جس کی مزید وضاحت کے لئے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں :
( یابنی آدمَ خذوازینتکم عندکل مسجدٍ،وکلواواشربواولاتُسرفواانّه لا یُحبّ المسرفین ) ( ۱ )
''اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اور ہر مسجد کے پاس زینت ساتھ رکھو اور کھائو پیو مگر اسراف
نہ کرو کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے ''
دوسری آیۂ کریمہ :
( قل من حرّم زینةَ ﷲ التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوافی الحیاةالدنیاخالصةً یومَ القیامةِکذلک نفصّل الآیات لقوم یعلمون٭قل نّما حرّم ربّیَ الفواحشَ ماظهرَمنها ومابطنَ وال ثمَ والبغیَ بغیرالحقِّ وأن تشرکوا باللّهِ مالم یُنزّل به سلطاناً وأن تقولواعلیٰ ﷲ مالا تعلمون ) ( ۲ )
''پیغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کردیا ۔اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں ہم اسی طرح صاحبان علم کے لئے مفصل آیات بیان کرتے ہیں۔کہہ دیجئے کہ ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام کیا ہے چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی اور گناہ اور ناحق ظلم اور بلا دلیل کسی چیز کو خدا کا شریک بنانے اور بلاجانے بوجھے کسی بات کو خدا کی طرف منسوب کرنے کو حرام قرار دیا ہے ''
مختصر یہ کہ یہ آیۂ کریمہ:
( یابنی آدم خذوا زینتکم عندکل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا )
ہر انسان کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے خوب فائدہ اٹھائے بس شرط یہ
____________________
(۱)سورئہ اعراف آیت ۳۱۔
(۲)سورئہ اعراف آیت ۳۲۔۳۳۔
ہے کہ اسراف نہ کرے۔ اسکے بعد دوسری آیت میں ان لوگوں کی مذمت ہے جنھوں نے خداوند عالم کی حلا ل کردہ پا ک و پاکیزہ چیزوں کو حرام (ممنوع)کردیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے :
( قل من حرّم زینة ﷲ التی أخرج لعباده والطیباتِ من الرزق )
آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ دنیا اور اسکی تمام نعمتیں اور سہولتیں در اصل مومنین کے لئے ہیں لیکن غیر مومنین کو بھی ان سے استفادہ کی اجازت دیدی گئی ہے لیکن آخرت کی تمام نعمتیں صرف اور صرف مومنین کے لئے ہیں ۔جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
( قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصةً یوم القیامة )
آیت نے یہ وضاحت بھی کردی ہے کہ خداوند عالم نے صرف اس دنیا کی پوشیدہ اور آشکار تمام برائیوںاور گناہوں سے منع کیا ہے اور اسکے علاوہ ہر چیز جائزقراردی ہے ۔
لہٰذاا سلام ،دنیا سے قطع تعلق کرنے والے نظریات کوٹھکراکر خداکی حلال اور پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندور ہونے کا حکم دیتا ہے اور جن لوگوں نے دنیا سے اپنا ناطہ توڑکر خدا کی حلال کردہ اور پاکیزہ روزی کو حرام کررکھا ہے ان کے اس عمل کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ﷲکی انہیں پاک وپاکیزہ نعمتوں میں سے ایک نعمت امتحان و آزمائش بھی ہے ۔جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے ۔اسکے باوجود خداوند عالم کی طرف سے یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرلیں اور یا ان سے بالکل دور ہوجائیں بلکہ حکم الٰہی تو یہ ہے کہ صرف برائیوں سے محفوظ رہیں اور حدودالٰہی سے آگے قدم نہ بڑھائیں۔
چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک بار ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا:
(أللهم انّی أعوذ بک من الفتنة )
''بارالٰہا میں فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں''
اس جگہ حضرت علی بھی موجود تھے جب آپ نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو فرمایا مجھے محسوس ہورہا ہے کہ تم اپنی اولاداور مال سے بھی خدا کی پناہ مانگ رہے ہو کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :
(نما أموالکم وأولادکم فتنة )
''بیشک تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہیں''
لہٰذا یہ نہ کہو کہ میں فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں بلکہ اس طرح کہا کرو۔
(أللهم انّی أعوذبک من مضلاّت الفتن )( ۱ )
''بارالٰہامیں گمراہ کن فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں''
مولائے کائنات کا یہ ارشاد گرامی ہے :
(لایقولَنَّ أحدکم:اللهم انّی أعوذبک من الفتنة،لأنه لیس أحد الاّٰ و هو مشتمل علیٰ فتنة،ولکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن،فان ﷲ سبحانه یقول: ( واعلموا أنّما أموالکم وأولادکم فتنة ) ( ۲ )
'' تم یہ ہرگز نہ کہو ! بارالٰہا میں فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ تمہارے درمیان کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جسکا دار ومدار فتنہ پرنہ ہو لہٰذا جس کو خدا سے پناہ چاہئے وہ گمراہ کن فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے ''کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے :
''یاد رکھو!بیشک تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہیں''
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہشات کو قابو میں رکھنے اور کنٹرول کرنے کے بارے میں اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے ؟اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے اس کے ذریعہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک جدیدنظریہ اور نظام تربیت پیش کیا ہے اور اس نظریہ کو عصمتوں کا نظام کہا جاتا ہے ۔
____________________
(۱)بحار الانوار ج۹۳ص۲۳۵۔
(۲)سورئہ انفال آیت ۲۸۔
کیونکہ عصمتوں (بچانے والی خصلتوں)کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بجلی یا آگ کا کام کرتے وقت ہم دستانے یا واٹرپروف کپڑے پہن لیتے ہیں اور کسی خطرے کے بغیر بڑی آسانی سے اسکا ہر کام کرلیتے ہیں اسی طرح اگر انسان چاہے توعصمتوں کے سہارے دنیا کی رنگینیوں اور فتنوں کے درمیان بڑی آسانی سے زندگی گذار سکتا ہے اور ان کی موجودگی میں اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا ۔ لہٰذا جس طرح صرف آگ کی حرارت یا بجلی کے کرنٹ کے خطرات کی بناء پر ان کا استعمال ترک کردینا صحیح نہیں ہے اور دوسروں کو اس سے منع کرنا بھی غلط ہے کیونکہ دستانے اور واٹر پروف لباس وغیرہ کے سہارے ان سے ہر کام لیا جاسکتا ہے ۔اسی طرح لوگوں کو دنیا کی آزمائشوں سے دور رکھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے مال واولاد بھی ایک قسم کی آزمائش اور فتنہ ہیں لہٰذا ہر شخص کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ان گمراہ کن اور آزمائش طلب مقامات پر ان عصمتوںسے اچھی طرح استفادہ کرے جو اسے ان سے محفوظ رکھیں ۔کیونکہ اگر یہ عصمتیں کسی کی ذاتی یا سماجی زندگی میں تکامل کی منزل تک پہنچ جائیں تو پھر انسان اپنی خواہشات اور ہوی وہوس کا مختار کل بن جاتا ہے جس کی طرف روایت میں صریحاً اشارہ موجود ہے کہ دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کی خواہش اور ہوی وہوس ان پر غالب ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خواہشات پر ان کا مکمل کنٹرول ہے لہٰذا کیونکہ خواہشات پر کنٹرول کرنا ممکن ہے اسی لئے اسلام میںدنیا کے راحت و آرام سے منع نہیں کیا گیا ہے البتہ اتنا ضروری ہے کہ جسے دنیا سے دل چسپی ہے وہ خواہشات اور ہوی و ہوس پر مکمل کنٹرول کرلے اسکے بعد چاہے جس نعمت دنیا کو استعمال کرے ،ہدایت اور ہوائے نفس کے درمیان یہی معیار اور حد فاصل ہے ۔
امام جعفر صادق :(منملک نفسه اذا غضب،واذا رهب،واذا اشتهیٰ،حرّم ﷲجسده علیٰ النار )( ۱ ) ''جو شخص غصہ،خوف اور خواہشات ابھر نے کی حالت میں اپنے نفس کو
____________________
(۱)بحارالانوارج۷۸ص۲۴۳۔
قابو میں رکھے گاخداوندعالم اسکے جسم کو جہنم پر حرام کردیگا''
(منملک نفسه اذا رغب،واذا رهب،واذا اشتهیٰ،واذا غضب،واذا رضی حرّم ﷲجسده علیٰ النار )( ۱ )
''جو شخص رغبت،خوف اور خواہشات ابھرنے اورغصہ یا خوشی کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے خداوندعالم اسکے جسم کو جہنم پر حرام کردیگا''
عصمتوں کی قسمیں
ہر انسان کے اندر تین طرح کی عصمتیں پائی جاتی ہیں:
۱۔کچھ عصمتیں ایسی ہیں جن کو خداوند عالم نے انسانی فطرت کی تکوینی خلقت اور تربیت کی گہرائیوں میں ودیعت فرمایا ہے جیسے حیا، عفت اوررحم دلی وغیرہ۔۔۔یہی وجہ ہے کہ انسان اور حیوان دونوں کے اندریکساں طور پر جنسی خواہشات موجود ہیں البتہ ان کے درمیان اتنا فرق ضرورہے کہ حیوانوں میں یہ جذبہ بالکل ہی واضح اورظاہرہے جبکہ انسان کے اس جذبہ کے اوپر حیاء وعفت کے پردے پڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ حیوانوں کو اسکی تسکین میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن انسان کو اسکی تسکین سے بہت ساری جگہوں پرپرہیز کر ناپڑتاہے ۔ظاہرہے کہ یہ انسان کی جنسی کمزوری کی بناء پر نہیںہے ۔ بلکہ حیاء وشرم وعفت جیسی عصمتیں اسکے لئے مانع ہوجاتی ہیں کیونکہ یہ جنسی خواہش کو متعادل،لطیف اور کمزوربنادیتی ہیں اور اس پر روک لگاکر اسے مختلف طریقوں سے ابھرنے نہیں دیتیں۔
اسی طرح جذبۂ رحمت(رحم دلی)سے کافی حد تک انسان کا غصہ ٹھنڈا ہوجاتا ہے یہی وجہ
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۱ص۳۵۸
ہے کہ اگرچہ انسان اور حیوان دونوں کے اندر ہی غصہ کا مادہ پایا جاتا ہے مگر حیوان کے اندر اسکے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی لیکن انسان کے یہاں اسکے اوپر رحمت (رحم دلی)کا سائبان ہے جس سے وہ بآسانی معتدل ہوجاتا ہے۔
۲۔کچھ عصمتیں وہ ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی صلاحیت اور محنت سے حاصل کرتا ہے اور ہر انسان کی زندگی میں اسکی تربیت ان عصمتوں کے حصول میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ۔جیسے ذکر الٰہی ، نماز ،روزہ ،تقویٰ وغیرہ ۔۔۔کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے ،ذکر الٰہی سے شیطان دور ہوجاتا ہے روزہ جہنم کی سپر ہے۔اور تقویٰ ایسا لباس ہے جو انسان کو گناہوں اور برائیوں کے مہلک ڈنک سے محفوظ رکھتا ہے۔اسی لئے قرآن مجید میں ارشاد ہے:
( ولباس التقوی ذٰلک خیر ) ( ۱ )
''لیکن تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے ''
۳۔عصمتوں کی تیسری قسم وہ ہے جسے خداوند عالم نے انسان کی معاشرتی زندگی میں ودیعت کیا ہے جیسے دیندار سماج اور معاشرہ یاشادی بیاہ وغیرہ ۔۔۔کیونکہ دیندار سماج اور معاشرہ بھی انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔اور شادی (شوہر اور زوجہ )دونوں کو بے شمار برائیوں سے بچالیتی ہے۔
فی الحال ہم آپ کے سامنے نفس کے اندر اللہ کی ودیعت کردہ ان عصمتوں کے دو نمونوں (خوف وحیا)کی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔
خوف الٰہی
خداوند عالم نے انسان کے اندر جو عصمتیں ودیعت فرمائی ہیں ان کے درمیان خوف الٰہی
____________________
(۱)سورئہ اعراف آیت ۲۶۔
سب سے اہم اور بڑی عصمت ہے جس کو حدیث میں عقل کاایک لشکر قرار دیا گیا ہے اوریہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کاسب سے بہترین ذریعہ ہے ۔
جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:
( وأ مّا من خاف مقام ربّه ونهیٰ النفس عن الهویٰ فانّ الجنة هی المأویٰ ) ( ۱ )
''اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکاجنت اسکا ٹھکانا اور مرکز ہے''
اس آیۂ کریمہ سے بالکل صاف روشن ہے کہ خوف الٰہی اورنفس کو خواہشات سے روکنے کے درمیان ایک قریبی رابطہ پایا جاتا ہے۔
اسی آیت کے بارے میں امام صادق سے روایت ہے کہ:
(من علم أن ﷲ یراه ویسمع مایقول،ویعلم مایعمله من خیر أو شر، فیحجزه ذ لک عن القبیح،فذلک الذی خاف مقام ربّه،ونهیٰ النفس عن الهویٰ )( ۲ )
''یعنی جسے یہ علم ہوجائے کہ خداوند عالم اسے دیکھ رہا ہے اور اسکی ہر بات سنتا ہے اور اسکے ہر اچھے یا برے عمل پر اسکی نظر ہے تو یہی خیال اسکو برائی سے روک دیگا اور اسی انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے خوفزدہ ہوگیا اور اس نے اپنے نفس کو اپنی ہوس(خواہشات ) سے باز رکھا''
امیر المومنین :
(الخوف سجن النفس من الذنوب،ورادعها عن المعاصی )( ۳ )
____________________
(۱)سورئہ نازعات آیت۴۰،۴۱۔
(۲)اصول کافی ج۲ص۷۱۔
(۳)میزان الحکمت ج۳ص۱۸۳۔
''خوف الٰہی انسان کے نفس کو گناہوں اور برائیوں سے بچانے والا حصار ہے''
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :
سبعةیظلّهم الله یو م لاظل الاظله،الامام العادل،وشاب نشأ بعبادةاللّٰ ہ
عزوجل،ورجل قلبه معلّق فی المساجد ،ورجلان تحابّا فی اللّٰه عزوجل اجتمعا علیه وتفرقاعلیه،ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتی لاتعلم شماله ماتنفق یمینه، ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه،ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انّی أخاف ﷲعزّوجل )( ۱ )
'' سات افرادکے اوپر اس دن رحمت الٰہی سایہ فگن ہوگی جس دن اسکے علاوہ اور کوئی سایہ موجود نہ رہے گا:۱۔امام عادل۔۲۔وہ جوان جسکی نشو و نماعبادت الٰہی میں ہوئی ہو۔۳۔جسکا دل مسجدوں سے وابستہ ہو۔ ۴۔خداوند عالم کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جو اسی کے نام پر جمع ہوں اور اسکی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوجائیں(یعنی ان کی ہر محبت اور دشمنی خدا کے لئے ہو) ۔۵۔جوشخص اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اگر ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔۶۔جو گوشۂ تنہائی میں ذکر الٰہی کرے اور اسکی آنکھ سے آنسو نکل آئیں۔۷۔وہ مرد جسے کوئی حسین وجمیل اور صاحب منصب عورت اپنی طرف دعوت دے اور وہ اس سے یہ کہدے کہ مجھے خدا سے ڈرلگتا ہے''۔
گویا خوف الٰہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اسکی سب سے خطرناک خواہش اور ہوس یعنی جنسی جذبہ سے بھی روک دیتی ہے اور انسان گناہوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے
حضرت علی :
(العجب ممن یخاف العقاب فلم یکف،ورجیٰ الثواب
____________________
(۱)صحیح بخاری بحث وجوب نماز جماعت باب ۸،بحث وجوب زکات باب ۱۸کتاب رقاق باب ۲۳ کتاب محاربین باب ۴ ،صحیح مسلم در کتاب زکات باب ۳۰ اور ابوالفرج نے بھی اپنی کتاب ذم الہوی میں ص۲۴۳پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔
فلم یتب ویعمل )( ۱ )
''اس شخص پر حیرت ہے جسے سزا کا خوف ہومگر پھر بھی برائی سے نہ رکے اور ثواب کی امید رکھتا ہو اوراسکے باوجودتوبہ کرکے نیک عمل انجام نہ دے ''
امام محمد باقر :
(لاخوف کخوف حاجز ولارجاء کرجاء معین )( ۲ )
''برائیوں سے روکنے والے خوف سے بہتر کوئی خوف نہیں اور نیکیوں میں معاون ثابت ہونے والی امید سے بہتر کوئی امید نہیں ہے ''
مولائے کائنات :
(نعم الحاجزمن المعاصی الخوف )( ۳ )
''برائیوں سے روکنے والی سب سے بہترین چیز کانا م خوف ہے''
خوف ایک پناہ گاہ
یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو خوف اورڈر،اضطراب سے پیدا ہوتا ہے اسی خوف سے اضطراب پیدا ہوجاتا ہے اوراگرچہ یہ امن وامان کے مقابل میں بولا جاتا ہے مگراس کو اسلام نے انسان کے لئے امان اور ڈھال بنادیا ہے ۔کیونکہ خوف ،انسان کو گناہوں اور برائیوں سے نہیں روکتا بلکہ در حقیقت یہ اسے ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی ڈھال کا نام ہے۔یہی وجہ ہے کہ جس خوف
____________________
(۱)بحارالانوارج۷۷ص۲۳۷۔
(۲)بحارالانوار ج ۷۸ص۱۶۴۔
(۳)میزان الحکمت ج۳ص۱۸۳۔
کوانسان پہلی نظر میں خطرناک محسوس کرتا ہے وہی خوف انسان کی زندگی کو امن وامان عطا کرنے والی ایک نعمت ہے ۔
اسی بارے میں حضرت علی کا ارشاد ہے :
۱۔(الخوف امان )( ۱ )
''خوف ایک امان ہے''
۲۔(ثمرة الخوف الامان )( ۲ )
''خوف کا پھل امان ہے''
۳۔(خف ربک وارج رحمته، یؤ منک مماتخاف،وینلک مارجوت )( ۳ )
''خدا سے ڈرتے رہو اور اسکی رحمت کی امید رکھو تو جس سے بھی تم خوفزدہ ہو گے وہ تمہیں اس سے بچائے رکھے گا اور جس کی امید ہے وہ تمہیں حاصل ہوجائے گا''
(لاینبغی للعاقل ان یقیم علی الخوف اذا وجد الی الأمن سبیلا )( ۴ )
''کسی صاحب عقل وخرد کے لئے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ امن وامان کا راستہ مل جانے کے بعد خوف کی منزل میں پڑا رہے''
روایا ت میں جس خوف کا تذکرہ ہے اس سے مرادعذاب الٰہی سے امان ہے،اور امان سے مراد ،عذاب خداکا خوف ہے اور یہ اسلامی تہذیب و تمدن کے ایک متقابل اور حسین معنی ہیں ۔جس کا
____________________
(۱)میزان الحکمت ج۳ص۱۸۶۔
(۲)گذشتہ حوالہ۔
(۳)گذشتہ حوالہ۔
(۴)گذشتہ حوالہ۔
مطلب یہ ہے کہ دنیا کا خوف آخرت کے لئے امن وامان ہے اور دنیا کا امن وامان اور بے فکری آخرت میں خوف بن جائے گا۔
امیر المومنین نے یہ مفہوم پیغمبر اسلام کے کبھی خشک نہ رہنے والے چشمۂ فیاض سے اخذفرمایا ہے جیسا کہ رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے روایت ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے :
(وعزتی وجلالی لاأجمع علی عبدی خوفین ولاأجمع له امنین،فاذاامننی فی الدنیااخفته یوم القیامة،واذاخافنی فی الدنیاآمنته یوم القیامة)(۱)
''میری عزت وجلالت کی قسم میںاپنے کسی بندے کو دو خوف یا دو امان (ایک ساتھ)نہ دونگا پس اگر وہ دنیا میں مجھ سے امان میں رہا تو قیامت میں اسے خوف میں مبتلا کردونگا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے خوفزدہ رہا تو آخرت میں اسے امن وامان عطا کردونگا''
____________________
(۱)کنز العمال ،متقی ھندی حدیث ۵۸۷۸۔
چند واقعات
ہر انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچانے میں خوف الٰہی کیا کردار ادا کرتاہے؟ اسکی مزید وضاحت کے لئے ہم چند واقعات پیش کر رہے ہیں جن میں سے بعض واقعات روایات میں بھی موجود ہیں۔
۱۔ابن جوزی کا بیان ہے کہ مجھ سے عثمان بن عا مرتیمی نے بیان کیا ہے کہ ان سے ابو عمر یحیی بن عاص تیمی نے بیان کیا تھا کہ :''حی''نامی ایک جگہ کا ایک آدمی حج کے لئے گھر سے نکلا ایک رات پانی کے ایک چشمہ پر اس نے ایک عورت کو دیکھا جسکے بال اسکے کاندھوںپربکھرے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف سے اپنا منھ پھیر لیا تو اس نے کہا کہ تم نے میری طرف سے منھ کیوں پھرلیا؟میں نے جواب دیا کہ مجھے خداوند عالم سے ڈرلگتا ہے ۔چنانچہ اس نے اپنا آنچل سر پر ڈال کر کہا:تم بہت جلدی خوف زدہ ہوگئے جبکہ تم سے زیادہ تو اسے ڈرنا چاہئیے جو تم سے گناہ کا خواہشمند ہے ۔
پھر جب وہ وہاں سے واپس پلٹی تو میں اسکے پیچھے پیچھے ہولیا اور وہ عرب دیہاتیوںکے کسی خیمے میں چلی گئی چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں اپنی قوم کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس جوان لڑکی کا حسن وجمال اور چال ڈھال ایسی تھی:تو وہیں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا وہ فوراًبول پڑا خدا کی قسم وہ میری بیٹی ہے۔میں نے کہا کیا آپ اس سے میری شادی کرسکتے ہیں؟اس نے جواب دیا اگرتم اسکے کفوہوئے توضرور کردونگا۔میںنے کہا: خداکا ایک مرد ہوں اس نے کہا نجیب کفوہے چنانچہ وہاں سے چلنے سے پہلے ہی میں نے اس سے شادی کرلی اور ان سے یہ کہدیا کہ جب میں حج سے واپس پلٹوں گا تو اسے میرے ساتھ رخصت کردینا چنانچہ جب میں حج سے واپس پلٹاتو اسے بھی اپنے ساتھ کوفہ لے آیا اور اب وہ میرے ساتھ رہتی ہے اور اس سے میرے چند بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔( ۱ )
۲۔مکہ میں ایک حسین وجمیل عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس نے ایک دن آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر اپنے حسن وجمال کی تعریف کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا ،ذرا بتائے آپ کی نظر میں کیا کوئی ایسا ہے جو اس حسن وجمال کو دیکھ کر نہ بہکنے پائے؟
____________________
(۱)ذم الہوی لا بن جوزی ص۲۶۴۔۲۶۵۔
شوہر نے کہا ہاں کیوں نہیں، پوچھا کون ہے؟جواب دیا عبید بن عمیر، عورت نے کہا: اگر تم مجھے اجازت دوتو میں آج اسے بہکاکردکھائووں گی؟ کہا :جائو تمہیں اجازت ہے۔چنانچہ وہ گھر سے نکلی اور مسئلہ پوچھنے کے بہانے اسکے پاس پہونچی اس نے اسے مسجد الحرام کے اندر تنہائی میں ملنے کا موقع دے دیا ،تو اس نے اسکے سامنے چاند کی طرح چمکتے ہوئے اپنے چہرہ سے نقاب الٹ دی، تو اس
نے کہا: اے کنیز خدا ،عورت بولی: میں آپ کے اوپر فریفتہ ہوگئی ہوں لہٰذااس معاملہ میں آ پ کی رائے کیا ہے؟اس نے کہا میں تم سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں اگر تم نے میری تصدیق کردی تو میں تمھیں اپنی رائے بتادوں گا، وہ بولی جو کچھ تم پوچھوگے میں سچ سچ جواب دوںگی۔ کہا:ذرا یہ بتائو اگر ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لئے آئیں تو اس وقت تمہیں اچھا لگے گا کہ میں تمہاری یہ تمنا پوری کردوں؟وہ بولی بخدا ہرگز نہیں۔کہا :تم نے سچ کہا ہے۔پوچھا اگر تمہیں تمہاری قبر میں اتار دیا جائے اور سوال کرنے کے لئے بٹھایا جائے تو اس وقت تمہیں اچھا معلوم ہوگا کہ میں تمہاری یہ تمنا پوری کردوں؟وہ بولی بخدا نہیں،کہا تم نے سچ جواب دیا۔پھر پوچھا یہ بتائوکہ جب روز قیامت تمام لوگوں کے ہاتھ میں نامۂ اعمال دئے جا رہے ہوں گے اور تم کو یہ معلوم نہ رہے کہ تمہارا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں(یعنی نامۂ عمل خراب ہے یا اچھا)اس وقت کیا تم یہ پسند کروگی کہ میں تمہاری یہ حاجت پوری کردوں؟بولی بخدا نہیں۔پھر سوال کیا بتائو جب سب کو میزان کے اوپر کھڑاکیا جارہا ہوگا اور تمھیں یہ معلوم نہ ہو کہ تمہارا نامۂ عمل وزنی ہے یا ہلکا تو کیا تمہیں اس وقت خوشی ہوگی کہ میں تمہاری یہ تمنا پوری کردوں؟بولی بخدا نہیں۔کہا تم نے صحیح جواب دیا۔پھر پوچھا اگر تمھیں سوال اور جواب کے لئے خدا کے سامنے کھڑا کیا جائے اورمیں تمہاری یہ تمنا پوری کردوں توکیا اس وقت تم کو اچھا لگے گا؟بولی بخدا نہیں۔کہا تم نے سچ کہا ہے، تواس نے کہا: اے کنیز خدا ،ذرا خدا سے ڈرو اس نے تم کویہ نعمت دے کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے یہ سن کر وہ اپنے گھر واپس آگئی شوہر نے پوچھا کہو کیا کرکے آئی ہو؟وہ بولی تم فضول ہو اور ہم سب کے سب فضول ہیں اور اسکے بعد وہ مستقل نماز ، روزہ اور عبادت میں مشغول ہوگئی وہ کہتا ہے کہ اسکا شوہر یہ کہتا رہتا تھا کہ بتائو عبید بن عمیر سے میری کیا دشمنی تھی ؟
جس نے میری بیوی کو برباد کردیا وہ کل تک تو ایک بیوی کی طرح تھی اوراب اس نے اسے راہبہ بناڈالا۔( ۱ )
۳۔ابو سعد بن ابی امامہ نے روایت کی ہے ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا تھا ،اور وہ بھی اسے چاہنے لگی ایک دن یہ دونوں کسی جگہ ایک دوسرے سے ملے تو عورت نے اسے اپنی طرف دعوت دی ، اس نے جواب دیا :میری موت میرے قبضہ میں نہیں ہے اور تمہاری موت بھی تمہارے بس سے باہر ہے ایسا نہ ہو کہ ابھی موت آجائے اور ہم دونوں گناہکار اور مجرم کی صورت میں خداوند عالم کے دربار میں پہونچ جائیں، بولی: تم سچ کہہ رہے ہو، چنانچہ اسی وقت دونوں نے توبہ کرلی اور اسکے بعد دونوں راہ راست پرآگئے۔( ۲ )
۴۔خارجہ بن زید کا بیان ہے کہ بنی سلیمہ کے ایک شخص نے مجھ سے اپنایہ ماجرا بیان کیا ہے کہ میں ایک عورت کا عاشق ہوگیاتھااور جب بھی وہ مسجد سے نکل کر جاتی تھی میں بھی اسکے پیچھے چل دیتا تھا اور اسے بھی میری اس حرکت کا علم ہوگیا۔چنانچہ اس نے ایک رات مجھ سے کہا تمھیں مجھ سے کچھ کا م ہے؟ میں نے کہا ہاں۔بولی: کیا کام ہے؟میں نے جواب دیا تمہاری محبت ۔اس نے کہا کہ اسے گھاٹے والے دن (روز قیامت) پر چھوڑدو، اسکابیان ہے کہ :خداکی قسم اس نے مجھے رلادیا جسکے بعد میں نے پھر یہ حرکت نہ کی۔( ۳ )
۵۔بنی عبد القیس کے ایک بزرگ کی روایت ہے ،وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلہ والوں سے سنا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو اپنی طرف دعوت دی تو وہ بولی تم نے حدیث سنی ہے اور قرآن پڑھا ہے تم پڑھے لکھے ہو،پھر مرد نے عورت سے کہا کہ :محل کے دروازے بند کردو، تو اس نے دروازے بند کردئے مگر جب وہ مرد اسکے نزدیک ہوا تو وہ عورت بولی کہ ابھی ایک دروازہ کھلارہ گیا
____________________
(۱)ذم الہوی لابن جوزی ص۲۶۵۔۲۶۶۔
(۲)ذم الہوی لا بن جوزی ص۲۶۸۔
(۳)ذم الہوی لا بن جوزی ص ۲ ۲۷۔
ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوسکا۔اس نے کہا کون سا دروازہ ؟جو اب دیا:وہ دروازہ جو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان کھلا ہے یہ سن کر اس نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔( ۱ )
۶۔ابن جوزی کا بیان ہے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کے بصرہ کی زاہدہ وعابدہ خاتون ایک مہلّبی مرد( ۲ ) کے چنگل میں پھنس گئی ہے،کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اور جو کوئی اسے شادی کا پیغام دیتا تھاتو وہ منع کردیتی تھی چنانچہ مہلّبی کو یہ خبر ملی کے وہی عورت حج کرنے جاری ہے ،تو اس نے تین سو اونٹ خریدے اور یہ اعلان کردیا کہ جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مجھ سے اونٹ کرائے پرلے سکتا ہے۔چنانچہ اس عورت نے بھی اس سے کرایہ پرایک اونٹ لے لیا۔ایک دن راستہ میں وہ رات کے وقت اسکے پاس آیا اور کہا یاتم مجھ سے شادی کرو، ورنہ !عورت نے جواب دیا :تم پروائے ہو ذرا خدا کا خوف کرو، تو اس نے کہا:ذرا کان کھول کر سنو، خدا کی قسم میں کوئی اونٹوں کاساربان ( اونٹ والا)نہیں ہوں بلکہ میں تو اس کام کے لئے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے نکلا ہوں، لہٰذا جب عورت نے اپنی آبرو خطرے میں دیکھی تو کہا کہ اچھا جائو یہ دیکھو کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں جاگ رہا ہے وہ پھر بولی ایک بار اور دیکھ آئو چنانچہ وہ گیا اور جب واپس پلٹ کرآیا تو کہا: ہاں سب کے سب سوچکے ہیں تو عورت نے کہا: تجھ پروائے ہو،کیا رب العالمین کوبھی نیند آگئی ہے؟( ۳ )
حیاء
عقل کے لشکرکی ایک اور صفت ''حیائ''بھی ہے یہ بھی انسان کو تباہی اور بربادی سے بچانے میں اہم کردار کرتی ہے۔چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگرکسی شخص کو خداوند عالم یا اسکے بندوں کی حیاء نہ ہوتووہ گناہوں میں مبتلا ہوجاتاہے اور اسے اسکی عقل بھی نہیں روک پاتی ہے ۔ایسے حالات میں
____________________
(۱)ذم الہوی لا بن جوزی ص۲۷۴۔
(۲،۳) مہلّب :ایک ثروت مند قبیلہ کا نام ،ذم الہویٰ لا بن جوزی ص۲۷۷۔
صرف حیاء ہی اسکو گناہ سے بچاتی ہے۔
حیاء (چاہے جس مقدار میں ہو اس) کے اندر عصمت کے مختلف درجات پائے جاتے ہیں جیسے اعزاء و اقرباء سے شرم وحیاء میں جو عصمت پائی جاتی ہے وہی غیروں سے حیاء کے وقت ایک درجہ اور بڑھ جاتی ہے اسی طرح انسان جس کا احترام کرتا ہے اور اسکی تعظیم کا قائل ہے اسکے سامنے حیاء کی وجہ سے اسکے اندر اس سے اعلیٰ درجہ کی عصمت پیدا ہوجاتی ہے۔
آخر کار پروردگار عالم سے حیاء کرنے کی وجہ سے انسان عصمت کے سب سے بلند درجہ کا مالک ہوجاتا ہے ۔لہٰذا اگر انسان اپنے نفس کے اندر خداوند عالم کی حیاء پیدا کرلے اور اس کو اچھی طرح اپنے وجود میںراسخ کرلے اور خدااور اسکے فرشتوں کو ہمیشہ اپنے اوپر حاضر وناظر سمجھے تواس احساس کے اندر اتنی اعلیٰ درجہ کی عصمت پائی جاتی ہے جو اس کو ہر طرح کی نافرمانی، گناہ اور لغزشوںسے بچاسکتی ہے۔
ﷲ تعالیٰ سے حیائ
یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کے دل میں خداوند عالم کا خیال موجود ہواور وہ اسے حاضر وناظر بھی سمجھ رہا ہو اور اسے یہ بھی یاد ہو کہ خداوند عالم کے علاوہ اسکے معین کردہ فرشتے بھی اس سے اتنا نزدیک ہیں کہ خداوند عالم نے ان سے اسکا جو عمل پوشیدہ رکھتا ہے اسکے علاوہ اسکا کوئی عمل ان سے پوشیدہ نہیں ہے اورپھر بھی وہ گناہ کا مرتکب ہوجائے چنانچہ پیغمبر اکرم صلی ﷲ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں یہ بھی ہے کہ اے ابوذر خدا وند عالم سے شرم وحیاء کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ ٔ قدرت میں میری جان ہے میرا حال تو یہ ہے کہ جب میں بیت الخلاء کے لئے جاتا ہو ں تو اپنے دونوں فرشتوں سے شرم وحیاء کی بناپر اپنے چہرے پر کپڑاڈال لیتا ہوں۔
حیاء کا وہ ارفع و اعلیٰ درجہ جو خداوند عالم نے اپنے رسول کو عنایت فرمایا ہے وہ دنیا میں بہت کم افراد کو نصیب ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ جب انسان کے نفس کے اندر اور اسکے شعور و ادراک میں اچھی طرح حیائے الٰہی جلوہ فگن ہوجاتی ہے تو پھر اسے گناہوں، برائیوں نیزہوس کے مہلک خطرات کے سامنے سپر انداختہ نہیں ہونے دیتی ہے ۔
جب اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے شرم وحیاء کی بناء پرانسان نہ جانے کتنے ایسے کام نہیں کرتا ہے جنہیں ان کی عدم موجودگی یا تنہائی میں انجام دے لیتا ہے تواگر اسکے اندرخداوند عالم سے حیاء کا مادہ پیدا ہوجائے تو پھر خداوند عالم کی ناپسندیدہ چیزوں سے وہ بدرجۂ اولیٰ پرہیز کریگا اور اسکے لئے ملاء عام (علی الاعلان)اور گوشہ تنہائی میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ اس لئے کہ خداوند عالم ہرجگہ حاضر وناظر ہے ۔اور یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص ،بندوں سے کوئی بات پوشیدہ رکھ لے لیکن خداوندعالم سے اسکی کوئی بات ہرگز پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :
(یاأباذراستح من ﷲ،فأنی والذی نفسی بیده لأظل حین أذهب الیٰ الغائط متقنّعاًبثوبی استحی من المَلکین الذین معی )( ۱ )
''اے ابوذر،خداوند عالم سے حیاء کرو،کیونکہ اس ذات کی قسم جسکے قبضہ میں میری جان ہے میں جب بھی بیت الخلاء کے لئے جاتاہوں تو اپنے ہمراہ دونوں فرشتوںسے شرم وحیاء کی وجہ سے اپنے چہرہ کو ڈھانپ لیتاہوں''
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :
(استحِ من ﷲاستحیاء ک من صالح جیرانک،فان فیهازیادةالیقین )( ۲ )
''خداوند عالم سے اس طرح شرم وحیاء کرو جس طرح تم اپنے نیک اور صالح پڑوسی سے
____________________
(۱) بحارالانوار ج۷۷ص۸۳وکنز العمال ح۵۷۵۱۔
(۲) بحارالانوار ج۷۸ص۲۰۰۔
شرماتے ہو کیونکہاس سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے''
آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے :
(لیستحِ أحدکم من ملکیه الذین معه،کمایستحی من رجلین صالحین من جیرانه،وهمامعه باللیل والنهار )( ۱ )
''اپنے فرشتوں سے تم اسی طرح شرم وحیا کیا کرو جس طرح تم اپنے دو صالح اور نیک پڑوسیوں سے شرماتے ہو کیونکہ یہ فرشتے رات دن تمہارے ساتھ رہتے ہیں''
خداوند عالم سے ہر حال میں شرم وحیا کے بارے میں امام کاظم سے نقل ہوا ہے:
(استحیوا من ﷲ فی سرائرکم،کما تستحون من الناس فی علانیتکم )( ۲ )
''تنہائی میں خداوند عالم سے اسی طرح شرم وحیا کیاکرو جس طرح لوگوں کے سامنے تمھیں حیا آتی ہے''
مختصر یہ کہ اگر کسی کے اندر خداوند عالم سے حیاکا عرفان پیدا ہوجائے تو وہ عصمت کے بلند ترین درجہ پر فائز ہوسکتا ہے اور اسکے لئے ملا ء عام یاگوشۂ تنہائی میں کوئی فرق نہیں ہے اسکے لئے روایات میں مختلف تعبیرات ذکر ہوئی ہیں۔
حضرت علی :
(الحیاء یصدّ عن الفعل القبیح )( ۳ )
''حیا برائیوں سے روک دیتی ہے ''
آپ ہی نے یہ بھی فرمایا ہے:
____________________
(۱)میزان الحکمت ج۲ص۵۶۸۔
(۲)بحارالانوار ج۷۸ص۳۰۹۔
(۳)میزان الحکمت ج۲ص۵۶۴۔
(علیٰ قدرالحیاء تکون العفة )( ۱ )
''حیا کی مقدار کے برابرہی عفت بھی ہوتی ہے''
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :
(استحیوا من ﷲحق الحیائ،فقیل یارسول ﷲ:ومن یستحی من ﷲحق الحیائ؟فقال:من استحییٰ من ﷲحق الحیاء فلیکتب أجله بین عینیه،ولیزهد فی الدنیاوزینتها،ویحفظ الرأس وماحویٰ والبطن وماوعیٰ )
''خداوند عالم سے ایسی حیا کروجو حیا کر نے کا حق ہے سوال کیا گیا خداوند عالم سے حیا کرنے کا جوحق ہے اسکا کیا طریقہ ہوگا؟آپ نے فرمایا کہ جو خداوند عالم سے واقعاً حیا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی موت کو اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے مجسم کرلے (اپنی پیشانی پر لکھ لے )اور دنیا اور اس کی زینتوںسے اجتناب کرے اور اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اور اپنے پیٹ اور جو اسکے اندر بھرا ہے ان سے محفوظ رہے''( ۲ )
امام موسیٰ کاظم :
(رحم ﷲ من استحییٰ من الله حق الحیائ،فحفظ الرأس وماحویٰ،والبطن وماوعیٰ )( ۳ )
''ﷲ تعا لی اس بندے پر رحم کرے جسکو اس سے واقعا حیا آتی ہو اور اسی لئے وہ اپنے سر کے وسوسوں اور پیٹ کی شہوتوں سے اپنے کو محفوظ رکھے''
روایت میں سر اور معدہ کا تذکرہ اس لئے کیا گیا ہے کہ اکثر شہوتیں انہیں دونوں جگہوں سے
____________________
(۱)گذشتہ حوالہ۔
(۲)بحارالانوار ج۷۰ص۳۰۵۔
(۳)بحارالانوار ج۷۰ص۳۰۵۔
جنم لیتی ہیں مثلاًاگر آنکھیں شہوت کا ایک دروزہ اور کان دوسرا دروازہ ہے تومعدہ ( پیٹ ) شہوت کی پیدا ئش کاپہلامرکز اور شرم گاہ دوسرا مرکزہے ۔
لہٰذا جب انسان کے اندر شرم وحیاء پیدا ہوجاتی ہے تو پھر ذہن ودماغ کے برے خیالات (سر کے وسوسے )اور پیٹ کی شہوت کے سارے راستے خود بخود بندہوجاتے ہیں اور انسان ان کے شر سے محفوظ ہوجاتا ہے ۔
آپ ہی سے مروی ہے :
(مِن أفضل الورع أن لاتبدی فی خلواتک ما تستحی من اظهاره فی علانیتک )( ۱ )
''سب سے بڑا ورع اور پارسائی یہ ہے کہ جس کام کو تم کھلم کھلا کرنے سے شرماتے ہو اسے تنہائی میں بھی انجام نہ دو''
بارگاہ خدا میں قلت حیا کی شکایت
متعدد دعائوں میں یہ ملتا ہے کہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اس سے حیاکی قلت کی شکایت کرتا ہے جو ایک بہت ہی لطیف اور عجیب بات ہے کہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ شکایت کرے کہ اسکے اندر خود ذات پروردگار سے شرم وحیاء کی قلت پائی جاتی ہے جس میں خدا قاضی ہے کیونکہ اسکا فیصلہ اسی کے اوپر چھوڑدیاگیا ہے شکایت کرنے والا خود انسان (انا،میں )ہے اور جس کے خلاف شکایت کی گئی ہے وہ نفس ہے اور شکایت (مقدمہ) کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نفس اس خدا کے سامنے بے حیائی پر اتر آیا ہے جو خود اس مقدمہ میں قاضی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے نفس کی یہ شکایت کررہا ہے کہ وہ خود خدا سے حیاء نہیں کرتا ہے بطورنمونہ دعائے
____________________
(۱)غررالحکم ج۲ص۲۵۳۔
ابوحمزہثمالی(رح) کے یہ جملات ملاحظہ فرمائیں:
(أنا یاربّ الذی لم أستحیک فی الخلائ،ولم اُراقبک فی الملأ،أناصاحب الدواهی العظمیٰ،أناالذی علیٰ سیده اجتریٰاناالذی سترت علیّ فمااستحییت،وعملت بالمعاصی فتعدّیت،واسقطتنی من عینیک فما بالیت )( ۱ )
''پروردگارا !میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی اور مجمع میں تیرا خیال نہیںکیا میرے مصائب عظیم ہیں میں نے اپنے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے ۔۔۔میں وہی ہوں ۔۔۔ جس کی تونے پردہ پوشی کی تو میں نے حیا نہیں کی، گناہ کئے ہیں تو بڑھتا ہی چلا گیا اور تو نے نظروں سے گرا دیا تو کوئی پروا نہیں کی ''
امام زین العابدین کی مناجات شاکین(شکایت اور فریاد کرنے والوں کی مناجات ) میں بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے نفس اور گناہوں سے پرہیز نہ کرنے کی شکایت ان الفاظ میں کی گئی ہے:
(الٰهی أشکوالیک نفساًبالسوء أمّارة،والیٰ الخطیئة مبادرة، وبمعا صیک مولعة،ولسختک متعرّضة )( ۲ )
''خدایا میں تجھ سے اس نفس کی شکایت کر رہا ہوں جو برائیوں کا حکم دیتا ہے اور خطائوں کی طرف تیزی سے دوڑ تا ہے اور تیری معصیتوں پر حریص ہے اور تیری ناراضگی کی منزل میں ہے ''۔
____________________
(۱)دعا ئے ابو حمزہ ثمالی۔
(۲)مفاتیح الجنان: مناجات الشاکین ۔
دوسری فصل
جو شخص اپنی ہویٰ وہوس کو خداوند عالم کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے۔
۱۔ہوی وہوس کے معنی
۲۔اسکے خصائل اور صفات
۳۔اسکا طریقہ ٔ علاج
حدیث شریف کے پہلے فقرے کی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کے سامنے اس حدیث کے دوسرے اور تیسرے جملے ''جو شخص خداوند عالم کی مرضی پر اپنی خواہش اور ہوس کو مقدم کرتا ہے'' اور اسکے برخلاف ''جو انسان مرضی خدا کو اپنی مرضی اوراپنی خوشی پرفوقیت اور ترجیح دیتا ہے '' کی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔
جو شخص اپنی ہوس کو خداوند عالم کی مرضی پر فوقیت دیتا ہے۔ اس (دوسرے)جملہ کی وضاحت متعلقہ حدیث قدسی میں کچھ اس طرح کی گئی ہے۔
عن رسول ﷲ یقو ل ﷲ تعالیٰ :
(وعزّتی وجلا لی،وعظمتی،وکبریائی،ونوری،وعلوّی،وارتفاع مکانی لایؤثرعبد هواه علیٰ هوای لّا شتّت أمره،ولبّست علیه دنیاه،وشغلت قلبه بها،ولم اُوته منها لاماقدّرت له)(۱)
____________________
(ا)عدةالداعی ص۷۹۔اصول کافی ج۲ص۲۳۵۔ان دونوںسے علامہ مجلسی (رح)نے بحارالانوار ج۷۰ص۷۸حدیث۱۴ اور ج۷۰ص۸۵نیزص۸۶پر اس حدیث کو نقل کیاہے۔اس سے پہلے بھی ہم نے کتاب کے مقدمہ میں اس حدیث کے بعض حوالے نقل کئے ہیں۔
''میری عزت وجلالت ،عظمت وکبریائی ،نور ورفعت اور میرے مقام ومنزلت کی بلندی کی قسم ،کوئی بندہ بھی اپنی ہویٰ وہوس کو میری مرضی اور خواہش پر ترجیح نہیں دیگا مگر یہ کہ میں اسکے معاملات کودرہم برہم کردونگا اسکے لئے دنیا کو بنا سنوار دونگا اور اسکے دل کو اسی کا دلدادہ بنا دونگا اور اسکو صر ف اسی مقدار میں عطا کرونگاجتنا پہلے سے اسکے مقدر میں لکھ دیا ہے''
حدیث قدسی کے اس فقرہ میں تین اہم نکات پائے جاتے ہیں:
۱۔جو لوگ اپنی خواہش کو مرضی خدا پر ترجیح دینگے انہیں خداوند عالم تین قسم کی سزائیں دیگا:
الف۔ان کے معاملات مشتبہ اوردرہم برہم ہوجائیں گے۔
ب۔ دنیاان کی نگاہ میں آراستہ ہوجائے گی۔
ج۔ان کادل، دنیا کا دیوانہ ہوکر رہ جائے گا۔
۲۔مذکورہ سزائوںکے تذکرہ سے پہلے اس حدیث شریف میں متعدد طرح کی عظیم قسمیں کھائی گئی ہیں(جیسے میری عزت،جلالت،عظمت،کبریائی، نوراور میرے مقام و منزلت کی رفعت کی قسم) جن سے اُس بات کی اہمیت کابخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے جسکا تذکرہ ان کے بعد کیا گیا ہے۔
۳۔حدیث شریف میں جس طرز کلام کا انتخاب کیا گیا ہے اس سے دائرہ کلام بالکل محصور اور محدودہوجاتا ہے کیونکہ پہلے جملہ یعنی (لایؤثرعبدھواہ۔۔۔الاشتت أمرہ) میں نفی اور دوسرے جملہ(الاشتت أمرہ) میں اثبات کا لہجہ موجود ہے لہٰذا اس حصر کے معنی یہ ہیں کہ جب کبھی بھی انسان اپنی ہوس کو خداوند عالم کی مرضی پر ترجیح دیگا تو وہ کسی بھی طرح خداوند عالم کی ان سزائوں سے نہیں بچ سکتا ہے اب آپ حدیث قدسی میں مذکور، ان تینوں سزائوں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں:
۱۔اسکے امور کو درہم برہم کردوںگا
جو لوگ خوداپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور خداوند عالم کی مرضی کاکوئی خیال نہیں کرتے ہیں ان کو خداوند عالم سب سے پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ ان کے معاملات درہم برہم کردیتا ہے اور ان کے ہر کام میں بے ثباتی ،تزلزل اور بے ترتیبی آجاتی ہے کیونکہ وہ ان سے طریقۂ کار، راہ وروش، مقصد اور وسیلہ کی یکسانیت اور یکسوئی کو سلب کرلیتا ہے۔جسکے نتیجہ میں وہ ہوا میں کٹی پتنگ یا کسی تنکے کی طرح ہر طر ف اڑتے رہتے ہیں اور ہوا کا ہر جھونکا انکو ایک نئی سمت کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔کیونکہ لوگ عام طور سے دو طرح کے ہوتے ہیں:
۱۔منظم اور ٹھوس شخصیت کے مالک۔
۲۔بے نظم اوربے ترتیب
ٹھوس شخصیت
ٹھوس اور مستحکم شخصیت ایسی شخصیتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی ایک حاکم کے ماتحت رہتی ہیں جب کہ متزلزل ،مضطرب اور بد حواس قسم کے افراد متعدد اسباب وعوامل کے آلۂ کار بنے رہتے ہیں۔
چنانچہ پہلے طریقۂ کار کو توحیدی طریقہ اور دوسرے طریقہ کوشرک کا نتیجہ کہا جاتاہے کیونکہ جو شخص توحید الٰہی کا نمونہ ہوتا ہے۔وہ ہر اعتبار سے خداوند عالم کے ارادہ ،حکمت اور اسکے احکام کا تابع ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے اسی کی مشیت اور مرضی کے سامنے سرتسلیم خم کئے رہتا ہے۔
اسی طرح ہرخوشی اور مصیبت میں وہ حکم الٰہی کا پابند رہتا ہے اور خداوند عالم کی خو شنودی ہی اسکا اصل مقصد ہے اور اسکے علاوہ اسے کسی دوسری چیز کی خواہش نہیں ہوتی اور وہ ہرطرح سے اس کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کئے رہتا ہے اوراسکی نظر صرف اپنے اس پاک مقصد پر مرکوز رہتی ہے اور وہ اسکی طرف رواں دواں رہتا ہے ۔اور کیونکہ احکام الٰہی کا نظام صرف ایک ہی مرکز سے متصل ہے اور اس میں مکمل طور سے یکسانیت پائی جاتی ہے لہٰذا اس پر عمل کر نے کے بعد ہر انسان کی شخصیت مقدس ہو جا تی ہے اور اس میں یکسوئی پیدا ہو جا تی ہے یعنی کبھی مختلف قسم کی سیاسی یا سما جی ردو بدل اور اتھل پتھل کی وجہ سے جنگ اور لڑائی کی نوبت آجاتی ہے جسکی بناپرانہیں اسلحہ اٹھا نا پڑ تاہے ۔اور کبھی صورتحال یہ ہوجاتی ہے کہ اسلحہ کو زمین پر رکھنا پڑتا ہے مگرحالات کے اس پورے اتار چڑھائو کے باوجود انسان کی شخصیت کے اندر کسی طرح کا اختلاف یا ردو بدل پیدا نہیں ہوتی اور اسکی شخصیت کی یکسا نیت اور توحید کے سرچشمہ سے پیدا ہو نے والی ترتیب ویگانگت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور اسی کو (توحید عملی ) کہا جاتا ہے جو توحید نظری کے مقابلہ میں بولی جاتی ہے کیونکہ یہ صورت حال دراصل انسان کی زندگی میں توحید نظری کے پر توکاہی نتیجہ ہے ۔
توحید عملی کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے نفس کے اندر اور باہر موجودتمام حاکمو ں جیسے ہوی وہو س اور طاغوت وغیرہ کی ماتحتی سے خارج ہو جاتا ہے اور احکام الٰہی کے دائر ہ حکومت میں داخل ہوجاتا ہے اس طرح تنہا حکم الٰہی ہی اسکے ہر عمل کا حاکم ومختار ہوتا ہے اور اسکی رفتار وگفتار اور کردار وعمل میں ہر جگہ توحید ی رنگ نظر آتا ہے اور وہ پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی اس حدیث شریف کا مصداق بن جاتا ہے :
(لایؤمن أحدکم حتیٰ یکون هواه تبعاً لما جئت به )( ۱ )
''تم میں سے کو ئی شخص بھی اس وقت تک مو من نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہر خو ا ہش اس دین کی تا بع نہ بن جا ئے جو میں لیکر آیا ہوں ''
جبکہ شر ک کی صورتحال اس کے برخلاف ہو تی ہے کیونکہ شرک آجا نے کے بعد انسان سوفیصد خدا وند عالم کے احکام کا پا بند نہیں رہتا بلکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ خوا ہش نفس اور طاغوت وغیرہ کی پیروی بھی شروع کر دیتا ہے اور جب انسان تو حید کے قلعہ کی چار دیواری سے با ہر نکل جاتا ہے توپھر ہوس اور طا غوت اس کے سر پر سوار ہو جا تے ہیں اس کی بنیا دوںکو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور گویااسے با لکل تباہ و بر باد کر ڈالتے ہیں اس با رے میں قرآنی تعبیرات ملاحظہ فر ما ئیے :
( ﷲ ولی الذین آمنوا والذین کفرواأولیاؤهم الطاغوت) (۲)
____________________
(۱)جا مع الکبیرطبری ۔
(۲)سورئہ بقرہ آیت ۲۵۷۔
''ﷲ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے ۔۔۔اور جو لوگ کافر ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہیں''
جسکا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مومن ہیں ان کا صرف ایک ولی وسرپرست ہے ایک ذریعہ اور ایک ہی سرچشمہ ہے اور صرف اسی سے ان کو نسبت ہے لیکن مشرکین مختلف لیڈروں اور حاکموں کے آلہ کار اور تابع ہوتے ہیں انہیںجو ذریعہ اور وسیلہ بھی نظر آجاتا ہے وہ اسی کے پیچھے لگ لیتے ہیں اسی لئے ان کے واسطے جمع کا صیغہ استعمال کیاگیا ہے :
( والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت )
''اورجو لوگ کافر ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہیں ''(اس میں لفظ اولیاء جمع ہے )
یہاں تک یہ بالکل واضح ہوگیا کہ جو شخص ،ٹھوس شخصیت کا مالک ہوتا ہے اس پر صرف شرعی قانون کی حکومت چلتی ہے اور وہ مرضی خدا کا پابند ہوتا ہے ایسے افراد کسی غوروفکر ،شرم وحیا اور خوف وہراس کے بغیر اپنی شرعی ذمہ داریوںپر عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ خوف وہراس ،شرمندگی اور اضطرابی حالت انسان کی اندرونی کشمکش اور تذبذب کی دلیل ہے جو نفس کے اندرونی یا بیرونی اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لہٰذا جب انسان کسی ایک طاقت کا پابنداور پیرو ہوتا ہے اور اسکی نظر ہمیشہ ایک ہی مرکز پر رہتی ہے تو اس پر ان چیزوں کا اثرنہیں پڑتا ہے ۔
ایسے افراد کی پہچان یہ ہے کہ وہ ثقہ، قابل اطمینان، ثابت قدم ،ٹھوس رائے ،پاکیزہ نفس صاف وشفاف ضمیر کے مالک ،شجاع اورتنہائی یا چاہنے والوں اور مددگاروں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود اپنے موقف پر اٹل رہتے ہیں ۔امیر المومنین نے فرمایا ہے :
(لایزیدنی کثرة الناس عزّة،ولاتفرُّقهم عنی وحشة )( ۱ )
____________________
(۱)نہج البلاغہ مکتوب۳۶۔
''لوگوں کی کثرت سے نہ میری عزت اوراستحکام میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ان کے متفرق ہوجانے سے مجھے کوئی وحشت ہوتی ہے ''دوسرے یہ کہ ان لوگوں کے ان خصائل اور صفات پر وقتی سکون واطمینان ،زحمت ومشکلات رزم وبزم ،فتح ونصرت یا ناکامی اورشکست کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور وہ پرچم توحید کے سایہ میں سدا بہار رہتے ہیں ۔
عماربن یاسر
خداوند عالم جناب عمار یاسر پر رحمتیں نازل فرمائے وہ ایک مثالی ،ٹھوس اور عظیم شخصیت کے مالک تھے ۔جنگ صفین میں آپ نے حضرت علی کی رکاب میں اس وقت معاویہ سے جنگ کی تھی جب آپ کی عمر ،نوے برس سے زیادہ تھی آپ نڈر،بہادر،ثابت قدم، جنگ کے شعلوں میں کودجانے والے اورامام کے ایسے جانثار ساتھی تھے جن کے دل میں حضرت علی کی حقانیت اور معاویہ کے ناحق اور باطل ہونے کے بارے میں ایک لمحہ کے لئے بھی شک پیدا نہیں ہوا۔
یہی وجہ ہے کہ صفین کی جنگ کے دوران ہی حضرت علی کے سامنے آپ نے پروردگار عالم سے یہ دعا کی:
(اللّٰهم انکتعلم أنی لوأعلم أن رضاک فی أن اقذف بنفسی فی هذاالبحرلفعلت،اللّٰهم انک تعلم أنی لوأعلم انّ رضاک أن أضع ضُبّةسیفی فی بطنی ثم أنحنی علیها حتیٰ یخرج من ظهری لفعلت،اللّٰهم وانی أعلم مماعلّمتنی أنی لاأعمل الیوم عملاًهو أرضیلک من جهاد هؤلاء الفاسقین،ولوأعلم الیوم عملاً أرضیٰلک منه لفعلت )( ۱ )
____________________
(۱)صفین:نصربن مزاحم ۳۱۹۔۳۲۰تحقیق ڈاکٹر عبدالسلام ہارون۔
''بارالٰہاتوجانتاہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ اس سمندر میں کودجانے میں تیری خوشنودی ہے تو میں یقینا کودجائوں گا۔بارالٰہا تو جانتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوجائے کہ تیری خوشی اس میں ہے کہ میں اپنی تلوار اپنے پیٹ پر رکھکر اس کے اوپر اتنا جھک جائوں کہ وہ میری کمر کے پار نکل جائے تو میں یہ کرنے کے لئے تیار ہوں ۔۔۔بارالٰہا تونے مجھے جو علم دیا ہے اسکی بنا پر مجھے معلوم ہے کہ آج تجھے ان فاسقین سے جہاد کرنے سے زیادہ میرا کوئی عمل پسند نہیں ہے (لہٰذا میں ان سے جہاد کررہا ہوں)اور اگر مجھے اس سے زیادہ تیراپسندیدہ عمل معلوم ہوجائے تو میں اسکو ضرورانجام دونگا''
اسماء بن حکم فزاری کا بیان ہے کہ ہم صفین کے میدان میں حضرت علی کے لشکر میں جناب
عمار یاسر کی سپہ سالاری میں دو پہر کے وقت سرخ چادر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے ۔اس وقت ایک شخص(جو سب کے چہرے غورسے دیکھ رہاتھا)آیا اور اس نے کہا کیا تمہارے درمیان عمار یاسر ہیں ؟
جناب عمار نے کہا :میں عمار ہوں ۔
اس نے کہا! ابوالیقظان؟
جواب دیا :جی ہاں۔
پھر اس نے کہا :کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے ،فرمائیے یہیں سب کے سامنے عرض کروں یا تنہائی میں،جناب عمار بولے جو تم چاہو۔اس نے کہا ٹھیک ہے سب کے سامنے ہی عرض کئے دیتا ہوںجناب عمار نے کہا بتائو کیا کام ہے ؟
کہا! میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا تو مجھے اپنی حقانیت اور اس قوم(لشکر معاویہ)کی گمراہی کے بارے میں کوئی شک و شبہہ نہیں تھااور مسلسل میری یہی کیفیت تھی مگر آج رات عجیب اتفاق ہوا کہ جب صبح ہوئی تو ہمارے مؤذن نے(اشهد أن لاالٰهَ الاﷲ وأن محمداًرسول ﷲ )کی صدا بلند کی اور ان کے موذن نے بھی اسی طرح اذان دی جب نماز شروع ہوئی تو ہم سب نے ایک ہی طرح نماز پڑھی ایک ہی طرح دعا کی،ایک ہی کتاب (قرآن مجید )کی تلاوت کی اور ہمارے رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم بھی ایک ہیں، یہیں سے میرے دل میں کچھ شک پیدا ہوا ۔چنانچہ خداہی بہتر جانتا ہے کہ میں نے بقیہ وقت کیسے گذارا ہے، صبح ہوئی تو میں امیر المومنین کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں پورا ماجرا بیان کردیا تو انھوں نے فرمایا :کیا تم عمار بن یاسر سے ملے ہو؟میں نے عرض کی نہیں، فرمایا جائو ان سے ملاقات کرو اور جو کچھ وہ کہیں اس پر عمل کرنا ۔
لہٰذا اسی کام کے لئے میں آپ کی خدمت حاضر ہوا ہوں تو جناب عمار یاسر(رح) نے اس سے کہا: کیا تم ہمارے مقابلہ میں موجود اس سیاہ پرچم والے لشکر کے سپہ سالار کوجانتے ہو؟وہ عمروبن عاص ہے، رسول ﷲصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ساتھ رہ کر میں نے اس سے تین بارجنگ کی ہے اور آج اس سے یہ میری چوتھی جنگ ہے ۔اور یہ جنگ ان جنگوں سے کچھ بہتر نہیں ہے بلکہ بدتر ہی ہے بلکہ اس کا شروفساد ان سب سے زیادہ ہے ،کیا تم بدر واحد اور حنین میں تھے یا تمہارے والد ان میں موجود تھے کہ انھوں نے تم سے ان جنگوں کے کچھ حالات بتائے ہوں؟اس نے کہا نہیں آپ نے کہا کے بدرواحد وحنین کے دن ہم سب رسول ﷲکے پرچم تلے جمع تھے اور وہ لوگ، مشرکین کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا تھے۔کیا تم اس لشکر اوراہل لشکرکو دیکھ رہے؟خدا کی قسم ! معاویہ کے ساتھ یہ جتنے لوگ حضرت علی کے مقابلہ میںہم سے لڑنے آئے ہیں ۔ یہ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور میرادل تویہ چاہتا ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کرڈالوں۔
خدا کی قسم ان سب کا خون ایک چڑیا کے خون سے زیادہ حلال ہے ۔کیا تم چڑیا کا خون بہانا حرام سمجھتے ہو؟اس نے کہا :نہیں بلکہ حلال ہے تو جناب عمار نے کہا بس سمجھ لو کہ ان کا خون بھی اسی طرح حلال ہے ۔کیا میری بات تمہارے لئے واضح ہوگئی؟اس نے کہا :جی ہاں آپ نے درست وضاحت فرمائی جناب عمار نے کہا: لہٰذا اب جسے چاہومنتخب کرسکتے ہوپھرجب وہ شخص واپس چلنے لگا تو جناب عمار نے اسے واپس بلایا اور اس سے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ہم پر اپنی تلوارکا وارکیا تو تم میں سے بعض افراد شک وشبہ کا شکار ہوگئے اور یہ کہنے لگے کہ اگر یہ لوگ حق پر نہ ہوتے تو ہمارے خلاف جنگ کے لئے نہ نکلتے ،خدا کی قسم ان کے پاس مکھی کے ایک آنسوکے برابر بھی حق موجود نہیں ہے ۔
ﷲ کی قسم اگر وہ ہم پر اپنی تلوار وں سے حملہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمیںسعفات ہجر (ایک مقام کانام)تک پہونچادیں تب بھی مجھے یہی معلوم ہوگا کہ میں حق پر ہوں اور وہ باطل پر ہیں اور خدا کی قسم اس وقت تک امن وامان قائم نہیں ہوسکتا ہے جب تک فریقین میں سے کوئی ایک فریق اپنے حق ہونے کا منکر نہ ہواور وہ یہ گواہی نہ دے کہ اسکا مخالف فریق بر حق ہے ا ور ان کے مقتولین اور مردے جنّتی ہیں اور دنیا کے دن اس وقت تک پورے نہیں ہوسکتے جب تک وہ یہ اقرار نہ کرلیں کہ ان کے مردے اور مقتولین جہنمی اور زندہ رہنے والے اہل باطل ہیں۔( ۱ )
کھوکھلااوربے ہنگم انسان(شخصیت )
کھوکھلے اور بے ہنگم لوگوں کے نفس میں اندرونی کشمکش اور بیقراری کا آغاز سب سے پہلے عقل اور خواہشوں کی خانہ جنگی سے ہوتا ہے کیونکہ خواہشیں انسان کے نفس کو اسکی عقل کی ماتحتی اور کنٹرول سے باہر نکالنے کی در پے رہتی ہیں جس سے آدمی کا نفس دو متصادم دھڑوں میں تقسیم ہوجاتا ہے ۔
اس داخلی جنگ کے نتیجہ میں انسان کی مشکلات اور زحمتیں بہت زیادہ ہوجاتی ہیں کیونکہ انسان کے اوپراسکے ضمیر، فطرت اور عقل کی حکومت بہت مستحکم ہوتی ہے اور یہ اسباب اسکے اندر ہوس کے نفوذ(داخلے)کاسختی سے مقابلہ کرتے ہیں اور انکی مسلسل یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ انسان کی شخصیت کوتقویت دیکراسے اسکی پہلی حالت اور فطرت کی طرف لوٹا دیں اس مرحلہ میں انسانی نفس کے اندر ایک خلفشار اور خانہ جنگی کی صورت حال رہتی ہے جسکی بنا پر اسے سخت زحمتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جب انسا ن کی عقل اس کی رفتار وکردار کو کنڑول کرنے اور اسے استقامت عطا کرنے سے عاجز ہوجاتی ہے اور انسان کے لئے اسکے نفس کااندرونی خلفشار اور خانہ جنگی بھی ناقابل برداشت
____________________
(۱)صفین،نصربن مزاحم ص۳۲۲۳۲۱
ہوجاتے ہیں تو پھر وہ اپنی فطرت سے فرار کی کوشش کرنے لگتا ہے جو ان مشکلات کا منفی اور غلط راہ حل ہے بلکہ اسکا صحیح راہ حل تویہ ہے کہ اپنی عقل وفطرت کو پھر سے زندہ کرکے اسے استحکام بخشے اور اسکے احکامات کے مطابق عمل کرے۔
لیکن اسکے بجائے صورتحال یہ ہوجاتی ہے کہ انسان خواہشات کی سلطنت کے سامنے سپر ڈال دیتا ہے اور ان مشکلات سے نجات پانے کے لئے اپنی فطرت سے فرار کی کوشش کرتا ہے ؟اور نشہ،جو ا،جرائم یا جنسیات کے دامن میں پناہ تلاش کرتا ہے ۔
مزید تعجب کی بات تویہ ہے کہ انسان اپنی ہوس سے اپنی ہوس ہی کی طرف فرار کرتا ہے اور ایک جرم سے دوسرے جرم کی طرف بھاگتا ہے ورنہ اگر وہ اپنی ہوس کے برخلاف قدم اٹھائے اور خواہش نفس اور ہوس سے خدا کی طرف آگے بڑھے توبآسانی ان سے نجات پاکرسکون حاصل کرسکتا ہے جسکی طرف قرآن مجید نے ان الفاظ میںمتوجہ کیا ہے :
(ففرّوا الیٰ ﷲ انی لکم منه نذیرمبین )( ۱ )
''لہٰذا اب خدا کی طرف دوڑپڑو کہ میں کھلا ہوا ڈرا نے والا ہوں''
لہٰذا جب تک انسان خداوند عالم کی پناہ حاصل نہ کرلے وہ اپنی ہوس کے سامنے لاچار اور مجبور ہی رہتا ہے اسی لئے وہ مشکلات اور زحمتوں نیز اپنی زندگی کے دردسر سے نجات پانے کے لئے نشے اور جنسیات کارخ کرتا ہے جنکے بارے میں قرآن کریم کی یہ تعبیر کتنی صحیح ہے کہ :
(نسوا ﷲ فأنساهم أنفسهم )( ۲ )
''انھوں نے خدا کو بھلاڈالاتو خدا نے خود ان کو بھی نظر انداز کردیا''
کیونکہ جو لوگ اپنی فطرت اور ضمیر سے فرار کرکے شراب یا جوئے وغیرہ کی طرف بھاگتے
____________________
(۱)سورئہ ذاریات آیت ۵۰۔
(۲)سورئہ حشر آیت ۱۹۔
ہیں در اصل وہ اپنے کو بھلادینا چاہتے ہیں اور انسان کا یہ فرار ذکر(یاد)سے نسیان (بھول)کی طرف ہے جو خود فرار سے بدترہے ۔
بالآخرانسان کے نفس اور اسکی شخصیت کے اندر ہوی وہوس کا مقابلہ کرنے والی آخری طاقت کا نام ضمیر ہے جو حتی الامکان اپنی کوشش بھر انسان کواسکی ہوس اور شیطان کے خونخوار پنجوں سے
بچانے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ جب ضمیر بھی خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے تو پھر انسانی وجود کے اندر اسکے خواہشات کا مقابلہ کرنے والا آخری قلعہ بھی منہدم ہوجاتا ہے اور یہی اس جنگ کا پہلا مرحلہ ہے جسکے بعد انسان دائمی دردسر اور تشنج کا شکار ہوجاتا ہے ۔
جب خواہشات ہر اعتبار سے فتح یاب ہوجاتے ہیں اور انسان کے اوپر ان کی سلطنت کا نفوذ ہوجاتا ہے اور وہ پورے طورپر ان کے دائرہ اختیار کے اندرآجاتا ہے ۔۔۔تب بھی اسے اپنے خیالات کے برخلاف اس اندرونی خلفشاراور خانہ جنگی سے نجات نہیں مل پاتی بلکہ نفس کے اندرہی خود ان خواہشات کے درمیان ایک اور خانہ جنگی اور خلفشار شروع ہوجاتا ہے بلکہ اس بار اسکا انداز اورزیادہ خطرناک اور سخت ہوتا ہے کیونکہ انسان اس مرحلہ میں مختلف قسم کے خواہشات نفس (اور ہوس)کے درمیان تذبذب کاشکاررہتاہے لہٰذا اسکا خلفشار پہلے مرحلہ کی بہ نسبت کہیں زیادہ ہوجاتا ہے اور اگر اسکی دردسر ی اورذہنی پریشانی گذشتہ مرحلہ سے زیادہ نہ ہو تو بہر حال اس سے کم ہرگز نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس مرحلہ میں بھی گذشتہ مرحلہ کی طرح اسکے معاملات بالکل متفرق اوردرہم برہم ہوجاتے ہیں البتہ ان دونوں کے درمیان یہ فرق ضرورہوتا ہے کہ پہلے مرحلہ میں انسان کی مشکلات کے دوران اسکی عقل اور خواہشات کے درمیان ٹکرائو ہواتھا لیکن اس مرحلہ میں خوداسکی خواہشات اور ہوس کے درمیان ٹکرائورہتا ہے کیونکہ اسکی ہر خواہش (ہوس)دوسری خواہشات کے مقابلہ میںآگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے اسی لئے ان کے درمیان یہ جنگ جاری رہتی ہے ۔
اس سلسلہ میں چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں :
۱۔جب کبھی انسان جذبۂ انتقام اورغصہ یا محبت دنیا اور عہدہ کی محبت کے درمیان تذبذب کا شکار ہوتا ہے تو حکومت ،عہدہ اور پوسٹ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ نرم رویہ سے پیش آئے مگر جذبۂ انتقام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقابلہ میں آنے والے ہردشمن کا قلع قمع کردے ۔۔۔اور ہمیں بخوبی یہ معلوم ہے کہ یہ نرمی اور مدارات ،حلم کی قسم نہیں ہے (جو عقل کے لشکروں میں سے ہے)بلکہ یہ درحقیقت ایک ہوس کودوسری ہوس پر ترجیح دینے کا نتیجہ ہے ۔
۲۔کبھی عہدہ یا حکومت کی لالچ اور سماجی مقام یاعظمت ووقار جیسے دو جذبات اور خواہشات کے درمیان ٹکرائو پیدا ہوجاتا ہے کیونکہ انسان کی سماجی عزت ووقار اس سے کچھ خاص اقدار وآداب کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ دوسرے خواہشات ان سے کنارہ کشی کے خواہاں ہوتے ہیں جیسے جنسی خواہش،لہٰذا ان سیاسی یا سماجی عہدوں اور کرسیوں تک پہونچنے کے لئے اپنے جنسیات پر کنٹرول کرنا، یہ کسی عفت کی بنا پر نہیں ہے ۔بلکہ یہ ایک خواہش(ہوس) کو دوسری ہوس پر ترجیح دی گئی ہے۔یہی وجہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنسی ہوس دوسرے خواہشات (عہدہ کی لالچ)پر غالب آجاتی ہے جسکے نتیجہ میں ارباب حکومت کے یہاںبھی جنسی اسکینڈل رونما ہوجاتے ہیں اور انہیں بد نام کرکے رکھ دیتے ہیں ۔
۳۔کبھی انسان کسی عہدے کی محبت اوراپنی جان کے خوف کا نوالہ بن کر رہ جاتا ہے کیونکہ عہدہ کی تمنا اس سے دوسروں پر حملہ کرنے انہیں قتل وغارت کرنے اور خطرات میں کو د پڑنے کا مطالبہ کرتی ہے لیکن جان کا خطرہ اس کو حفاظتی انتظامات اور احتیاطی تدابیر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پر اکساتا ہے ۔
دومختلف قسم کی خواہشات کی بناء پر انسانی نفس کے اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی کی یہ تین مثالیں آپکے سامنے حاضرہیںان کے علاوہ بھی مختلف خواہشات کے درمیان نہ جانے ایسے کتنے حادثات ہر روز رو نما ہوتے رہتے ہیں جوانسانی زندگی کے لئے ایک عام بات ہیں اور اس میں متعدد خواہشات اور جذبات ایک دوسرے سے ٹکراکر اسے اپنی سمت کھینچنا چاہتے ہیں اور انسان خوف اور لالچ ، حب جاہ ،بخل وحسد ،جنسیات اور غصہ و انتقام نیز حب مال جیسے خواہشات کے کھنچائو کی بناپر،تتر بتر ہو کر رہ جاتا ہے جسکے بعد وہ اپنے ذہنی بوجھ اور مشکلات کے دلدل میں اور زیادہ دردسری کاشکار ہوجاتا ہے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( انّما یریدﷲ لیعذبهم بهافی الحیاة الدنیاوتزهق أنفسهم وهم کافرون ) ( ۱ )
''بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں کے ذریعہ ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے ''
یہی معاملات کادرہم برہم ہوناہے جس کی طرف حدیث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے ۔
ہوس کے عذاب
جب انسان اپنی ہوس کا شکار ہو جاتا ہے تو اسکے خواہشات کا ٹکرائو بھی اسکے لئے وبال جان بن جاتا ہے جبکہ اس کے پنجوں میں پھنسے کے بعد انسان جس دوسرے دردسر اور زحمت میں مبتلا ہو تا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ عذاب خود اس ہوس سے مربوط ہوتا ہے لہٰذا انسان کی ہوس اور خواہش جیسی ہوگی اسکا ویسا ہی عذاب اور دردسر سامنے آئے گاجیسے حرص ،لالچ اورحسد جیسے خواہشات اگر ہمارے نفس کے اندر جگہ بنالیں تو ان کی خواہش ہمیں ایک الگ مصیبت میں مبتلا کردے گی اوریہ طے شدہ بات ہے کہ جو شخص اپنے معاملات کو ان خواہشات کے حوالے کردیگا وہ ان مصائب سے نجات نہیں پاسکتا ہے ۔
خواہشات کے چنگل میں رہ کر انسان جس عذاب اور وبال جان میں مبتلا ہوتا ہے اسکی طرف اس روایت میں اشارہ موجود ہے جسے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الارشاد(۲) میں امیرالمو منین سے نقل کیا ہے :
____________________
(۱)سورئہ توبہ آیت ۵۵۔
(۲)ارشاد مفیدص ۱۵۹ ۔
(ماأعجب أمرالانسان،ان سنح له الرجاء أذلّه الطمع،وان هاج به الطمع هلکه الحرص،وان ملکه الیأس قتله الأسف،وان سعد نسی التحفظ،وان ناله خوف حیّره الحذر،وان اتسع له الامن أسلمته الغرّة''الغفلة''وان أصابته ۔۔۔)
''اس انسان کے معاملات کتنے تعجب آور ہیں کہ اگر اسے امید کی کرن نظر آنے لگے تو طمع اسکو ذلیل کر دیتی ہے اور اگر اسکی لا لچ بھڑک اٹھے توحرص اسے ہلاک کر ڈا لتی ہے اور اگر اس پر نا امیدی کا غلبہ ہوجائے تو افسوس اسے قتل کردیتا ہے اور اگر وہ کامیاب اورخوشحال ہوجائے تو پھر (دین کی)پابندی کو بھول جاتا ہے ،اگر اسے خوف لاحق ہوجائے تو دہشت متحیر وسرگردان کردیتی ہے اور اگر ہر طرف امن وسکو ن رہے تو غفلت (دھوکہ)میں گرفتارہوجاتاہے اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوجائے تو بے صبری اور آہ وفریاد ذلیل کردیتی ہے اگر کہیں سے مال مل جائے تودولت اسے باغی بنادیتی ہے اگر وہ فاقہ کے چنگل میں پھنس جائے توبلائیں اسکے شامل حال ہوجاتی ہیں اور اگر بھوک لاغر بنادے تو کمزوری نڈھال کردیتی ہے اور اگر کھانے پینے میں افراط کر بیٹھے تو پرخوری سے اس کا سانس رک جاتا ہے ۔مختصر یہ کہ اسکے لئے ہر تقصیر مضر ہے اور ہر زیادہ روی (افراط)مفسد ہے اور اس (افراط)کے بعد ہر خیر شر بن جاتا ہے اور ہر شر اسکے لئے ایک آفت ہے ''
مختصر یہ کہ دنیا کے بارے میں پرامیدہونا ہر انسان کو طمع کی ذلت کے حوالہ کردیتا ہے اور طمع (لالچ)ہلاکتوں کے سپردکردیتی ہے کسی چیز سے مایوسی کے بعد وہ کف افسوس ہی ملتا رہتا ہے اور کوئی خوف پیدا ہوجائے تو وہ دہشت کے منھ میں جھونک دیتا ہے اس طرح ہرخواہش اور ہوس ایک نئی خواہش اور ہوس کے حوالے کردیتی ہے اور آخر کار وہ ہلاکت کے منھ میں پہونچ جاتا ہے ۔
دنیا اپنے خواہشمند کے لئے ایک وبال جان
انسان کے دنیا وی عذاب کا پہلا رخ اور پہلا مرحلہ تو اسکے خواہشات (ہوس)ہیں مگر دوسری منزل میں خود یہ دنیا اسکے لئے عذاب بن جاتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ دنیا خواہشات (ہوس) کا کھلا میدان،ان کی آخری منزل، انکے حصول کا سرچشمہ،ان کی آماجگاہ اور انکو ابھارنے اور ان کی پرورش کی جگہ ہے
لہٰذا جب خداوند عالم کسی انسان کو خواہشات نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تواس پر یہ عذاب لا محالہ، طلب دنیا کے ذریعہ ہی ہوتا ہے کیونکہ انسانی ہوس اور دنیا طلبی کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور اسلامی افکار کے اہم مسائل کا حصہ ہے جس کی ہم یہاںوضاحت کر رہے ہیں ۔
اگر کوئی انسان اپنے ضروریات زندگی اور ضروریات دین اور تکامل کے لئے دنیا حاصل کرے تو اس حصول دنیا اور حتی دنیا میںکوئی چیزشر اور عذاب نہیں ہے جس کی تصدیق اسلام میں موجود ہے کیونکہ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز شر نہیں ہے بلکہ سب خیر ہی خیر ہے اسی لئے اس نے دنیا حاصل کرنے اور رزق تلاش کرنے کے لئے دوڑدھوپ کرنے کو شریعت کا جزء قرار دیا ہے کیونکہ اسلام کی نگاہ میں دنیا اولیاء خدا کا میدان تجارت (منڈی)اور اسکے محبین کی مسجد ہے :
(متجرأولیاء ﷲ،ومسجدأحبّاء ﷲ )( ۱ )
''(دنیا)اللہ کے اولیاء کا میدان تجار ت اور اسکے محبین کی مسجد ہے''
لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا شر اور عذاب ہو
اس دنیا میں محنت ومشقت کرنا اور رزق تلاش کرنا شریعت اسلامیہ کاجزہے جس کی تائید کے لئے قرآن مجید کی اس آیت میں مہر تصدیق ثبت ہے :
(فاذاقضیت الصلوٰة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل ﷲ )( ۲ )
''جب نماز تمام ہوجائے تو روئے زمین پر پھیل جائو اور فضل الٰہی تلاش کرو ''
لہٰذاجب یہ سب خیر ہے تو شر اور عذاب کا وجود کہاں رہے گا؟
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت۱۳۱۔
(۲)سورئہ جمعہ آیت ۱۰۔
لہٰذا جب تک یہ دنیا خداوند عالم تک پہونچنے کا ذریعہ اور اسکی مرضی حاصل کرنے کاوسیلہ ہو اور اس سے بڑھ کر خودخدا تک جانے کا ارادہ ہو تو یہ پوری دنیا اور اس میں ہونے والی ہر کوشش خیر ہی خیر ہے۔۔۔
لیکن اگر انسان کی محنت و مشقت اوراسکی حرکت کا رخ خداوند عالم اور اسکی مرضی حاصل کرنے کے بجائے دنیا کی طرف مڑجائے تو یہ اسلام کی نظر میں ناقابل برداشت بات ہے ۔اور اسے اس نے شر قرار دیا ہے اور اسی کو خداوند عالم انسان کے لئے عذاب دنیا بنا دیتاہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا انسان کی نظر میں خدا تک پہونچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہونے کے بجائے خودایک مستقل مقصد میں تبدیل ہوجائے تو پھر انسان اپنی گمراہی کی وجہ سے خدا کی طرف جانے کے بجائے دنیا کی طرف چل دیتا ہے اور اسکی نظر یںذات خدا کے بجائے دنیا کی رنگینیوں پر ٹکی رہتی ہیں اور جب وہ دنیا میں گھرارہ جائے تو اسکا ہر عمل باطل اور محنت بیکارنیز اسکی ترقی اور تکامل معطل ہوکر رہ جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ تنزلی ،لغزش اور خسارہ کا شکار ہوجاتا ہے ۔
بلکہ کبھی کبھی انسان خداوند عالم سے منحرف ہوکر اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ خداوندعالم سے جنگ کی ٹھان لیتا ہے اور کھلم کھلا خدا ورسول کی دشمنی کا اعلان کرتا ہے ۔
بہر حال چاہے جو کچھ بھی ہواگر یہ دنیا انسان کے لئے خدا تک پہونچنے کا وسیلہ ہونے کے بجائے منزل مقصود میں تبدیل ہوجا ئے اور انسان کی کل دوڑدھوپ دنیا طلبی تک محدودرہے تو پھر یہی دنیاانسان کیلئے دردسر اور عذاب جان بن جاتی ہے ۔
جودنیا، انسان کی خواہشمند ہوتی ہے اور جس دنیا کا خواہشمند انسان ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ انسان کی خواہشمند دنیا اسے خدا تک پہونچاتی ہے لیکن جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہی دنیاخدا تک پہونچنے کا راستہ ہونے کے بجائے اس کے لئے سنگ راہ بن کر عذاب اور وبال جان بن جاتی ہے ۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے روایت ہے :
(لما خلق ﷲ الدنیا أمرها بطاعة ربّها،فقال لها خالفی مَنْطلبکِ ووافقی من خالفک،فهی علیٰ ماعهد الیها ﷲ وطبعهاعلیه )( ۱ )
''جب خداوند عالم نے دنیا کو خلق فرمایا تو اس سے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے طلب کرے (تیرا خواہشمند ہو )اسکی مخالفت کرنا اور جو تیرامخالف ہو اسکی موافقت کرنا لہٰذایہ دنیا خداوند عالم سے کئے ہوئے عہد کے مطابق اپنی طبیعت پر باقی ہے ''
روایت میں بطور کنایہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص فکر دنیا میں پڑجائے اور اسی کو اپنا سب کچھ سرمایہ اور مقصد قرار دیدے توخداوند عالم اسی دنیا کو اسکے لئے عذاب بنا دیتا ہے اور جو شخص دنیا سے دل نہ لگائے اور اسکی مخالفت کرتا رہے تو پروردگار اسکے لئے دنیا کو چین اور سکون میں بدل دیتا ہے ۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :
(أوحیٰ ﷲالیٰ الدنیا:اخدمی من خدمنی،وا تعبی من خدمک )( ۲ )
''ﷲ تعالی نے دنیا کی طرف یہ وحی فرمائی جو میری خدمت کرے اسکی خدمت گذار بننا اور جو تیری خدمت کرے اسکے لئے عذاب بن جانا''
اس روایت میں بھی گذشتہ روایت کی طرح یہ کنایہ موجود ہے کہ اگر انسان کا مقصد خداوندعالم کو خوش کرنا ہو،تو یہ دنیا اسکی خدمت کے لئے خلق کی گئی ہے لیکن جب اسکا مقصد خدا کے بجائے دنیا ہوجائے تو پھر اسکے لئے دنیا کی خدمت کرنا ضروری ہے اور دنیا کی خدمت کرنا کسی عذاب
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۰ص۳۱۵۔
(۲)بحارالانوارج۷۸ص۲۰۳۔
اور درد سر سے کم نہیں ہے ۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے ہی یہ بھی روایت ہے :
(ان ﷲ جل جلاله أوحیٰ(الیٰ)الدنیا أن اتعبی منخد مک واخدمی من رفضکِ )( ۱ )
''خداوند عالم نے دنیا کی طرف یہ وحی فرمائی کہ جو تیری خدمت کرے اسے عذاب میں مبتلا کردینا اور جو تجھے چھوڑدے اسکی خدمت کرنا''
اس روایت کا بھی انداز اور لہجہ بعینہ وہی ہے بلکہ اگر کوئی روایات کے اندازبیان سے واقف ہوتو اسے بخوبی محسوس ہوگا کہ اس روایت میں گذشتہ روایات کے بالمقابل کچھ زیادہ صراحت موجود ہے ۔
حضرت علی سے مروی ہے :
(من خدم الدنیا استخدَ متْه ومن خدم ﷲخد مه )( ۲ )
'' جو شخص دنیا کی خدمت کریگا وہ اسے اپنا نو کر بنائے رکھے گی اور جو شخص خداوند عالم کی خدمت(اطاعت)کریگا تو خداوند عالم دنیا کواس کا خدمت گذار بنادیگا''
ﷲ تعالی نے جناب موسیٰ کی طرف یہ وحی فرمائی :
(ما من خلقی أحد عظّمها(۳)فقرّت عینه ،ولم یحقّرها أحد الا انتفع بها )( ۴ )
''یعنی میری مخلوقات کے درمیان کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے دنیا کو بڑا سمجھا
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۳ص۱۲۱۔
(۲)غرر الحکم ج۲ ص۲۳۷۔
(۳)یعنی دنیا۔
(۴)بحارالانوارج۷۳ص۱۲۱۔
ہو اور اسکی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہو اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اسکو ذلیل سمجھا ہو اور اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو''
کتب احادیث میں اس قسم کی روایات بہت زیادہ ہیں مگر یہ دوسری بات ہے کہ ان روایات میں کا ئنات کے بارے میںالہی سنتوںکی وضاحت جس انداز میںپیش کی گئی ہے اگر کوئی اس سے واقف نہ ہوتو یہ روایات اسکے لئے کچھ مبہم ہیں لیکن جولوگ زبان وبیان حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان روایات میں جس عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد وہ عذاب ہے جو خدا سے روگردانی کرنے اور دنیا سے دل لگالینے کی صورت میں اسکے سامنے آتا ہے یعنی یہ دنیا ہی اسکے لئے عذاب بن جاتی ہے لیکن اگر اسکا دل خداوند عالم کی طرف متوجہ رہے اور وہ دنیا کو خداوند عالم تک رسائی حاصل کرنے کے ذریعہ کے علاوہ کچھ اور خیال نہ کرے اور اسی نیت سے دنیاکا ہر کام کرتار ہے اور اپنا رزق کمائے تو دنیا اسے نقصان نہیں پہونچاسکتی بلکہ وہ اسکے لئے فائدہ مند اور خدمت گذارہی ثابت ہوگی۔
خواہشات کی پیروی کے بعد انسان کی دوسری مصیبت
گذشتہ صفحات میں ہم نے دنیا داری اور خواہشات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے پہلے عذاب کا تذکرہ کیا ہے جس میں انسان کے معاملاتِ زندگی بکھرکر رہ جاتے ہیں اوراسکی خواہشات کے آپسی ٹکرائو کی بناء پر اسکا نفس عجیب وغریب اندرونی خلفشار کا شکار ہوجاتا ہے ۔
مگر اس تذبذب اور خلفشار کے بعد بھی یہ خواہشات انسان کو چین سے نہیں رہنے دیتیں بلکہ جب انسان خدا سے اپنا منھ پھیرکر انہیں خواہشات کے مطابق چلتا ہے تو وہ حرص اور لالچ کے عذاب میں بھی پھنس جاتا ہے کیونکہ اگر انسان کی توجہ خدا کے بجائے دنیا کی طرف ہوتو وہ کسی چیز سے سیر نہیں ہوپاتا اور اسے چاہے جس مقدار میںدنیا مل جائے یا اسکے برعکس وہ اس سے منھ پھیرے رہے تب بھی اسکی طمع کا وہی حال رہے گا کیونکہ یہ ایک نفسیاتی بات ہے اور مال ودولت وغیرہ کی کمی یا زیادتی سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جتنی زیادہ فراوانی کے ساتھ دولت ملتی ہے اسکے اندر دنیا کی محبت اور لالچ اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور انسان دنیا کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا ہے اور اسکا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر پاتا اور اسکے سینہ میں محبت دنیا کی آگ پہلے کی طرح ہی جلتی رہتی ہے اور وہ کبھی سردنہیں پڑتی ہے ۔
دنیا انسان کا ایک سایہ
جب انسان اس دنیا کو اپنا مقصد حیات بنالے تو پھر اس دنیا کے بارے میں وہی مثال مناسب ہے جو بعض روایات میں امیر المومنین سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا :
(مثل الدنیا کظلکِ،انْ وقفتَ وقفَ،وانْ طلبتَه بَعُدَ )( ۱ )
''دنیا کی مثال تمہارے سایہ کی طرح ہے کہ اگر تم رک جائو تو وہ بھی رک جائے گا اور اگر تم اسے پکڑنا چاہو تو وہ تم سے دور بھاگے گا''
آپ کا یہ جملہ دنیا سے انسان کے رابطہ اور انسان سے دنیا کے رابطہ کے بارے میں بہت ہی بلیغ ہے کیونکہ دنیا کی لالچ اور اس پر ٹوٹ پڑنے سے اسے اپنے نصیب سے زیادہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ دنیا بالکل سایہ کی طرح ہے کہ اگرہم اسکی طرف آگے بڑھیں گے تووہ ہم سے اتنا ہی آگے بڑھ جائے گا ۔گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپناپیچھا کرنے والے سے فرار کرجاتا ہے ، لہٰذا اسکے پیچھے دوڑنے سے تھکن اور دردسر کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے ۔۔۔ اور بالکل یہی حال دنیا کا بھی ہے ۔
لہٰذا دنیا کو حاصل کرنے کا سب سے بہتر راستہ یہی ہے کہ طلب دنیا کی آرزو کو مختصر کردیا جائے اور دنیا کے اوپر جان کی بازی نہ لگائی جائے کیونکہ اس کے اوپر مرمٹنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے بلکہ انسان اپنے لئے مزید مصیبت مول لے لیتا ہے ۔
____________________
(۱)غررالحکم ج۲ ص۲۸۴۔
روایات کی روشنی میں عذاب دنیا کے چند نمونے
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :(ما سکن حب الدنیاقلباً الا التاط بثلاث:شغل لاینفدْ عناؤه،وفقرلا ید رکغناه،وأمل لاینال مناه )( ۱ )
''دنیا کی محبت کسی دل میں نہیں آتی مگر یہ کہ وہ تین چیزوں میں مبتلاہوجاتاہے ایسی مصروفیت جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی،ایسی فقیری جو مالداری میں تبدیل نہیں ہوسکتی اور ایسی آرزو جو کبھی پوری نہیں ہوسکتی ہے ''
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے مروی ہے :
(من أصبح والدنیا أ کبرهمه،فلیس من ﷲ فی شی ئ،وألزمه قلبه أربع خصال:همّاً لا ینقطع أبداً،وشغلاً لاینفرج عنه أبداً،وفقراً لایبلغ غناه أبداً،وأملا ً لا یبلغ منتهاه ابداً )( ۲ )
''صبح ہوتے ہی جسے سب سے زیادہ دنیا کی فکر ہوا سے خدا سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے بلکہ وہ اسکے دل میں چار خصلتوںکو راسخ کردے گا۔کبھی ختم نہ ہونے والا غم،ایسی مصروفیت جس سے کبھی چھٹکارانہ ملے،ایسی فقیری جو استغنا تک نہ پہونچ سکے ،ایسی آرزو جو کبھی اپنی آخری منزل نہ پا سکے''
حضرت علی :
(من لهج قلبه بحب الدنیاالتاط قلبه منهابثلاث:همّ لایغنیه، ومرض لایترکه،وأمل لایدرکه )( ۳ )
____________________
(۱)بحارالانوار ج ۷۷ ص ۱۸۸ ۔
(۲)میزان الحکمت ج۳ص۳۱۹۔
(۳)شرح نہج البلاغہ ابی الحدیدج۱۹ص۵۲،بحارالانوار ج۷۳ص۱۳۰۔
''جس شخص کا دل دنیا کی محبت کا دلدادہ ہوجائے اسکا دل تین چیزوں میں پھنس کررہ جاتا ہے ۔ ایسا غم جس سے افاقہ ممکن نہیںایسی بیماری جو اسے کبھی نہ چھوڑے گی ایسی آرزو جسے وہ کبھی نہیں پاسکتا''
حضرت علی :
(من کانت الدنیا اکبر همّه،طال شقاؤه وغمه )( ۱ )
''جسکے لئے دنیا سب کچھ ہوگی اسکی بدبختی اور غم طولانی ہوجائینگے''
حضرت علی :
(من کانت الدنیا همّته اشتدت حسرته عند فراقها )( ۲ )
''جسکا سب سے بڑا مقصد، دنیا ہو تو اس سے دوری کے وقت اس کی حسرت شدید ہوجاتی ہے ''
حضرت علی :
(المتمتّعون من الدنیا تبکی قلوبهم وان فرحوا،ویشتد مقتهم لانفسهم وان اغتبطواببعض مارزقوا )( ۳ )
''دنیا سے لطف اندوز ہونے والے اگر چہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں مگر ان کے دل روتے ہیں اور وہ خود اپنے نفس سے بیزار رہتے ہیں چاہے لوگ ان کے رزق سے غبطہ ہی کیوں نہ کریں''
امام جعفر صادق :
(من تعلّق قلبه بالدنیا تعلّق قلبه بثلاث خصال:همّ لایُغنی،وأمل لایُدرک، ورجاء لایُنال )( ۴ )
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۳ص۸۱۔
(۲) بحارالانوار ج۷۱ ص۱۸۱۔
(۳)بحارالانوارج۷۸ص۲۱۔
(۴)بحار الانوار جلد ۷۳ص۲۴۔
''جسکا دل دنیا سے وابستہ ہوجائے اسکے دل کے اندر تین خصلتیں پیدا ہوجاتی ہیں:لازوال غم ،پو ری نہ ہونے والی آرزو،ہاتھ نہ آنے والی امید''
یہ رنگ برنگے عذاب ،دنیا کے ان عذابوں کا کچھ حصہ ہیں جو خداوند عالم نے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے لئے آخرت سے پہلے اسی دنیا میں معین فرمادئے ہیں مثلاً اہل ثروت کو اپنے اقرباء یا دور والوں سے اپنے مال کے بارے میں جو خوف اور پریشانی لا حق رہتی ہے یہ ان کے لئے دنیاوی عذاب کا صرف ایک حصہ ہے ۔
آخرت میں انسان کی سرگردانی وپریشا ں حالی
حدیث قدسی میں انسان کی جس پریشان حالی (افتراق اوردرہم برہم ہوجانے )کا تذکرہ ہے اسکا تعلق صرف دنیا سے ہی نہیںہے بلکہ دنیا کی طرح اسے آخرت میں بھی اسی صورتحال سے دوچارہونا پڑے گا ۔
آخرت میں یہ افتراق اور بیقراری سب سے پہلے اپنے خواہشات نفس اور ہوی وہوس کے پیچھے چلنے والوں کے درمیان ہی دکھائی دینگے کیونکہ وہ دنیا میں جسمانی اعتبار سے بظاہر متحدضرور تھے مگر ان سب کی تمنائیں اور ہوس ایک دوسرے سے الگ تھیں نیزانھوں نے اپنے جواختلافات دنیا میں چھپارکھے تھے وہ سب آخرت میں کھل کر سامنے آجائیں گے خداوند عالم نے قرآن مجید میں اہل جہنم کے حالات کی یوںتصویر کشی کی ہے :
(کلّما دخلت اُمة لعنت اُختها )( ۱ )
''جہنم میں داخل ہونے والی ہر جماعت اپنی دوسری برادری پر لعنت کرے گی''
اس اختلاف اور انتشار یا خانہ جنگی کی دوسری صورت اس وقت سامنے آئے گی کہ جب
انسان خدا سے اپنے جرائم چھپانا چاہے گا اور اسی وقت اس کے اعضاء اسکے جرائم کے بارے میں
____________________
(۱)سورئہ اعراف آیت ۳۸
گواہی دینے لگیں گے تو وہ ان پر غصہ ہو گااوراسی وقت اسکے یہی ہاتھ پیر اور کھال وغیرہ اسے ذلیل و رسوا کرکے رکھ دینگے تووہ اپنے اعضاء سے یہ کہے گا:
(وقالوا لجلود هم لم شهد تم علینا قالوا أنطقنا ﷲ الذی أنطق کلّ شیئ )( ۱ )
''اور وہ (اہل جہنم )اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دیدی تو وہ جواب دینگے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے ''
بلکہ روایات میں تو یہاں تک ہے کہ روز قیامت اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے گنہگاروں کے بعض اعضاء ان سے اظہار نفرت کرینگے اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے دکھائی دینگے اور یہ بعینہ وہی صورتحال ہے جو دنیا میں خواہشات کی پیروی کی بنا پر انسان کے اندر دکھائی دیتی ہے ۔
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے مروی ہے :
(کُفّ أذاک عننفسک،ولا تتابع هواهافی معصیةاللّٰه،اذتخاصمک یوم القیامة،فیلغی بعضک بعضاً،الا أن یغفرﷲو یستر برحمته )( ۲ )
''اپنے نفس کو اذیت نہ دواور معصیت خدا میں اپنے نفس کے خواہشات کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ روز قیامت تم سے جھگڑا کریگا اور اسکا بعض حصہ دوسرے حصہ کو برا بھلاکہے گا ۔مگر یہ کہ خدا وند کریم تمہیں معاف فرمادے اور اپنی رحمت کے پردے ڈال دے ''
____________________
(۱)سورئہ فصلت آیت ۲۱۔
(۲)محجةالبیضاء فیض کاشانی ج۵ص۱۱۱۔
۲۔اسکی دنیا کو اسکے لئے مزین کردوںگا
دنیا کا ظاہر اور باطن
خواہشات کی پیروی کرنے والے کی دوسری سزا یہ ہے کہ اسکے لئے دنیا مزین کردی جاتی ہے اور دنیا کے مزین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری لحاظ سے دنیا اس پرفریب انداز میں اس کے سامنے آتی ہے کہ وہ اسے دیکھ کر دھوکہ میں پڑا رہتا ہے جبکہ وہ دنیا کی واقعی شکل نہیں ہو تی ہے اور انسان اسی ظاہری صورت سے فریب کھا جاتا ہے کیونکہ اس کی جن ظاہری صورتوں کو دیکھ کر وہ فریب خوردہ رہتا ہے وہ وقتی ہیں اور ان میں بہت جلد تبدیلی آجاتی ہے لیکن دنیا کی واقعی شکل و صورت جو اسکے بالکل برخلاف ہے وہ درحقیقت یہ ہے کہ یہ دنیاانسان کے لئے مقام عبرت اور چشم بصیرت حاصل کرنے نیز زہد وتقوی اختیار کرنے کا سرچشمہ اور مرکز ہے ۔
یہی وجہ ہے کہ جن افراد کو خداوند عالم نے چشم بصیرت عنایت فرمائی ہے ان کی نگاہیں دنیاکے وقتی اور اوپری خول کے اندر گھس کر اس کی حقیقت کو بخوبی دیکھ لیتی ہیں اسی لئے وہ اس میں زہد سے کام لیتے ہیں اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے رہتے ہیںلیکن جو لوگ خداوندعالم کی عطا کردہ بصیرت کو ضائع کردیتے ہیں وہ زندگانی دنیا کو اسی ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی نگاہیں اس کے باطن اور حقیقت تک نہیں پہونچ پاتی ہیں لہٰذا ان کے دل اس کے دھوکہ میں پڑے رہتے ہیں ۔
مختصر یہ کہ دنیا کے دو روپ ہیں :
۱۔ظاہری
۲۔ باطنی
اسی اعتبار سے اہل دنیا کی بھی دو قسمیں ہیں :
۱۔کچھ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں دنیا کے ظاہرسے آگے نہیں بڑھتی ہیں ۔
۲۔ کچھ ایسے افراد ہیں جن کی نظر یںدنیا کے باطن کو بخوبی دیکھ لیتی ہیں ۔
اس تقسیم کی طرف قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے ۔
(یعلمون ظاهراًمن الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون )( ۱ )
''یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں ''
لیکن جن لوگوں کو خداوند عالم نے فہم وبصیرت عطا فرمائی ہے ان کے سامنے دنیاکا ظاہر وباطن ایک دوسرے سے مشتبہ نہیں ہوتا ہے ۔البتہ جب خداوند عالم کسی سے غضبنا ک ہوجاتا ہے تو اس کی بصیرت سلب کرلیتا ہے اور پھر اسکے سامنے دنیا کا ظاہر وباطن مخلوط ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ اسکے ظاہری خول اور اسکی واقعی حقیقت کے درمیان تمیزنہیں کرپاتا لہٰذا دنیا کی ظاہری رنگینیاں اسے دھوکہ دیدیتی ہیں اور وہ بھی اس دنیا کوفریب خوردہ نگاہ سے دیکھتا ہے جسکی طرف قرآن مجید نے یوں اشارہ کیا ہے :
(زُیّن للذ ین کفروا الحیاة الدنیا )( ۲ )
''اصل میں کافروں کے لئے زندگانی دنیا آراستہ کردی گئی ہے ''
لہٰذا کیونکہ وہ اسکے پرفریب ظاہر کو دیکھتا ہے اس لئے اسکی نگاہوں میں دنیا سجی رہتی ہے لیکن اگر اسکے باطن پر نگاہ رکھی جائے تو پھر کبھی اسکی رنگینی نظر نہ آئے گی۔
مختصر یہ کہ زندگانی دنیا کے دو روپ اور دوچہرے ہوتے ہیں :
ا۔باطنی حقیقت (اصلی چہرہ)
ب۔ظاہری چہرہ
أ ۔دنیا کا باطنی چہرہ (اصل حقیقت)
جیسا کہ ہم عرض کرچکے ہیں کہ دنیاکی واقعی شکل و صورت صرف اہل بصیرت کو دکھائی دیتی
____________________
(۱)سورئہ روم آیت ۷۔
(۲)سورئہ بقرہ آیت۲۱۲۔
ہے اوراسکی اس شکل میں کسی قسم کا دھوکہ اور فریب نہیں ہے بلکہ وہ منزل عبرت ونصیحت ہے جیسا کہ قرآن کریم نے بھی دنیا کے اس پہلو کی نہایت دقیق تعریف و توصیف فرمائی ہے جسکے بعض نمونے ملاحظہ فرمائیں :
۱۔دنیا ایک پونجی ہے :ارشاد الٰہی ہے :
(وماالحیاة الدنیا فی الآخرة الامتاع )( ۱ )
''اور آخرت میں زندگانی دنیا کی حقیقت مختصر پونجی کے علاوہ اور کیا ہے ''
متاع ،وقتی لذت کو کہا جاتا ہے جبکہ اس کے بالمقابل آخرت کی لذتیں دائمی اور باقی رہنے والی ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے :
(فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل )( ۲ )
''پس آخرت میں اس متاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے ''
۲۔دنیا عارضی ہے ۔ارشاد الٰہی ہے :
(تریدون عرَضَ الد نیاوﷲ یرید الآخرة )( ۳ )
''تم لوگ صرف مال دنیا چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے ''
یا ارشا د ہے :
(تبتغون عَرَضَ الحیاة الدنیا فعند ﷲ مغانم کثیرة )( ۴ )
''اس طرح تم زندگانی دنیا کا چند روزہ سرمایہ چاہتے ہو اور خدا کے پاس بکثرت فوائد پائے جاتے ہیں''
____________________
(۱)سورئہ رعد آیت ۲۶۔
(۲)سورئہ توبہ آیت ۳۸۔
(۳)سورئہ انفال آیت ۶۷۔
(۴)سورئہ نساء آیت ۹۴۔
(یأخذون عَرَضَ هذا الادنیٰ و یقولون سَیُغْفَرلنا )( ۱ )
''لیکن وہ دنیا کا ہر مال لیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا ''
عارضی چیز اسکو کہتے ہیں جو بہت جلد تبدیل ہوکر ختم ہوجائے اور کیونکہ دنیا کی لذتیں تبدیل ہوکر ختم ہو جاتی ہیں اور کسی کے لئے بھی باقی رہنے والی نہیںہیںاسکے باوجود بھی یہ لوگوںکو بری طرح فریب میں مبتلا کردیتی ہیں۔
گویادنیا کی دوصفتیں ہیں :
۱۔وہ صفت جس سے انسان زاہد دنیا بن جاتا ہے ۔
۲۔وہ صفت جو انسان کو فریب میں مبتلا کردیتی ہے ۔(جس سے انسان دھوکہ کھاجاتاہے )
وہ صفت جس کی بنا پر انسان زاہد بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی، زوال پذیر اور بہت جلد ختم ہوجانے والی ہے ۔(لہٰذا وہ اس سے دل نہیں لگاتا)
لیکن اسکا پر فریب رخ یہ ہے کہ یہ نرم لقمہ ہے نچلی سطح پر جلد ہاتھ آجاتی ہے ۔
اور کیونکہ لوگ عام طورسے عجلت پسند ہوتے ہیں لہٰذاوہ جلد ہاتھ آنے والی چٹپٹی چیزوں کو دیر سے ملنے والی دائمی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
(لوکان عرضاً قریباً وسفراً قاصد اً لا تّبعوک )( ۲ )
''پیغمبر،اگر کوئی قریبی فائدہ یا آسان سفر ہوتا تو یہ ضرور تمہارا اتباع کرتے ''
اس طرح انسان کی طبیعت اور فطرت میں ہی جلدبازی پائی جاتی ہے ۔
۳۔دنیا دھوکہ اور فریب کا اڈہ ہے ۔
ﷲتعالی کا ارشاد ہے :
____________________
(۱)سورئہ اعراف آیت ۱۶۹۔
(۲)سورئہ توبہ آیت ۴۲۔
(فلا تغرّنّکم الحیاة الدنیا ولایغرّنّکم بﷲ الغرور )( ۱ )
''لہٰذا تمہیں زندگانی دنیا دھوکہ میں نہ ڈال دے اور خبردار کوئی دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے''
۴۔اور دنیا متاع غرور ہے: یہ دو الفاظ کی ترکیب ہے جن کو قرآن مجید نے دنیا کے لئے الگ الگ اور ایک ساتھ دونوں طرح استعمال کیا ہے ۔جیسا کہ ارشاد ہے :
(وماالحیاةالدنیاالامتاع الغرور )( ۲ )
''اور زندگانی دنیا تو صرف دھوکہ کا سرمایہ ہے ''
اس فریب کی اصل بنیاد دنیا کی وقتی اور ختم ہوجانے والی پونجی ہے ۔
دنیا اورآخرت کا تقابلی جائزہ
اگر ہم قرآن مجید پر ایک اور نظر ڈالیں تو اسکے بیان کردہ اوصاف کی روشنی میں دنیا و آخرت کا موازنہ کرنا بہت آسان ہے جیسا کہ ہم عرض کرچکے ہیں کے قرآن مجید کی نگاہ میں یہ دنیا وقتی ،بہت جلد قابل زوال اور ایسی پونجی ہے جو کسی کے لئے دائمی (اور باقی رہنے والی)نہیں ہے لیکن آخرت سکون واطمینان کی ایک دائمی جگہ ہے ۔جیسا کہ ارشادالٰہی ہے :
( یاقوم انماهذه الحیاة الدنیامتاع وانّ الآخرة هی دارالقرار ) ( ۳ )
''قوم والو،یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے ''
____________________
(۱)سورئہ لقمان آیت ۳۳سورئہ فاطر آیت ۵۔
(۲)سورئہ آل عمران آیت ۱۸۵سورئہ حدید آیت ۲۰ ۔
(۳)سورئہ غافر آیت۳۹۔
دنیا ایک کھیل تماشہ ہے لیکن آخرت دائمی حیات کا گھر ہے اور وہی حقیقی زندگی ہے اور وہ زندگی کھیل تما شہ نہیں ہے ۔
جیسا کہ ارشادالٰہی ہے :
(وماهذه الحیاةالدنیاالالهوولعب وان الدارالآخرة لهی الحیوان لوکانوایعلمون )( ۱ )
''اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشہ کے سوا کچھ نہیں اور اگر یہ لوگ سمجھیں بو جھیں تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی (کی جگہ)تو بس آخرت کا گھر ہے ''
کلا م امیر المومنین میں دنیاکا تذکرہ
مولائے کائنات نے اپنے اقوال میں دنیا کی حقیقت کو بالکل آشکار کر دیا ہے اور اس کے چہرہ سے دھوکہ اور فریب کی نقاب نوچ لی ہے جس کے بعد ہر شخص دنیا کی اصلی شکل و صورت کو بآسانی پہچان سکتا ہے۔
لہٰذا دنیا کے بارے میں آپ کے چند اقوال ملاحظہ فرمائیں :
۱۔(وﷲ مادنیاکم عندی الاکسَفْرٍعلیٰ منهل حلّوا،اذصاح بهم سائقهم فارتحلوا،ولالذاذاتُهافی عینی الاکحمیم أشربُه غسّاقا،وعلقم أتجرع به زُعافا،وسمّ أفعاةٍ دِهاقاً،وقَلادةٍ من نار )( ۲ )
''خدا کی قسم تمہاری دنیا میرے نزدیک ان مسافروں کی طرح ہے جو کسی چشمہ پر اترے ہوں ،اور جیسے ہی قافلہ سالار آواز لگائے وہ چل پڑیں ،اور اسکی لذتیں میری نگاہ میں اس گرم اور
____________________
(۱)سورئہ عنکبوت آیت ۶۴۔
(۲)بحارالانوارج۷۷ص۳۵۲۔
گندے پانی کی طرح ہیں جسے مجبوراً پینا پڑے اور وہ کڑوی چیز ہے جسے مردنی کی حالت میں زبردستی گلے سے نیچے اتارا جائے اور وہ اژدہے کے زہر سے بھرا ہوا پیالہ اور آگ کا طوق ہے''
اس دنیا کا جو رخ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے وہ اسی بھرے ہوئے چشمہ کی طرح ہے جس پر قافلہ ٹھہراہو '' سفرعلی منھل حلوا''اور یہ اسکا وہی ظاہری رخ ہے جس کے اوپر وہ ایک دوسرے کو مرنے اور مارنے کو تیار رہتے ہیں ۔جبکہ مولائے کائنات نے اس کو زود گذر قرار دیا ہے جو کہ دنیا کا واقعی چہرہ ہے :
(اذصاح بهم سائقهم فارتحلوا )''جیسے ہی قافلہ سالار آواز لگائے وہ چل پڑیں''
یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جن لذتوں کیلئے لوگ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مولائے کائنات کی نگاہ میں گرم، بدبوداراور سانپ کے زہر کے پیالہ کی طرح ہے ۔
''جب معاویہ نے جناب ضرار بن حمزہ شیبانی(رح) سے امیر المومنین کے اوصاف و خصائل و معلوم کئے تو آپ نے کہا کہ بعض اوقات میں نے خوددیکھا ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں محراب عبادت میں کھڑے ہیں اور اپنی ریش مبارک ہاتھ میںلئے ہوئے ایک بیمار کی طرح تڑپ رہے ہیں اور ایک غمزدہ کی طرح گریہ کررہے ہیںاس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری رہتے ہیں :
(یادنیاالیک عنی،أبی تعرّضتِ؟أم الیّ تشوّقتِ؟هیهات!!غرّی غیری لا حاجة لی فیکِ،قدطلقتک ثلاثاً،لارجعة فیها:فعیشک قصیر،وخطرک کبیر،واملک حقیر،آه من قلّة الزاد،وطول الطریق )( ۱ )
''اے دنیا مجھ سے دورہوجا کیا تو میرے سامنے بن ٹھن کر آئی ہے اور کیا واقعاً میری مشتاق بن کر آئی ہے بہت بعید ہے جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا دینا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے ۔میں تجھے تین بار طلاق دے چکا ہوں جسکے بعد رجوع ممکن نہیں ہے تیری زندگی بہت مختصر، تیری حیثیت
____________________
(۱) نہج البلاغہ حکمت ۷۷وبحارالانوار ج۷۳ص۱۲۹۔
بہت معمولی ،تیری آرزوئیں حقیر ہیں ،آہ، زاد راہ کس قدر کم اور راستہ کتنا طولانی ہے ''
آپ نے دنیاکے ان تینوں حقائق کو اس سے فریب کھانے والے شخص کے لئے واضح کردیا ہے کہ اسکی زندگی بہت مختصر اسکے خطرات زیادہ اور اسکی آرزوئیں حقیر ہیں ۔
اس بارے میں آپ کے یہ ارشادات بھی ہیں ۔
۱۔(ألاوان الدنیا دارغرّارة،خدّاعة، تنکح فی کل یوم بعلاً،وتقتل فی کل لیلة أهلاً،وتُفرّق فی کل ساعة شملاً )( ۱ )
''یاد رکھو یہ دنیا بہت پر فریب گھر ہے اور بیحد دھوکے باز(عورت کے مانند ہے جو) ہر روز ایک نئے شوہر سے نکاح کرتی ہے اوہر رات اپنے گھر والوں کوہلاک کرڈالتی ہے اور ہرساعت ایک قوم کو متفرق کرڈالتی ہے ''
۲۔(ان اقبلت غرّت،وان أدبرت ضرّت )( ۲ )
''اگریہ دنیا تمہاری طرف رخ کرے گی تو تمہیں فریب میں مبتلا کردیگی اور اگروہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تونقصان دہ ہے ''
۳۔(الدنیا غرورحائل،وسراب زائل،وسنادمائل )( ۳ )
''دنیابدل جانے والا فریب، زائل ہوجانے والا سراب اور خم شدہ ستون ہے ''
۴۔دنیا کے ظاہر وباطن کی نقشہ کشی آپ نے ان الفاظ میں کی ہے :
(مثل الد نیا مثل الحیّة مسّها لیّن،وفی جوفهاالسم القاتل،یحذرها الرجال ذووالعقول،ویهوی الیهاالصبیان بأید یهم )( ۴ )
____________________
(۱)بحارالانوارج۷۷ص۳۷۴۔
(۲)بحارالانوارج۷۸ ص۲۳۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۱۰۹۔
(۴) بحارالانوارج۷۸ص۳۱۱۔
''یہ دنیا بالکل سانپ کی طرح ہے جو چھونے میں بہت نرم ہے مگراسکے اندر مہلک زہر بھرا ہوا ہے اہل عقل اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور بچے اسے ہاتھ میں اٹھانے کیلئے جھک جاتے ہیں ''
اس قول میں امام نے بہت ہی حسین وجمیل انداز میں دنیا کے ظاہروباطن کو ایک دوسرے سے جدا کردیا ہے کہ اسکا ظاہر سانپ کی طرح جاذب نظراور چھونے پر بہت نرم معلوم ہوتا ہے لیکن اسکے باطن میں دھوکہ اور زوال ہی زوال ہے جیسے ایک سانپ کے منھ میں مہلک زہر بھرا رہتا ہے ۔
اسی طرح اس دنیا کی طرف دیکھنے والے لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں :
اہل عقل اور صاحبان بصیرت اس سے خائف رہتے ہیں جس طرح انہیں سانپ سے خوف محسوس ہوتاہے ۔لیکن ان کے علاوہ بقیہ لوگ اس سے اسی طرح دھوکہ کھاجاتے ہیں جس طرح زہریلے سانپ کی چمکیلی اور نرم کھال دیکھ کر بچے دھوکہ کھاتے ہیں ۔
آپ کے ایک خطبہ کا ایک حصہ
''یہ ایک ایسا گھر ہے جو بلائوں میں گھرا ہوا ہے اور اپنی غداری میں مشہور ہے نہ اس کے حالات کو دوام ہے اور نہ اس میں نازل ہونے والوں کے لئے سلامتی ہے ۔
اسکے حالات مختلف اور اسکے طورطریقے بدلنے والے ہیں اس میں پر کیف زندگی قابل مذمت ہے اور اس میں امن وامان کا کہیں دو ر دور تک پتہ نہیں ہے ۔۔۔اسکے باشندے وہ نشانے ہیں جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور اپنی مدت کے سہارے انھیں فنا کے گھاٹ اتارتی رہتی ہے ۔
اے بندگان خدا ،یاد رکھو اس دنیا میں تم اور جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا وہی راستہ ہے جس پر پہلے والے چل چکے ہیں جن کی عمریں تم سے زیادہ طویل اور جن کے علاقے تم سے زیادہ آبادتھے ان کے آثار بھی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے لیکن اب ان کی آوازیں دب گئیں ہیں ان کی ہوائیں اکھڑگئیں ہیں ان کے جسم بوسیدہ ہوگئے ہیں ۔ان کے مکانات خالی ہوگئے ہیں اور ان کے آثار مٹ چکے ہیں وہ مستحکم قلعوں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور چنی ہوئی سلوں اور زمین کے اندرقبروں میں تبدیل کرچکے ہیں جن کے صحنوں کی بنیاد تباہی پر قائم ہے اور جن کی عمارت مٹی سے مضبوط کی گئی ہے ۔ان قبروں کی جگہیں تو قریب قریب ہیں لیکن ان کے رہنے والے سب ایک دوسرے سے اجنبی اور بیگانہ ہیں ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جو بوکھلائے ہوئے ہیں اور یہاں کے کاموں سے فارغ ہوکر وہاں کی فکر میں مشغول ہوگئے ہیں ۔نہ اپنے وطن سے کوئی انس رکھتے ہیں اور نہ اپنے ہمسایوں سے کوئی ربط رکھتے ہیں ۔حالانکہ بالکل قرب وجوار اور نزدیک ترین دیار میں ہیں ۔ اور ظاہر ہے اب ملاقات کا کیاامکان ہے جبکہ بوسیدگی نے انہیں اپنے سینہ سے دباکر پیس ڈالا ہے اور پتھروں اور مٹی نے انہیں کھاکر برابر کردیا ہے اور گویا کہ اب تم بھی وہیں پہونچ گئے ہو جہاں وہ پہونچ چکے ہیں اور تمہیں بھی اسی قبر نے گروی رکھ لیا ہے اور اسی امانت گا ہ نے جکڑلیا ہے ۔
ذرا سوچو اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے تمام معاملات آخری حد تک پہنچ جائیںگے اور دوبارہ قبروں سے نکال لیا جائے گا اس وقت ہر نفس اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرے گا اور سب کو مالک برحق کی طرف پلٹادیا جائے گا اور کسی پر کوئی افترا پر دازی کام آنے والی نہ ہوگی۔( ۱ )
سید رضی نے نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے شریح بن حارث سے فرمایا:
(بلغنی انّک ابتعت داراً بثمانین دیناراً،وکتبت لهاکتاباً، وأشهدت فیه شهوداً؟!)
مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسی (۸۰) دینا ر میں ایک گھر خریدا ہے اور اسکے لئے باقاعدہ ایک بیع نامہ لکھ کر لوگوں کی گواہی بھی درج کی ہے ۔تو شریح نے عرض کی :اے امیر المومنین ۔جی ہاں: ایسا ہی ہے ۔تو آپ نے ان کی طرف غصہ بھری نظر وں سے دیکھ کرکہا ۔اے شریح عنقریب تمہارے پاس ایسا شخص آنے والا ہے جو نہ تمہارے اس بیع نامہ کو دیکھے گا اور نہ گواہوں کے بارے
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۲۲۶۔
میں تم سے کچھ سوال کرے گا اور وہ تمہیں اس گھر سے نکال کر تن تنہا تمہاری قبر کے حوالے کردیگا لہٰذا ۔ اے شریح۔کہیں ایسا نہ ہوکہ تم نے اس گھر کو اپنے مال سے نہ خریدا ہو اور ناجائز طریقے سے اسکے دام ادا کئے ہوں۔اگر ایسا ہواتو تم دنیا اورآخرت دونوں جگہ گھاٹے میں ہو ۔کاش تم یہ گھر خریدنے سے پہلے میرے پاس آجاتے تو میں تمہارے لئے ایک دستاویز تحریر کردیتا تو تم ایک درہم میں بھی یہ گھر نہ خریدتے ۔
میں اسکی دستاویز اس طرح لکھتا :
یہ وہ مکان ہے جسے ایک بندئہ ذلیل نے اس مرنے والے سے خریداہے جسے کوچ کے لئے آمادہ کردیا گیا ہے ۔یہ مکان پر فریب دنیا میں واقع ہے جہاں فنا ہونے والوں کی بستی ہے اور ہلاک ہونے والوں کا علاقہ ہے ۔اس مکان کے حدود اربعہ یہ ہیں ۔
ایک حد اسباب آفات کی طرف ہے اور دوسری اسباب مصائب سے ملتی ہے تیسری حد ہلاک کردینے والی خواہشات کی طرف ہے اور چوتھی گمراہ کرنے والے شیطان کی طرف اور اسی طرف سے گھر کا دروازہ کھلتا ہے ۔
اس مکان کو امیدوں کے فریب خوردہ نے اجل کے راہ گیر سے خریدا ہے جس کے ذریعہ قناعت کی عزت سے نکل کر طلب وخواہش کی ذلت میں داخل ہوگیا ہے ۔اب اگر اس خریدار کو اس سودے میں کوئی خسارہ ہوتو یہ اس ذات کی ذمہ داری ہے جو بادشاہوں کے جسموں کو تہ وبالا کرنے والا، جابروں کی جان لینے والا،فرعونوں کی سلطنت کوتباہ کردینے والا،کسریٰ وقیصر ،تبع وحمیر اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے والوں،مستحکم عمارتیں بناکر انھیں سجانے والوں،ان میں بہترین فرش بچھانے والوں اور اولاد کے خیال سے ذخیرہ کرنے والوں اور جاگیریں بنانے والوں کو فناکے گھاٹ اتار دینے والا ہے ۔کہ ان سب کو قیامت کے میدان حساب اور منزل ثواب و عذاب میں حاضر کردے جب حق وباطل کا حتمی فیصلہ ہوگا اور اہل باطل یقیناخسارہ میں ہونگے۔
اس سودے پر اس عقل نے گواہی دی ہے جو خواہشات کی قید سے آزاد اور دنیا کی وابستگیوں سے محفوظ ہے ''( ۱ )
دنیا کے بارے میںآپ نے یہ بھی فرمایا ہے :
یاد رکھو:اس دنیا کا سرچشمہ گندہ اور اسکا گھاٹ گندھلاہے ،اسکا منظر خوبصورت دکھائی دیتا ہے لیکن اندر کے حالات انتہائی درجہ خطرناک ہیں ،یہ ایک فنا ہوجانے والا فریب، بجھ جانے والی روشنی ،ڈھل جانے والا سایہ اور ایک گر جانے والا ستون ہے ۔جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہوجاتا ہے اور اسے برا سمجھنے والا مطمئن ہوجاتا ہے تو یہ اچانک اپنے پیروں کو پٹکنے لگتی ہے اور عاشق کو اپنے جال میں گرفتار کرلیتی ہے اور پھر اپنے تیروں کا نشانہ بنالیتی ہے انسان کی گردن میں موت کا پھندہ ڈال دیتی ہے اور اسے کھینچ کر قبر کی تنگی اور وحشت کی منزل تک لے جاتی ہے جہاں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے اور اپنے اعمال کا معاوضہ حاصل کرلیتا ہے اور یوں ہی یہ سلسلہ نسلوں میں چلتا رہتا ہے کہ اولاد بزرگوں کی جگہ پر آجاتی ہے نہ موت چیرہ دستیوں سے بازآتی ہے اور نہ آنے والے افراد گناہوں سے باز آتے ہیں پرانے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اپنی آخری منزل انتہا ء وفنا کی طرف بڑھتے رہتے ہیں ۔( ۲ )
دنیا کے بارے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے :
''میں اس دار دنیاکے بارے میں کیا بیان کروں جسکی ابتداء رنج وغم اور انتہا فنا ونابودی ہے
____________________
(۱)نہج البلاغہ مکتوب ۳۔
(۲)نہج البلاغہ خطبہ۸۳۔
اسکے حلال میں حساب ہے اور حرام میںعذاب،جو اس میں غنی ہوجائے وہ آزمائشوں میں مبتلا ہوجائے ۔ اور جو فقیر ہوجائے وہ رنجیدہ و افسردہ ہوجائے ۔جو اسکی طرف دوڑلگائے اسکے ہاتھ سے نکل جائے اور جو منھ پھیر کر بیٹھ رہے اسکے پاس حاضر ہوجائے جو اسکو ذریعہ بناکر آگے دیکھے اسے بینابنادے اور جو اسے منظور نظر بنالے اسے اندھا بنادے ''( ۱ )
اپنے دور خلافت سے پہلے آپ نے جناب سلمان فارسی کو اپنے ایک خط میں یہ بھی تحریر فرمایا تھا ۔اما بعد :اس دنیا کی مثال صرف اس سانپ جیسی ہے جو چھونے میں انتہائی نرم ہوتا ہے لیکن اسکا زہر انتہائی قاتل ہوتا ہے اس میں جو چیز اچھی لگے اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کرو۔کہ اس میں سے ساتھ جانے والا بہت کم ہے ۔اسکے ہم وغم کو اپنے سے دور رکھو کہ اس سے جدا ہونا یقینی ہے اور اسکے حالات بدلتے ہی رہتے ہیں ۔اس سے جس وقت زیادہ انس محسوس کرو اس وقت زیادہ ہوشیار رہو کہ اسکا ساتھی جب بھی کسی خوشی کی طرف سے مطمئن ہوجاتا ہے تو یہ اسے کسی ناخوشگواری کے حوالے کردیتی ہے اور انس سے نکال کرو حشت کے حالات تک پہونچادیتی ہے ۔والسلام ''( ۲ )
دنیا کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایاہے :
آگاہ ہوجائو دنیا جارہی ہے اور اس نے اپنی رخصت کا اعلان کردیا ہے اور اسکی جانی پہچانی چیزیں بھی اجنبی ہوگئی ہیں وہ تیزی سے منھ پھیر رہی ہے اور اپنے باشندوں کو فنا کی طرف لی جارہی ہے اور اپنے ہمسایوں کو موت کی طرف ڈھکیل رہی ہے اسکی شیرینی تلخ ہوچکی ہے اور اسکی صفائی ہوچکی ہے اب اس میں صرف اتنا ہی پانی باقی رہ گیا ہے جو، تہ میں بچاہوا ہے اور وہ نپا تلا گھونٹ رہ گیا ہے جسے پیاسا پی بھی لے تو اسکی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے لہٰذا بند گان خدا اب اس دنیا سے کوچ کرنے کا ارادہ کرلو جسکے رہنے والوں کا مقدر زوال ہے اور خبردار: تم پر خواہشات غالب نہ آنے پائیں اور اس
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۸۲۔
(۲)نہج البلاغہ مکتوب۶۸۔
مختصر مدت کو طویل نہ سمجھ لینا''( ۱ )
دنیا کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایاہے :
میں تم لوگوں کو دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ شیریں اور شاداب ہے لیکن خواہشات میں گھری ہو ئی ہے اپنی جلد مل جانے والی نعمتوں کی بنا پر محبوب بن جاتی ہے اور تھوڑی سی زینت سے خوبصورت بن جاتی ہے یہ امیدوں سے آراستہ ہے اور دھوکہ سے مزین ہے۔نہ اس کی خو شی دائمی ہے اور نہ اس کی مصیبت سے کو ئی محفوظ رہنے والا ہے یہ دھوکہ باز ،نقصان رساں ،بدل جانے والی ،فنا ہو جانے والی ،زوال پذیراور ہلاک ہو جانے والی ہے ۔یہ لوگوں کو کھا بھی جاتی ہے اور مٹا بھی دیتی ہے ۔
جب اسکی طرف رغبت رکھنے والوں اور اس سے خوش ہو جانے والوںکی خواہشات انتہاء کو پہونچ جاتی ہے تویہ بالکل پروردگار کے اس ارشاد کے مطابق ہو جاتی ہے :
(کمائٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبَات الأرض فأصبح هشیماً تذروه الریاح وکان ﷲ علیٰ کل شیئٍ مقتدرا )( ۲ )
''یعنی دنیا کی مثال اس پانی کے جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اسکے ذریعہ زمین کے سبزہ مخلوط(ہوکر روئیدہ)ہوئے وہ سبزہ سوکھ کر ایسا تنکا ہوگیا جسے ہوائیں اڑالے جاتی ہیں اور اللہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے ''
اس دنیا میں کو ئی شخص خوش نہیں ہوا ہے مگر یہ کہ اسے بعد میں آنسو بہانا پڑے اور کوئی اس کی خوشی کو آتے نہیں دیکھتا ہے مگر یہ کہ وہ مصیبت میں ڈال کر پیٹھ دکھلا دیتی ہے اور کہیں راحت وآرام کی ہلکی بارش نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ بلائوں کا دو گڑا گرنے لگتا ہے ۔اس کی شان ہی یہ ہے کہ اگر صبح کو کسی طرف سے بدلہ لینے آتی ہے تو شام ہوتے ہوتے انجان بن جاتی ہے اور اگر ایک طرف سے
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۵۲۔
(۲)سورئہ کہف آیت۴۵۔
شیریںاور خوش گوار نظر آتی ہے تو دوسرے رُخ سے تلخ اور بلا خیز ہوتی ہے ۔کوئی انسان اس کی تازگی سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس کے پے درپے مصائب کی بنا پر رنج وتعب کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی شخص شام کو امن وامان کے پروں پر نہیں رہتا ہے مگر یہ کہ صبح ہوتے ہوتے خوف کے بالوں پر لاد دیا جاتا ہے ۔یہ دنیا دھو کہ باز ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب دھو کہ ہے ۔یہ فانی ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والاہے ۔اس کے کسی زادراہ میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے تقویٰ کے ۔ اس میں سے جوکم حاصل کرتا ہے اسی کو راحت زیادہ نصیب ہوتی ہے اور جو زیادہ کے چکّر میں پڑجاتا ہے اس کے مہلکات بھی زیادہ ہوجاتے ہیں اور یہ بہت جلد اس سے الگ ہوجاتی ہے ۔کتنے اس پراعتبار کرنے والے ہیں جنہیں اچانک مصیبتوں میں ڈال دیا گیا اور کتنے اس پر اطمینان کرنے والے ہیں جنہیں ہلاک کردیا گیا اور کتنے صاحبان حیثیت تھے جنہیں ذلیل بنا دیاگیا اور کتنے اکڑنے والے تھے جنہیں حقارت کے ساتھ پلٹا دیاگیا ۔اس کی بادشاہی پلٹا کھانے والی ۔اس کا عیش مکدّر ۔اس کا شیریں شور ۔اس کا میٹھا کڑوا ۔اس کی غذاز ہر آلود اور اس کے اسباب سب بوسیدہ ہیں ۔اس کازندہ معرض ہلاکت میں ہے اور اس کا صحت مندبیمار یوں کی زدپر ہے ۔اس کا ملک چھننے والا ہے اور اس کا صاحب عزت مغلوب ہونے والا ہے ۔اس کا مالدار بدبختیوں کا شکار ہونے والا ہے اور اس کا ہمسا یہ لُٹنے والا ہے ۔کیا تم انھیں کے گھر وں میں نہیں ہو جوتم سے پہلے طویل عمر ،پائید ارآثار اور دوررس امیدوں والے تھے ۔بے پناہ سامان مہیا کیا ،بڑے بڑے لشکر تیار کئے اور جی بھر کر دنیا کی پر ستش کی اور اسے ہر چیز پر مقدم رکھا لیکن اس کے بعد یوں روانہ ہو گئے کہ نہ منزل تک پہونچا نے والا زادراہ ساتھ تھا اور نہ راستہ طے کرانے والی سواری ۔کیا تم تک کوئی خبر پہو نچی ہے کہ اس دنیا نے ان کو بچانے کے لئے کوئی فدیہ پیش کیا ہو یا ان کی کوئی مدد کی ہو یا ان کے ساتھ اچھا وقت گزاراہو ۔؟بلکہ اُس نے تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ،آفتوں سے اُنھیں عاجز ودر ماندہ کردیا اور لَوٹ لَو ٹ کرآنے والی زحمتوں سے انھیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ناک کے بل اُنھیں خاک پر پچھاڑ دیا اور اپنے گھروں سے کچُل ڈالا ،اور ان کے خلاف زمانہ کے حوادث کا ہاتھ بٹا یا ۔تم نے تو دیکھا ہے کہ جو ذرا دُنیا کی طرف جھکا اور اسے اختیار کیا اور اس سے لپٹا ،تو اس نے (اپنے تیّور بدل کر ان سے کیسی )ا جنبیّت اختیار کرلی ۔
یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے جُدا ہوکر چل دئیے ،اور اس نے انھیں بھُوک کے سوا کچھ زادِراہ نہ دیا ،اور ایک تنگ جگہ کے سوا کوئی ٹھہر نے کا سامان نہ کیا ،اور سواگھُپ اندھیرے کے کوئی روشنی نہ دی اور ندامت کے سوا کوئی نتیجہ نہ دیا ،تو کیا تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو،یا اسی پر مطمئن ہو گئے ہو یا اسی پر مرے جا رہے ہو ؟جو دنیا پر بے اعتماد نہ رہے اور اس میں بے خوف و خطر ہو کر رہے اس کے لئے یہ بہت برا گھر ہے ۔جان لو اور حقیقت میں تم جانتے ہی ہو ،کہ (ایک نہ ایک دِن)تمھیں دنیا کو چھوڑنا ہے ،اور یہاں سے کوچ کرنا ہے ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے کہ ''ہم سے زیادہ قوت و طاقت میں کون ہے ۔''انھیں لاد کر قبروں تک پہونچایا گیا مگر اس طرح نہیں کہ انھیں سوار سمجھا جائے انھیں قبروں میں اتار دیا گیا ،مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے پتھروں سے اُن کی قبریں چن دی گئیں ،اور خاک کے کفن ان پر ڈال دئے گئے اور گلی سڑی ہڈیوں کو ان کا ہمسایہ بنا دیا گیا ہے ۔وہ ایسے ہمسایہ ہیں جو پکارنے والے کو جواب نہیں دیتے ہیں اور نہ زیادتیوں کو روک سکتے ہیں اور نہ رونے دھونے والوں کی پروا کرتے ہیں ۔اگر بادل (جھوم کر )ان پر برسیں ،تو خوش نہیں ہوتے اور قحط آئے تو ان پر مایوسی نہیں چھا جاتی ۔وہ ایک جگہ ہیں ،مگر الگ الگ ،وہ آپس میں ہمسایہ ہیں مگر دور دور ،پاس پاس ہیں مگر میل ملاقات نہیں،قریب قریب ہیں مگر ایک دوسرے کے پاس نہیں پھٹکتے، وہ بردبار بنے ہوئے بے خبر پڑے ہیں ،ان کے بغض و عناد ختم ہو گئے اور کینے مٹ گئے ۔نہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ ہے ،نہ کسی تکلیف کے دور کرنے کی توقع ہے انھوں نے زمین کے اوپر کا حصہ اندر کے حصہ سے اور کشادگی اور وسعت تنگی سے
،اور گھر بار پردیس سے اور روشنی اندھیرے سے بدل لی ہے اور جس طرح ننگے پیر اور ننگے بدن پیدا ہوئے تھے ،ویسے ہی زمین میں (پیوند خاک )ہوگئے اور اس دنیا سے صرف عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی اور سدا رہنے والے گھر کی طرف کوچ کر گئے ۔جیسا کہ خداوندقدوس نے فرمایا ہے :
(کما بدأنا أول خلق نعیده وعداًعلینا انّا کنا فاعلین )( ۱ )
''جس طرح نے ہم نے مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دو بارہ پیدا کریں گے ۔ اس وعدہ کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کرکے رہیں گے ''
آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:
( واُحذّرکم الدنیا فانهامنزل قُلعة،ولیست بدارنُجعة،قد تزیّنت بغرورها، وغرّت بزینتها،دارهانت علیٰ ربها،فخلط حلالهابحرامها،وخیرهابشرها، وحیاتهابموتها،وحلوها بمرّها،لم یصفّهاﷲ تعالیٰ لاولیائه،ولم یَضنّ بهاعلیٰ أعدائه ) ( ۲ )
''میں تمہیں اس دنیا سے ہو شیار کر رہا ہوں کہ یہ کوچ کی جگہ ہے ۔آب ودانہ کی منزل نہیں ہے ۔یہ اپنے دھوکے ہی سے آراستہ ہوگئی ہے اور اپنی آرائش ہی سے دھو کا دیتی ہے ۔اس کا گھر پروردگار کی نگاہ میں با لکل بے ارزش ہے اسی لئے اس نے اس کے حلال کے ساتھ حرام ۔خیر کے ساتھ شر، زندگی کے ساتھ موت اور شیریں کے ساتھ تلخ کو رکھ دیاہے اور نہ اسے اپنے اولیاء کے لئے مخصوص کیا ہے اور نہ اپنے دشمنوں کو اس سے محروم رکھا ہے ۔اس کا خیر بہت کم ہے اور اس کا شر ہر وقت حاضر ہے ۔اس کا جمع کیا ہو ا ختم ہوجانے والا ہے اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے اور اس کے آباد کو ایک دن خراب ہوجانا ہے ۔بھلا اُس گھر میں کیا خوبی ہے جوکمز ور عمارت کی طرح گرجائے اور اس عمر میں کیابھلائی ہے جو زادراہ کی طرح ختم ہوجائے اور اس زندگی میں کیا حسن ہے جو چلتے پھرتے تمام ہوجائے ۔
دیکھو اپنے مطلوبہ امور میں فرائض الٰہیہ کو بھی شامل کرلو اور اسی سے اس کے حق کے ادا
____________________
(۱) نہج البلاغہ خطبہ ۱۱۱،آیت ۱۰۴ ازسورئہ انبیائ۔
(۲)نہج البلاغہ خطبہ۱۱۳۔
کرنے کی توفیق کا مطالبہ کرواپنے کانوں کو موت کی آواز سنادوقبل اسکے کہ تمہیں بلالیا جائے ''
دنیا کے سلسلہ میں ہی فرماتے ہیں :
(۔۔۔عبادﷲاُوصیکم بالرفض لهذه الدنیاالتارکة لکم وان لم تحبوا ترکها،والمبلیة لأجسامکم وان کنتم تحبون تجدیدها،فانّمامثلکم ومثلهاکسَفْرٍسلکواسبیلاً فکأنّهم قد قطعوه ۔۔۔)( ۱ )
''بندگانِ خدا !میں تمھیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ دو جو تمہیں بہر حال چھوڑنے والی ہے چاہے تم اسکی جدائی کو پسند نہ کرو۔وہ تمہارے جسم کو بہرحال بوسیدہ کردے گی تم لاکھ اس کی تازگی کی خواہش کرو ۔تمہاری اور اسکی مثال ان مسافروں جیسی ہے جو کسی راستہ پر چلے اور گویا کہ منزل تک پہونچ گئے ۔کسی نشان راہ کا ارادہ کیا اور گویا کہ اسے حاصل کرلیا اور کتنا تھوڑا و قفہ ہوتا ہے اس گھوڑا دوڑانے والے کے لئے جو دوڑاتے ہی مقصد تک پہونچ جائے ۔اس شخص کی بقا ہی کیا ہے جس کا ایک دن مقرر ہو جس سے آگے نہ بڑھ سکے اور پھر موت تیز رفتاری سے اسے ہنکا کرلے جارہی ہو یہانتک کہ بادل ناخواستہ دنیا کو چھوڑدے ۔خبردار دنیا کی عزت اور اسکی سربلندی میں مقابلہ نہ کرنا اور اسکی زینت و نعمت کو پسند نہ کرنا اور اسکی دشواری اور پریشانی سے رنجیدہ نہ ہونا کہ اسکی عزت وسربلندی ختم ہوجانے والی ہے اور اسکی زنیت و نعمت کو زوال آجانے والا ہے اوراسکی تنگی اور سختی بہرحال ختم ہوجانے والی ہے ۔یہاں ہر مدت کی ایک انتہا ہے اور ہر زندہ کے لئے فنا ہے ۔کیا تمہارے لئے گذشتہ لوگوں کے آثار میں سامان تنبیہ نہیں ہے ؟اور کیا آباء واجداد کی داستانوں میں بصیرت وعبرت نہیں ہے ؟اگر تمہارے پاس عقل ہے!کیا تم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جانے والے پلٹ کر نہیں آتے ہیں اور بعد میں آنے والے رہ نہیں جاتے ہیں ؟کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اہل دنیا
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۹۹۔
مختلف حالات میںصبح وشام کرتے ہیں ۔کوئی مردہ ہے جس پر گریہ ہو رہا ہے اور کوئی زندہ ہے تو اسے پرسہ دیاجارہا ہے ۔ ایک بستر پر کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو زمانہ اس سے غافل نہیں اور اس طرح جانے والوں کے نقش قدم پر رہ جانے والے چلے جارہے ہیں ۔آگاہ ہوجائو کہ ابھی موقع ہے اسے یاد کرو جو لذتوں کو فنا کردینے والی ۔خواہشات کو مکدر کردینے والی اور امیدوں کو قطع کردینے والی ہے ایسے اوقات میں جب برے اعمال کا ارتکاب کر رہے ہو اور ﷲسے مدد مانگو تاکہ اس کے واجب حق کو ادا کردو اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو جن کا شمار کرنا ناممکن ہے ''
یہ زندگانی دنیا کا پہلا رخ ہے چنانچہ دنیا کے اس چہرے کی نشاندہی کرنے کے لئے ہم نے روایات کو اسی لئے ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ دنیا کے باطن کو چھوڑ کراسکے ظاہر پر ہی ٹھہرجاتے ہیں اور ان کی نظر یں باطن تک نہیں پہونچ پاتیں ۔شاید ہمیں انہیں روایات میں ایسے اشارے مل جائیں جن کے سہارے ہم ظاہر دنیا سے نکل کر اسکے باطن تک پہونچ جائیں ۔
ب۔دنیا کاظاہری رخ(روپ)
دنیاوی زندگی کا ظاہری روپ بے حد پر فریب ہے کیونکہ جسکے پاس چشم بصیرت نہ ہو اسکو یہ زندگانی دنیا دھوکے میں مبتلا کرکے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور پھراسے آرزووں ،خواہشات ، فریب اور لہوولعب کے حوالے کردیتی ہے ۔جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
(وما الحیاة الدنیا الا لعب ولهو )( ۱ )
''اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل تماشہ ہے ''
(ما هذه الحیاة الدنیا الا لهوولعب )( ۲ )
____________________
(۱)سورئہ انعام آیت ۳۲۔
(۲)سورئہ عنکبوت آیت ۶۴۔
''اور یہ زندگانی دنیا ایک کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں ہے ''
(انماالحیاة الدنیالعب ولهووزینة وتفاخر بینکم )( ۱ )
''یاد رکھو کہ زندگانی دنیا صرف ایک کھیل تماشہ ،آرائش باہمی فخرومباہات اور اموال واولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے ''
خداوند عالم نے دنیا کے جس رخ کو لہو ولعب قرار دیا ہے وہ اسکا ظاہری رخ ہے ۔اور لہو ولعب سنجیدگی اور متانت کے مقابلہ میں بولاجاتا ہے ۔۔۔
البتہ انسان اسی وقت لہو ولعب میں گرفتار ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا کے ظاہری روپ پر نظر رکھے اور سنجیدگی و متانت سے دو ر رہے چنانچہ اگر وہ دنیا کے ظاہرکے بجائے اسکے باطن پر توجہ رکھے تو لہو ولعب (کھیل کود)سے بالکل دور ہوکر زاہد وپارسا بن جائیگا اور دنیا کے دوسرے معاملات میں الجھنے کے بجائے اسے صرف اپنے نفس کی فکر لاحق رہے گی۔کیونکہ دنیا''لُماظة''ہے ۔
مولائے کائنات فرماتے ہیں :
(ألا مَن یدع هذه اللُّماظة )( ۲ )
''کون ہے جو اس لماظہ کو چھوڑ دے ''لماظہ منھ کے اندر بچی ہوئی غذا کو کہا جاتا ہے
حضرت علی :
(اُحذّرکم الدنیا فانهاحلوة خضرة،حُفّت بالشهوات )( ۳ )
''میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ یہ ایسی شیرین وسرسبز ہے جوشہوتوں سے گھری ہوئی ہے ''
____________________
(۱)سورئہ حدید آیت ۲۰۔
(۲)بحارالانوار ج۷۳ص ۱۳۳۔
(۳)بحارالانوار ج ۷۳ص۹۶۔
دنیاوی زندگی کے ظاہر اور باطن کا موازنہ
قرآن کریم میں دنیاوی زندگی کے دونوں رخ (ظاہر وباطن )کا بہت ہی حسین موازنہ پیش کیا گیا ہے نمونہ کے طورپر چند آیات ملاحظہ فرمائیں :
۱۔( انّمامثل الحیاةالدنیاکمائٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ممایأکل الناس والانعام حتیٰ اذا أخذت الارض زُخرفها وازّیّنت وظنّ أهلها أنّهم قادرون علیها أتاها أمرنا لیلاً أونهاراً فجعلناها حصیداً کأن لم تغن بالامس کذٰلک نفصّل الآیات لقومٍ یتفکّرون ) ( ۱ )
''زندگانی دنیا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا پھر اس سے مل کر زمین سے نباتات برآمد ہوئیں جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے سبز ہ زارسے اپنے کو آراستہ کرلیا اور مالکوں نے خیال کرنا شروع کردیا کہ اب ہم اس زمین کے صاحب اختیار ہیں تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت آگیا اور ہم نے اسے بالکل کٹا ہواکھیت بناد یا گویا اس میں کل کچھ تھا ہی نہیں ہم اس طرح اپنی آیتوں کو مفصل طریقہ سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لئے جو صاحب فکر ونظر ہے ''
اس آیۂ کریمہ میں زندگانی دنیا ،اسکی زینت اور آرائشوں اور اسکی تباہی و بربادی اور اس میں اچانک رو نما ہو نے والی تبدیلیوں کی عکاسی مو جود ہے ۔
چنانچہ دنیا کو اس بارش کے پانی سے تشبیہ دی گئی ہے جو آسمان سے زمین پر برستا ہے اور اس سے زمین کے نباتات ملتے ہیں تو ان نباتات میں نمو پیدا ہوتا ہے اور وہ انسانوں اور حیوانوں کی غذانیززمین کی زینت بنتے ہیں ۔یہاں تک کہ جب زمین اپنی آرائشوں اور زینتوں سے آراستہ
____________________
(۱)سورئہ یونس آیت ۲۴۔
ہوجاتی ہے۔۔۔تو اچانک یہ حکم الٰہی کسی بجلی، آندھی(ہوا)وغیرہ کی شکل میں اسکی طرف نازل ہوجاتا ہے اور اسے بالکل ویرانے اور خرابے میں تبدیل کردیتا ہے جیسے کل تک وہ آباد ،سرسبز و شاداب ہی نہ تھی یہ دنیا کے ظاہری اور باطنی دونوں چہروںکی بہترین عکاسی ہے کہ وہ اگر چہ سر سبزو شاداب ، پُرفریب ، برانگیختہ کرنے والی،پرکشش (جالب نظر)دلوں کے اندر خواہشات کو بھڑکانے والی ہے لیکن جب دل اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ہیں تواچانک حکم الٰہی نازل ہوجاتا ہے اور اسے کھنڈر اور بنجر بناڈالتا ہے جس سے لوگوں کو کراہیت محسوس ہو تی ہے ۔
اس سورہ کا پہلا حصہ دنیا کے ظاہری چہرہ کی وضاحت کر رہا ہے جو انسان کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا کردیتا ہے جبکہ دوسرا حصہ وعظ و نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے ۔جو کہ دنیا کا باطنی رخ ہے ۔
۲۔:( انّاجعلنا ماعلیٰ الارض زینةً لهالنبلوهم أیّهم أحسن عملاً ) ( ۱ )
''بیشک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زینت قرار دیدیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے ''
دنیا یقینا ایک زینت ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہی زینت و آرائش انسانی خواہشات کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے مگر ان آرائشوں کی کوکھ میں مختلف قسم کے امتحانات بلائیں اور آزما ئشیںپو شیدہ رہتی ہیں جن کے اندر انسان کی تنزلی کے خطرات چھپے رہتے ہیں اور یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے کسی شکار کو پکڑنے کے لئے چارا ڈالا جاتا ہے ۔
۳۔( اعلموا أنماالحیاةالدنیا لعب ولهووزینة وتفاخربینکم وتکاثرفی الاموال والاولادکمثل غیث أعجب الکفّارنبا ته ثم یهیج فتراه )
____________________
(۱)سورئہ کہف آیت ۷۔
( مصفرّا ثم یکونحطاماً وفی الآخرةعذاب شدیدومغفرةمن ﷲ ورضوان وماالحیاة الدنیاالامتاع الغرور ) ( ۱ )
''یاد رکھو کہ زندگانی دنیا صرف ایک کھیل تماشہ ،آرائش ،باہمی فخرومباہات،اور اموال واولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے اور بس ۔جیسے کوئی بارش ہو جسکی قوت نامیہ کسان کو خوش کردے اور اسکے بعد وہ کھیتی خشک ہوجائے پھر تم اسے زرد دیکھو اور آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہوجائے اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضائے الٰہی بھی ہے اور زندگانی دنیا تو بس ایک دھوکہ کا سرمایہ ہے اور کچھ نہیں ہے ''
دنیا کے بارے میں نگاہوں کے مختلف زاوئے
در حقیقت دنیا کو متعدد زاویوںسے دیکھنے کی وجہ سے ہی دنیا کے مختلف رخ دکھائی دیتے ہیں اسی لئے زاویہ نگاہ تبدیل ہوتے ہی دنیا کا رخ بھی تبدیل ہوجاتا ہے ورنہ دنیا تو ایک ہی حقیقت کا نام ہے مگر لوگ اسکی طرف دو رخ سے نظر کرتے ہیں ۔
کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا کو پر غرور اور پرفریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں جبکہ بعض حضرات اسے عبرت کی نگاہوں سے دیکھاکرتے ہیں ان دونوں نگاہوںکے زاویوںمیں ایک انداز نگا ہ سطحی ہے جو دنیا کی ظاہری سطح پر رکا رہتا ہے اور انسان کو شہوت وغرور (فریب)میں مبتلا کردیتا ہے جبکہ دوسرا انداز نظر اتنا گہرا ہے کہ وہ دنیا کے باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے لہٰذا یہ اندازنظر رکھنے والے حضرات اس دنیا سے دوری اور زہد اختیار کرتے ہیں مختصر یہ کہ اس مسئلہ کا دارو مدار دنیا کے بارے میں ہمارے زاویہ نگاہ اور انداز فکر پر منحصر ہے ۔لہٰذا دنیا کے معاملات کو صحیح کرنے کے لئے سب سے پہلے اسکے بارے میں انسان کا انداز فکر صحیح ہوناچاہئیے جس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ دنیا کے بارے میں اپنا زاویۂ
____________________
(۱)سورئہ حدیدآیت ۲۰۔
نگاہ صحیح کرے اسکے بعد وہ اسکو جس نگاہ سے دیکھے گا اسی اعتبار سے اسکے ساتھ پیش آئے گا ۔
لہٰذا جو حضرات دنیا کو پر فریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں انہیں دنیا دھوکہ میں ڈال دیتی ہے اور خواہشات میں مبتلا کردیتی ہے اور ان کے لئے یہ زندگانی ایک کھیل تماشہ بن کر رہ جاتی ہے جسکی طرف قرآن مجید نے متوجہ کیا ہے ۔اور جو لوگ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اعمال میں صداقت اور سنجیدگی کا خیال رکھتے ہیں اور آخرت کا واقعی احساس انہیں دنیا کے کھیل تماشہ سے دور کردیتا ہے ۔
مولائے کائنات کے کلمات میں دنیا کے بارے میں موجود مختلف نگاہوں کی طرف واضح اشارے موجود ہیںجن میں سے ہم یہاں بعض کا تذکرہ کر رہے ہیں:
(کا ن لی فیما مضیٰ أخ فی ﷲ،وکان یعظّمه فی عینی صغرالدنیا فی عینه )( ۱ )
''گذشتہ زمانہ میں میرا ایک بھائی تھا جس کی عظمت میری نگاہوں میں اس لئے تھی کہ دنیا اسکی نگاہ میں حقیر تھی ''
دنیا کی توصیف میں آپ فرماتے ہیں :
(ما أصف من دارأوّلهاعنائ،وآخرها فنائ، فی حلالهاحساب،وفی حرامهاعقاب،من استغنیٰ فیها فُتن،ومن افتقرفیهاحزن )( ۲ )
''میں اس دنیا کے بارے میں کیا کہوں جسکی ابتدا رنج وغم اور انتہا فناونیستی ہے اسکے حلال میں حساب اور حرام میں عقاب ہے۔جو اس میںغنی ہوجاتاہے وہ آزمائشوں میں مبتلا ہوجاتاہے اور جو فقیر ہوجاتاہے وہ رنجیدہ و افسردہ ہوجاتاہے ''
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت۲۸۹۔
(۲)نہج البلاغہ خطبہ۸۲۔
یہی رخ دنیا کا باطنی رخ اور وہ دقت نظر ہے جو دنیا کے باطن میں جھانک کردیکھ لیتی ہے ۔
پھر آپ فرماتے ہیں :
(من ساعاهافا تته،ومن قعدعنهاواتته )( ۱ )
''جو اسکی طرف دوڑلگاتاہے اسکے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور جو منھ پھیر کر بیٹھ رہے اسکے پاس حاضر ہوجاتی ہے ''
دنیا سے انسانی لگائو کے بارے میں خداوند عالم کی یہ ایک سنت ہے جس میں کبھی بھی خلل یا تغیر پیدا نہیں ہوسکتا ہے چنانچہ جو شخص دنیا کی طرف دوڑلگائے گا اور اسکے لئے سعی کریگا اور اسکی قربت اختیار کریگا تو وہ اسے تھکاڈالے گی۔اور اسکی طمع کی وجہ سے اسکی نگاہیں مسلسل اسکی طرف اٹھتی رہیں گی۔چنانچہ اسے جب بھی کوئی رزق نصیب ہوگا تو اسے اس سے آگے کی فکر لاحق ہوجائیگی۔اور وہ اسکے لئے کوشش شروع کردیگا مختصر یہ کہ وہ دنیا کا ساتھی ہے اور اسکے پیچھے دوڑلگاتا رہے گا مگر اسے دنیا میں اسکا مقصد ملنے والا نہیں ہے ۔
البتہ جو دنیا کی تلاش اور طلب میں صبروحوصلہ سے کام لیکر میانہ روی اختیار کریگا تو دنیا خود اسکے قدموں میں آکر اسکی اطاعت کرے گی اور وہ بآسانی اپنی آرزو تک پہونچ جائے گا۔
پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں:
(من أبصربهابصّرته،ومن أبصرالیها أعمته )( ۲ )
''جو اسکو ذریعہ بنا کر آگے دیکھتارہے اسے بینابنادیتی ہے اور جو اسکو منظور نظر بنالیتاہے اسے اندھا کردیتی ہے ''
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ۸۲۔
(۲)گذشتہ حوالہ۔
سید رضی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی یہ تشریح فرمائی ہے: کہ اگر کوئی شخص حضرت کے اس ارشاد گرامی (من ابصربھا بصرتہ)میں غور وفکر کرے تو عجیب و غریب معانی اور دور رس حقائق کا ادراک کرلے گا جن کی بلندیوں اور گہرائیوں کا ادراک ممکن نہیں ہے ۔
مولائے کائنات نے دنیا کے بارے میں نگاہ کے ان دونوں زاویوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں سے ایک یہ ہے ''کہ دنیا کو ذریعہ بناکر آگے دیکھا جائے ''اس نگاہ میں عبرت پائی جاتی ہے اور دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ انسان دنیا کو اپنا منظور نظر اور اصل مقصد بنالے اس نگاہ کا نتیجہ دھوکہ اور فریب ہے جسکی وضاحت کچھ اس طرح ہے :
یہ دنیا کبھی انسان کے لئے ایک ایسا آئینہ بن جاتی ہے جس میں وہ مختلف تصویریں دیکھتا ہے اور کبھی اسکی نظر خود اسی دنیا پر لگی رہتی ہے ۔
چنانچہ جب دنیا انسان کے لئے ایک آئینہ کی مانند ہوتی ہے جس میں جاہلیت کے تمدن اور زمین پر فساد برپا کرنے والے ان متکبرین کا چہرہ بخوبی دیکھ لیتا ہے جن کو خدا نے اپنے عذاب کا مزہ اچھی طرح چکھادیا ۔۔۔تو یہ نگاہ ،عبرت ونصیحت کی نگاہ بن جاتی ہے ۔
لیکن جب دنیا انسان کے لئے کل مقصد حیات کی شکل اختیار کرلے اور وہ ہمیشہ اسی نگاہ سے اسے دیکھتا رہے تو دنیا اسے ہویٰ وہوس اور فتنوں میں مبتلا کرکے اندھا کردیتی ہے اور وہ اسے بہت ہی سر سبز و شیرین دکھائی دیتی ہے۔
اس طرح پہلی نگاہ میں عبرت کا مادہ پایا جاتا ہے اور دوسری نظر میں فتنہ وفریب کا مادہ ہوتا ہے ۔پہلی نگاہ میں فقط بصیرت پائی جاتی ہے جبکہ دوسری نگاہ میںعیاری اور دھوکہ ہے ۔
انہیں جملوں کی شرح کے بارے میں ابن الحدید کا بیان ہے کہ جب میں نے حضرت کے یہ جملات پڑھے تو اسکی تشریح میں یہ دو اشعار کہے :
دنیاک مثل الشمس تدنی ال
یک الضوء لکن دعوةَ المهلکِ
ان أنت أبصرت الیٰ نو ر ها
تَعْشُ و ان تُبصر به تد ر ک
تمہاری دنیا کی مثال اس سورج جیسی ہے جس کی ضیاء تمہارے سامنے ہے لیکن ایک مہلک انداز میں کہ اگر تم اس (نور)کی طرف دیکھو گے تو تمہاری نگاہ میں خیرگی پیدا ہوجائیگی اور اگر اسکے ذریعہ کسی چیز کو دیکھنا چاہو گے تو اسے دیکھ لو گے ۔
اسی زاویہ نگاہ کی بنیاد پر مولائے کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے :
(جعل لکم أسماعاً لتعی ماعناها،أبصاراً لتجلوعن عشاهاوکأن الرشدَ فی احرازدنیا ها )( ۱ )
''اس نے تمہیں کان عطا کئے ہیں تاکہ ضروری باتوں کو سنیں اور آنکھیں دی ہیں تاکہ بے بصری میں روشنی عطا کریں ۔۔۔اور تمہارے لئے ماضی میں گذر جانے والوں کے آثار میں عبرتیں فراہم کردی ہیں ۔۔۔لیکن موت نے انہیں امیدوں کی تکمیل سے پہلے ہی گرفتار کرلیا۔۔۔انہوں نے بدن کی سلامتی کے وقت کوئی تیاری نہیں کی تھی اور ابتدائی اوقات میں کوئی عبرت حاصل نہیں کی تھی ۔۔۔ تو کیا آجتک کبھی اقرباء نے موت کودفع کیا ہے یا فریاد کسی کے کام آئی ہے (ہرگز نہیں )مرنے والے کو قبرستان میں گرفتار کردیا گیا ہے اور تنگی قبر میں تنہاچھوڑدیا گیا ہے اس عالم میں کہ کیڑے مکوڑے اسکی جلد کو پارہ پارہ کررہے ہیں۔۔۔اور آندھیوں نے اسکے آثار کو مٹادیاہے اور روز گار کے حادثات نے نشانات کو محو کردیا ہے ۔۔۔تو کیا تم لوگ انہیں آباء واجداد کی اولاد نہیں ہو اور کیا انہیں کے بھائی بندے نہیں ہو کہ پھر انہیں کے نقش قدم پر چلے جارہے ہو اور انہیں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہو اور انہیں کے راستے پر گامزن ہو؟حقیقت یہ ہے کہ دل اپنا حصہ حاصل کرنے میں سخت ہوگئے ہیں اور راہ ہدایت سے غافل ہوگئے ہیں غلط میدانوں میں قدم جمائے ہوئے ہیں ایسا معلوم
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ۸۳۔
ہوتا ہے کہ اللہ کامخاطب ان کے علاوہ کوئی او ر ہے اور شاید ساری عقلمندی دنیا ہی کے جمع کرلینے میں ہے ''
اس بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے :
(وانما الدنیا منتهیٰ بصرالاعمیٰ،لا یبصرمماوراء ها شیئاً،والبصیر ینفذها بصره،ویعلم أن الدار ورائها،فالبصیرمنها شاخص،والأعمیٰ الیها شاخص،والبصیر منها متزود،والأعمیٰ لهامتزود )( ۱ )
''یہ دنیا اندھے کی بصارت کی آخری منزل ہے جو اسکے ماوراء کچھ نہیں دیکھتا ہے جبکہ صاحب بصیرت اس سے کوچ کرنے والا ہے اور اندھا اسکی طرف کوچ کرنے والا ہے بصیر اس سے زادراہ فراہم کرنے والا ہے اور اندھا اسکے لئے زاد راہ اکٹھاکرنے والاہے''
واقعاً اندھا وہی ہے جس کی نگاہیں دنیا سے آگے نہ دیکھ سکیں اور وہ اس سے وابستہ ہوکر رہ جائے (اس طرح دنیا اندھے کی نگاہ کی آخری منزل ہے )لیکن صاحب بصیرت وہ ہے جسکی نگاہیں ماوراء دنیا کا نظارہ کرلیتی ہیں اور اس کی عاقبت کو دیکھ لیتی ہیں آخرت اسکی نظروں کے سامنے ہے لہٰذا (اسکی نگا ہیں )اور اسکے قدم اس دنیا پر نہیںٹھہرتے بلکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرکے آ گے کی طرف کوچ کرجاتا ہے ۔
ابن ابی الحدید نے اس جملہ کی مذکورہ شرح کے علاوہ ایک اور حسین تشریح کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں ۔دنیا اور مابعد دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا کسی خیالی تاریکی کا تصور کرتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اس تاریکی،کو محسوس کررہا ہے جبکہ وہ واقعاً اسکاا حساس نہیں کرپاتا بلکہ وہ عدم ضیاء ہے (وہاں نور کا وجود نہیں ہے )بالکل اس طرح جیسے کوئی شخص کسی تنگ و تاریک گڑھے میں گھس
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۱۳۳۔
جائے اور تا ریکی کا خیال کرے مگر اسے کچھ نہ دکھائی دے اور اسکی نگاہیںکسی چیز کا مشاہدہ کرتے وقت کام نہیں کرپاتیں مگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تاریکی وظلمت کو دیکھ رہا ہے ۔لیکن جو شخص روشنی میں کسی چیز کو دیکھتا ہے اسکی بصارت (نگاہ)کام کرتی ہے اور وہ واقعاًمحسوسات کو دیکھتا ہے ۔چنانچہ دنیا اور آخرت کی بھی بالکل یہی حالت ہے :کیونکہ اہل دنیا کی نگاہوں کی آخری منزل اور ان کی پہنچ صرف ان کی دنیا تک ہے ۔او ر ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جبکہ واقعاً انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے اور نہ ان کے حواس کسی چیز کے اوپر کام کرتے ہیں ۔ لیکن اہل آخرت کی نگاہیں بہت کارگر ہیں اور انہوں نے آخرت کو باقاعدہ دیکھ لیا ہے لہٰذا دنیا پر ان کی نگاہیں نہیں ٹھہرتی ہیں ،تو در حقیقت یہی حضرات صاحبان بصارت ہیں ''( ۱ )
طرز نگاہ کا صحیح طریقہ کار
جس طرح انسان کے تمام اعمال وحرکات میں کچھ صحیح ہوتے ہیںاور کچھ غلط ۔ اسی طرح کسی چیزکے بارے میں اسکا طرز نگاہ بھی صحیح یا غلط ہوسکتا ہے ۔جیسا کہ قرآن کریم نے رفتار وکردار کے صحیح طریقوں کی تعلیم دیتے ہوئے صحیح طرز نگاہ کی تعلیم ان الفاظ میں دی ہے :
( ولا تمدّنَّ عینیک الیٰ ما متّعنابه أزواجاً منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیه ورزق ربک خیروأبقیٰ ) ( ۲ )
''اور خبر دار ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو جو زندگانی دنیا کی رونق سے مالامال کردیا ہے اسکی طرف آپ نظر اٹھاکر بھی نہ دیکھیں کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ ہے اور آپ کے پروردگار کا رزق
اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پائیدار ہے ''
____________________
(۱)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدیدج۸ص۲۷۶۔
(۲)سورئہ طہ آیت ۱۳۱۔
نظر اٹھاکر دیکھنا بھی کسی چیز کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اس مال ودولت اور رزق کے اوپر پڑتی رہے جو خداوند عالم نے دوسروں کو عنایت فرمائی ہے اس مد نظر (نگاہیں اٹھاکر دیکھنے)میں اپنی حد سے تجاوز کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں ۔گویا انسان کی نگاہیں اپنے پاس موجود خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں سے تجاوز کرکے دوسروں کے دنیاوی راحت وآرام اور نعمتوں کی سمت اٹھتی رہیں اور مسلسل انہیں پر جمی رہیں ۔
حد سے یہ تجاوزہی انسانی مشکلات اور عذاب کا سرچشمہ ہے ۔۔۔کیونکہ جب تک خداوند عالم اسے مال نہ دیگا اسے مسلسل اسکی تمنا رہے گی اور وہ اسکے لئے کوشش کرتا رہے گا۔اور جب خداوند عالم اسے اس نعمت سے نواز دیگا تو پھر وہ ان دوسری نعمتوں کی خواہش اور تمنا شروع کردیگا جو دوسروں کے پاس ہیں اور اسکے پاس نہیں ہیں ۔۔۔اور اس طرح دنیا سے اسکی وابستگی اور اسکے لئے سعی وکوشش میں دوام پیدا ہوجاتا ہے۔( جیسا کہ مولائے کائنات نے ارشادفرمایا ہے )نیزاسکے پیچھے دوڑنے سے عذاب مزید طولانی ہوجاتا ہے اور وہ اپنے آخری مقصد تک نہیں پہونچ پاتا ہے، دنیا کے بارے میں اس طرز نگاہ سے انسا ن کو یاس وحسرت کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آ نے والا نہیں ہے ۔
واضح رہے کہ لوگوں کے پاس موجود نعمتوںپر نگاہیں نہ جمانے اور ان کی طرف توجہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان سعی وکوشش اور محنت و مشقت کرنا ہی چھوڑدے کیونکہ ایک مسلمان ہمیشہ متحرک رہتا ہے ۔مگر لوگوں کے پاس موجود نعمتوں کو دیکھ کر حسرت اورغصہ کے گھونٹ پینے کی وجہ سے نہیں ۔
مختصر یہ کہ: کسی بھی چیز کے بارے میں انسان کی طرز نگاہ اسکے نفس کی سلامتی یا بربادی میں اہم کردار اداکرتاہے ۔کیونکہ کبھی کبھی ایک نظر انسان کی روح کو آلودہ اور گندھلا بنادیتی ہے اور اسے ایک طولانی مصیبت اور عذاب میں مبتلا کردیتی ہے ۔جیسا کہ روایت میں ہے :
(رُبَّ نظرة تورث حسرة )( ۱ )
''کتنی نگاہوں سے حسرت ہی ہاتھ آتی ہے ''
جبکہ کبھی کبھی یہی نگاہ انسان کی استقامت اور استحکام عمل کا سرچشمہ قرار پاتی ہے بیشک اسلام ہمیں''نگاہ ونظر''سے منع نہیں کرتا ہے بلکہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارا زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہئے!
____________________
(۱) وسائل الشیعہ ج۱۴ص۱۳۸۔فروع کافی ج۵ص۵۵۹۔میزان الحکمت ج۱۰۔
نفس کے اوپر طرز نگاہ کے اثرات اورنقوش
محبت یا زہددنیا
انسان اپنی زندگی میں کسی چیز کے بارے میں چاہے جو طرز نگاہ اپنا لے اسکے کچھ نہ کچھ مثبت یا منفی (اچھے یا برے )اثرات ضرور پیدا ہو تے ہیں اور انسان اسی زاویۂ دید کے مطابق اسکی طرف قدم ا ٹھاتا ہے اس طرح انسان دنیا کے بارے میں چاہے جو زاو یہ نگاہ رکھتا ہو یا اسے جس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہو اسکے فکر وخیال اور رفتار وکردار حتی اسکے نفس کے اوپر اسکے واضح آثار ونتائج اور نقوش نظر آئیں گے جن میں اس وقت تک کسی قسم کا تغیّریا تبدیلی ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنا انداز فکر تبدیل نہ کرلے ۔
اس حقیقت کی بیحدا ہمیت ہے اوریہ اسلامی نظام تربیت کی ریڑ ھ کی ہڈی کا ایک حصّہ ہے اسی بنیاد پر ہم دنیا کے بارے میںسطحی طرز نگاہ ۔(جو دنیا سے آ گے نہیں دیکھتی )اور جسے مولا ئے کائنات نے ۔(الابصار الی الد نیا)دنیا کو منظور نظر بنا کر دیکھنے سے تعبیر کیا ہے ۔۔۔اور دنیا کے بارے میں عمیق طرز نگاہ جسے امیرالمو منین نے (ابصاربالدنیا)دنیا کو ذریعہ بنا کر دیکھنے سے تعبیر کیا ہے ان دونوں کے نفسیاتی اور عملی اثرات کا جائز ہ پیش کریں گے البتہ ان دونوں نگاہوں کا
سب سے بڑا اثرحب دنیا یا زہد دنیا ہے ۔۔۔کیونکہ حب دنیا دراصل دنیا کے بارے میں سطحی طرز نگاہ کا فطری نتیجہ ہے اورزہد دنیا اسکے بارے میں عمیق طرز نگاہ کا فطری نتیجہ ہے ۔
لہٰذا اس مقام پر ہم انسانی زندگی کی ان دونوں حالتوں پر روشنی ڈال رہے ہیں ۔
حب دنیا
جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ حب دنیا دراصل دنیا کے بارے میں سطحی انداز فکر کا نتیجہ ہے اور اس انداز نگاہ میں ماور ائے دنیا کو دیکھنے کی طاقت نہیں پائی جاتی ہے لہٰذا یہ دنیا کی رنگینیوں اور آسائشوں تک محدود رہتی ہے اور اسی کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے ۔جبکہ زہد وپارسائی،دنیا کے بارے میں باریک بینی اور دقت نظر کا نتیجہ ہے ۔
حب دنیا ہر برائی کا سر چشمہ
انسانی زندگی میں حب دنیا ہی ہر برائی اور شروفساد کا سرچشمہ ہے چنانچہ حیات انسانی میں کوئی برائی اور مشکل ایسی نہیں ہے جسکی کل بنیاد یااسکی کچھ نہ کچھ وجہ حب دنیا نہ ہو!
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم :
(حبّ الدنیا أصل کل معصیة،وأول کل ذنب )( ۱ )
''دنیاکی محبت ہر معصیت کی بنیاد اور ہر گناہ کی ابتدا ہے ''
حضرت علی کا فرمان ہے :
(حبّ الدنیا رأس الفتن وأصل المحن )( ۲ )
____________________
(۱)میزان الحکمت ج۳ص۲۹۴۔
(۲)غرر الحکم ج۱ص۳۴۲۔
''محبت دنیا فتنوں کا سر اور زحمتوںکی اصل بنیاد ہے ''
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :
(رأس کل خطیئة حبّ الدنیا )( ۱ )
''ہر برائی کی ابتدا (سر چشمہ )دنیاکی محبت ہے ''
حب دنیا کا نتیجہ کفر ؟
حب دنیا کا سب سے خطر ناک نتیجہ کفر ہے جیسا کہ قرآن مجید میں محبت دنیا اور کفر کے درمیان موجود رابطہ اور حب دنیا کے خطر ناک نتائج کا تذکر ہ بار بار کیا گیا ہے ۔
۱۔خدا وندعالم کا ارشاد ہے :
( ولکن من شرح با لکفرصدراً فعلیهم غضب من ﷲ ولهم عذاب عظیم ذلک بأنهم استحبوا الحیاة الدنیاعلیٰ الآخرة وأن ﷲ لا یهدی القوم الکافرین ) ( ۲ )
'' لیکن جو شخص کفر کے لئے سینہ کشادہ رکھتا ہو ان کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اسکے لئے بہت بڑا عذاب ہے ۔یہ اس لئے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا اور ﷲ،ظالم قوموں کو ہر گز ہدایت نہیں دیتا ہے ''
اس آیۂ کریمہ میں صرف کفرہی کو حب دنیا کا اثر نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ آیۂ کریمہ نے اس سے کہیں آگے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ حب دنیا سے کفر کیلئے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور انسان اپنے کفر پر اطمینان خاطر پیدا کر لیتا ہے اور اسکے لئے کھلے دل (سعہ صدر )کا مظاہر ہ کرتا ہے اور یہ صور تحال کفر سے بھی بدتر ہے ایسے لوگوں پر خدا وند عالم غضبناک ہوتا ہے اور انھیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے ۔
____________________
(۱)بحار الا نوار ج۷۳ص۷ ۔
(۲) سورئہ نحل آیت ۱۰۶۔۱۰۷۔
۲۔ارشاد الٰہی ہے :
( وویل للکافرین من عذاب شدید٭الذین یستحبون الحیاة الدنیا علیٰ الآخرة ویصدّ ون عن سبیل ﷲ ویبغونها عوجاً ) ( ۱ )
''اور کافروں کے لئے تو سخت ترین اورا فسوسناک عذاب ہے وہ لوگ جو زندگانی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر تے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں ''
اس آیۂ کریمہ میں حب دنیا اور کفر یا راہ خدا سے روکنے کے درمیان موجود رابطہ کا بخوبی مشاہد ہ کیا جاسکتا ہے ۔
____________________
(۱)ابراہیم آیت۲۔۳۔
حب دنیا کے نفسیا تی اور عملی آثار
حب دنیا سے انسان کے کردار وعمل پر بے شمار اثرات پڑتے ہیں جن میں سے ہم بعض آثار کی وضاحت پیش کررہے ہیں ۔
۱۔طولانی آرزو
اسمیں کوئی شک وشبہ نہیں ہے کہ لمبی آرزوئیں بھی حب دنیا کا ایک اثر ہیں ۔ کیونکہ جب انسان دنیا کا دلدادہ ہوجاتا ہے اور اس سے وابستہ ہوکر رہ جاتا ہے تو اسکی آرزو ئیں بھی بہت طولانی ہوجاتی ہیں یہ ہے تصویر کا پہلا رخ ۔
تصویرکا دوسرا رخ !یہ ہے کہ جسکی آرزوئیں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ موت کو بہت کم یاد رکھتا ہے اور آخرت کیلئے اسکی تیاری اور اسکا عمل کم ہوجاتا ہے جسکی طرف روایات میں با قاعدہ متوجہ کیا گیا ہے حضرت علی کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائیں :
(ما أطاٰل عبد الأمل،الا أساء العمل )( ۱ )
''کسی شخص نے اپنی آرزوئیں طولانی نہیںکیں مگر یہ کہ اس نے اپنا عمل خراب کرلیا''
آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے :
(أکثرالناس أملاً،أقلّهم للموت ذکراً )( ۲ )
''لمبی آرزو رکھنے والے لوگ موت کوسب سے کم یاد کرتے ہیں ''
آپ نے یہ بھی فرمایا ہے :
(أطول الناس أملاً،أسوؤهم عملاً )( ۳ )
''جسکی آرزوئیںسب سے زیادہ ہوتی ہیں اسکا عمل سب سے بدتر ہوتا ہے ''
تیسرارخ یہ ہے !کہ جسکی آرزوئیںلمبی ہوتی ہیں وہ انہیں کو اپنے لئے سکون واطمینان کا سبب سمجھ لیتا ہے جبکہ اس دنیا کو خود ہی قرار نہیں ہے ۔مگر وہ اس سے وابستہ ہوکر اسی سے مطمئن ہوجاتا ہے ۔جسکی تفصیل آپ مندرجہ ذیل سطروں میں ملاحظہ فرماسکتے ہیں ۔
۲۔دنیا پر اعتماد اور اطمینان
جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ دنیا کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں اسکی محبت اور اس سے خوش وخرم رہنے سے دنیا پر اطمینان و اعتمادپیدا ہوتا ہے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( ان الذین لا یرجون لقاء نا ورضوا بالحیاة الدنیاواطمأنّوا بها والذین هم عن آیا تنا غافلون٭ اُولٰئک مأواهم النار بماکانوا یکسبون ) ( ۴ )
____________________
(۱)بحار الا نوار ج۷۳ص۱۶۶۔
(۲)غررالحکم ج۱ ص۱۹۰۔
(۳)گذشتہ حوالہ۔
(۴)سورئہ یونس آیت ۷۔۸۔
''یقینا جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور زندگانی دنیا پر راضی اور مطمئن ہوگئے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں یہ سب وہ ہیں جنکے اعمال کی بناء پر انکا ٹھکانا جہنم ہے ''
دنیا کے اوپر اس جھوٹے بھروسہ کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اسی دار دنیا میں رہنا ہے جبکہ یہ باقی رہنے والی نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ پونجی ہے جو بہت جلد فنا کے گھاٹ اتر جائیگی۔درحقیقت دار قرار وبقاء تو جنت ہے ۔جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے:
( وفرحوا بالحیاة الدنیا وماالحیاةالدنیا فی الآخرة الامتاع ) ( ۱ )
''یہ لوگ صرف زندگانی دنیا پر خوش ہو گئے ہیں حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں زندگانی دنیا صرف ایک وقتی لذ ت کا درجہ رکھتی ہے۔''
یا دوسرے مقام پر ارشاد ہے :
( یاقوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دارالقرار ) ( ۲ )
''قوم والو! یاد رکھوکہ یہ حیا ت دنیا صرف چند روزہ لذت ہے اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے ''
مختصر یہ کہ دنیا ختم ہوجانے والی پونجی ہے مگر آخرت ہمیشہ باقی رہنے والاسرمایہ ہے جبکہ اسکے برخلاف جو لوگ دنیا پر بھروسہ کئے بیٹھے ہیں اور اس کی محبت ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے اور وہ اسی پر خوش ہیں وہ در حقیقت دنیا کی ابدیت اور بقاء کی خام خیالی کے دھوکہ میں مبتلا ہیں۔
حضرت علی سے اس حدیث قدسی کی روایت کی گئی ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے :
(عجبت لمن یریٰ الدنیا وتصرّف أهلها حالاً بعد حال،کیف یطمئن الیها )( ۳ )
____________________
(۱)سورئہ رعد آیت ۲۶۔
(۲)سورئہ غافر آیت ۳۹۔
(۳)بحارالانوار ج۷۳ص۹۷۔
''مجھے اس شخص کے اوپر تعجب ہے جو دنیا اور اسکے الٹ پھیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے پھر بھی وہ اس کے اوپر کیسے بھروسہ کرلیتا ہے ؟''
یا خداوند عالم نے جناب موسی کی طرف یہ وحی نازل فرمائی تھی :
( یاموسیٰ لا ترکن الیٰ الدنیا رکون الظالمین،ورکون من اتخذها أُماً وأباً، واترک من الدنیامابک الغنیٰ عنه ) ( ۱ )
''اے موسی دنیا سے اس طرح دل نہ لگائو جس طرح ظالمین دنیا کے دلدادہ ہیں یا جن لوگوں نے اس کو اپنی ماں یا اپناباپ سمجھ رکھا ہے اور دنیاکو ایسے ترک کردو جیسے تمہیں اسکی ضرورت ہی نہیں ہے ''
در حقیقت یہ ایک صاف اور شفاف تعبیر ہے کہ جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اسی طرح بہت سارے لوگ دنیا پر بھروسہ رکھتے ہیں جبکہ انھیں اسکے تغیّرات کا بخوبی علم ہے ۔جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے کھیل تماشے یا اسکی رنگینیوںاور اسباب راحت جیسے فضولیات کی اوقات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اس سے دھوکہ نہیں کھاتے اور یہ حضرات اسکی طرف نگاہ اٹھاکر دیکھنے کے بجائے حقیقی زندگی کی تلاش میں صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں کیونکہ واقعی اور حقیقی زندگی در اصل آخرت کی زندگی ہے۔ جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
( وما هذه الحیاة الد نیا الا لهوولعب وان ا لدار الآخرة لهی الحیوان ) ( ۲ )
''اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے۔۔۔ ''
۳۔دنیاوی زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا
یہ بھی حب دنیا کا ہی ایک نتیجہ ہے کیونکہ جب انسان حد سے زیادہ محبت دنیا کا دلدادہ ہوجاتا
____________________
(۱)بحارالانوارج۱۳ص۳۵۴وج۷۳ص۷۳۔
(۲)سورئہ عنکبوت آیت ۶۴۔
ہے تو وہ اسکو آخرت پر ترجیح دینے لگتا جسکی طرف خداوند عالم نے قرآن مجید میں یوں اشارہ کیا ہے :
( فأمّا من طغیٰ وآثرالحیاة الدنیا فانّ الجحیم هی المأویٰ ) ( ۱ )
''پھرجس نے سرکشی کی ہے اور زندگانی دنیا کو اختیار کیا ہے جہنم اسکاٹھکاناہوگا''
( بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرةخیروأبقیٰ ) ( ۲ )
''لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو جبکہ آخرت مقدم اور ہمیشہ رہنے والی ہے ''
در حقیقت ان لوگوں کو صرف دنیا چاہئیے اور دنیا کو آخرت پر اسی وقت ترجیح دی جاسکتی ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان ٹکرائو پیدا ہوجائے کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان ٹکرائو پیدا ہوگا تو ان میں سے کسی ایک کو اختیارکرنا پڑیگا یعنی یا صرف دنیا کو لے لیا جائے اور یا صرف آخرت کو؟اور کیونکہ ان لوگوں نے آخرت کو چھوڑکر دنیا کو اپنا لیا ہے لہٰذا اب انہیں دنیاوی زندگی کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہے ۔جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( فأعرض عمن تولّیٰ عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاة الدنیا ) ( ۳ )
''لہٰذا جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منھ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے، آپ بھی اس سے کنارہ کش ہوجائیں''
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوںنے دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا ہے جیسا کہ ارشاد ہے :
( اُولٰئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة ) ( ۴ )
''یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے آخرت کو دے کردنیا خریدی ہے''
____________________
(۱)سورئہ نازعات آیت ۳۷،۳۸،۳۹۔
(۲)سورئہ اعلیٰ آیت۱۶،۱۷۔
(۳)سورئہ نجم آیت ۲۹۔
(۴)سورئہ بقرہ آیت ۸۶۔
اسی بارے میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے یہ روایت ہے :
(من عرضت له دنیاوآخرة،فاختارالدنیاعلیٰ الآخرة،لقی اللّٰه عزّوجلّ ولیست له حسنة یتّقی بهاالنار،ومن أخذالآخرةوترک الدنیالقی اللّٰه یوم القیامة وهو راضٍ عنه )( ۱ )
''جس کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو پیش کیا جائے اور وہ آخرت کو چھوڑ کردنیا کو اپنا لے تو جب وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں پہونچے گا تو اسکے نامۂ عمل میں کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم سے بچاسکے اور جو شخص دنیا کو چھوڑکر آخرت کو اپنا لے جب وہ روز قیامت خداوند عالم سے ملاقات کریگا تو وہ اس سے راضی رہے گا ''
حضرت علی :
(من عبدالدنیا وآثرها علیٰ الآخرة استوخم العاقبة )( ۲ )
''جو دنیا کا پجاری ہوگیا اور اس نے اسے (دنیا کو) آخرت پر ترجیح دی ہے اس نے اپنی عاقبت بگاڑلی''
حضرت علی :
(لا یترک الناس شیئاً من أمردینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح اللّٰه علیهم ما هوأضرّ منه )( ۳ )
''لوگ اپنی دنیا کی بھلائی کے لئے اپنے دین کا کوئی کام ترک نہیں کرتے مگر یہ کہ خداوند عالم ان کے سامنے اس سے زیادہ مضردروازہ کھول دتیا ہے ''
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۶ص۲۶۴وج۷۳ص۱۰۳۔
(۲)بحارالانوار ج۷۳ص۱۰۴۔
(۳)بحارالانوار ج۷۰ص۱۰۷۔
آپ ہی سے یہ بھی مروی ہے :
(من لم یبال مارزء من آخرته اذا سلمت له دنیاه فهوهالک )( ۱ )
''اگر کسی کی دنیاسالم ہو اور اسے یہ فکر نہ ہو کہ اس نے اپنی آخرت کے لئے کیا حاصل کیا تو وہ ہلاک ہونے والا ہے ''
آخرت کی نعمتوں کے لئے دنیا ہی میں عجلت پسندی
حب دنیا کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان آخرت کی نعمتوں کو دنیا میں ہی حاصل کرنے کے لئے عجلت سے کام لیتا ہے کیونکہ خداوند عالم نے انسان کو در حقیقت جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے پیدا کیا ہے لہٰذا جب انسان دنیا کا دلدادہ ہوجاتا ہے اور اسکی لذتوں اور نعمتوں پراکتفاء کر بیٹھتا ہے تو گویا اسے دنیا میں ہی آخرت کی تمام نعمتیں حاصل کرلینے کی جلدی ہے جیسے کوئی کسان جلدی غلہ یا پھل توڑنے کی فکر میں اسے خام اور کچاہی توڑلیتا ہے یا وہ بچہ جو بزرگی اور بڑھاپے کے دور کی راحت وآرام کوپہلے ہی حاصل کرنے کے لئے کھیل کود میں وقت گذار دیتا ہے اور اپنی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیںدیتا یعنی اسکے اوپر مستقبل (بڑھاپے اور ادھیڑپن )کے راحت وآرام کو قربان کرڈالتا ہے جس کی تصویر کشی اس آیۂ کریمہ نے کتنے حسین انداز میں کی ہے :( ۲ )
____________________
(۱)بحار الانوار ج۷۷ ص۲۷۷۔
(۲) اس تحقیق کا موضوع در حقیقت دنیا اور آخرت کے ٹکرائو کے وقت ہے یعنی ''حدود الٰہی ''اور دنیاکاٹکرائو! چنانچہ حدوداور احکام الٰہی کی پابندی کا لازمہ دنیا کی بعض اچھی چیزوںسے محرومی ہے اور دنیا سے لگائو کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان بعض حدود الٰہیہ سے تجاوز کر جائے اس مرحلہ پر انسان دنیا اور آخرت کے دوراہے پر کھڑاہوتا ہے اور یہ درحقیقت محرومی نہیں ہے چونکہ جب انسان حدود الٰہیہ کا پابند ہوجاتا ہے تو پروردگار اسکو آخرت کی نعمتیں جو کامل ودائم ،تروتازہ اور باقی رہنے والی ہیںدیناچاہتاہے لیکن انسان ان کو دنیا ہی میں پانے کے لئے جلدی کرتاہے اور ان کو اچانک حاصل کرلیتا ہے جو ناپختہ ہوتی ہیں اور یہ بہت جلدزائل ہوجانے والی پونجی ہے اور اس میں بے شمار مشکلات اور خطرات پائے جاتے ہیں ۔
جب ہم اسلامی نصوص میں غوروفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ کسی حد تک دنیا کی حلال چیزوں پر بھی منطبق ہوتا ہے لیکن مطلق طورپر نہیں لہذاجب کوئی انسان دنیا کی بعض حلال چیزوں میں زہد اختیار کرتا ہے تو خداوند عالم اسکے لئےآخرت کی نعمتیںذخیرہ کردیتا ہے ۔۔۔اور شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ اسکوحاصل کر لینے کے بعد اسکے دل میں دنیا سے لگائو اور اسکی محبت پیدا ہو سکتی ہے یایہ حکم مومنین کے غریب طبقہ سے برابری کی بنا پرہو۔۔۔ بہرحال اسکی وجہ چاہے جو بھی ہو اس قاعدہ اور خداوند عالم کے اس قول :( قل من حرّم زینة ﷲ التی أخرج لعبادہ والطیبات من الرزق)کے درمیان ہر لحاظ سے مطابقت پائی جاتی ہے ۔
( ویوم یعرض الذین کفروا علیٰ النارأذهبتم طیبا تکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بماکنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبماکنتم تفسقون ) ( ۱ )
''اور جس دن کفار جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑاچکے اور اس میں خوب چین کرچکے تو آج تم پر ذلت کا عذاب کیا جائے گا اس لئے کہ تم زمین میں اکڑاکرتے تھے اور اس لئے کہ تم بد کاریاں کرتے تھے ''
اس قول الٰہی کے بارے میں توجہ فرمائیں :
( أذهبتم طیبا تکم فی حیاتکم الدنیا ) ( ۲ )
''تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑاچکے ''
جبکہ خداوند عالم نے انسان کیلئے ان بہترین نعمتوں کو آخرت میں ذخیرہ کرکے رکھا ہے اور وہی دارالقرارہے لیکن انسان اسکو اچھی طرح پختہ ہونے بلکہ ان پرپھل آنے سے پہلے ہی دنیا میں ان کی فصل کانٹے کے لئے جلدبازی کرنے لگتا ہے جبکہ وہ بہت جلد تمام ہوکر گذر جانے والی ہیں۔
زود گذر
قرآن مجید نے دنیا کو اسی وجہ سے''زودگذر ''کہا ہے کیونکہ انسان اس دنیا میں آخرت کی نعمتوں کوان کے وقت سے پہلے ہی حاصل کرلینا چاہتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے :
____________________
(۱ ۲ )سورئہ احقاف آیت۲۰۔
( من کان یرید العاجلة عجّلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ) ( ۱ )
''اور جو شخص دنیا کا خواہاں ہوتو ہم جسے چاہتے اور جو چاہتے ہیں اسی دنیا میں سردست عطا کردیتے ہیں ''
آیت کے آخری حصہ (ما نشاء لمن نرید) '' ہم جسے چاہتے اور جو چاہتے ہیں''کے معنی پر توجہ کے بعد یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ دنیا میں ہی آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لئے جلد بازی کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی عجلت پسندی اوربے تابی کی وجہ سے جو چاہے حاصل کرلے بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ اسکی جلد بازی کے بعد بھی خداوند عالم ہی اسے جیسے چاہتا ہے اپنے اعتبار سے کم یا زیادہ رزق عطا کرتا ہے گویا رزق پھر بھی خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے اور اس پر وہی حکم فرماہے اور اس میں جلد بازی دکھانے سے انسان کا کچھ بس چلنے والا نہیں ہے ۔۔۔مگر اسکے باوجود بھی وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوجاتا ہے اور جن نعمتوں کیلئے اس نے ناجائز طورپر جلد بازی کی تھی وہ کم ہوجاتی ہیں۔
اس بارے میں خداوند عالم کا یہ ارشاد بھی ہے :
( قالواربّناعجل لناقِطّناقبل یوم الحساب ) ( ۲ )
''انہوں نے کہا پروردگار روز حساب سے پہلے ہی دنیا میں ہمارا حصہ ہمیں دیدے ''
یا خداوند عالم کا یہ بھی ارشاد ہے :( کلا بل تُحبّون العاجلة ) ( ۳ )
''مگر( لوگو )حق تو یہ ہے کہ تم لوگ(زود گذر) دنیا کو دوست رکھتے ہو''
دوسرے مقام پر ارشاد ہے :
____________________
(۱)سورئہ اسراء آیت ۱۸۔
(۲)سورئہ ص آیت۱۶۔
(۳)سورئہ قیامت آیت ۲۰۔
( ان هؤلاء یُحبّون العاجلة ویذرون وراء هم یوماً ثقیلاً ) ( ۱ )
''یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پس پشت چھوڑبیٹھے ہیں ''
ہم جب روایات کے اندر غوروفکر کرتے ہیں تویہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا وآخرت کے درمیان ٹکرائو ہمیشہ محرمات کے میدان ہی میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ٹکرائو کبھی کبھی ''حلال'' معاملات کے درمیان بھی پیدا ہوسکتا ہے یہ نکتہ اسلامی افکار کے انوکھے نظریات میں سے ایک ہے ۔
جیسا کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم اور آپ کے اہلبیت طاہرین اور خداوند عالم کے دوسرے نیک اور صالح بندے دنیا کی نعمتوں کے استعمال میں افراط کو پسند نہیںکرتے تھے جسکا سبب شاید یہ ہوکہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ لطف اندوز ہونے سے اس کی محبت میں اضافہ ہوجاتا ہے اورانسان دنیا سے مزید وابستہ ہوجاتا ہے کیونکہ دنیا کی محبت اور اس کی نعمتوں کے لئے جلد بازی کرنے کے درمیان دو طرفہ (طرفینی)رابطہ ہے یعنی جب انسان دنیا سے محبت کریگا تو اسکی نعمتوں کو حاصل کرنے کیلئے بے تابی دکھا ئے گا اور جب نعمتوں کو حاصل کرنے کیلئے جلد بازی سے کام لینے لگے گا تو اسکے دل میں دنیا کی محبت رچ بس جائے گی ۔
بہر حال اس تحقیق کا نتیجہ چاہے جو کچھ بھی ہو لیکن ہمیں اس بات میں کوئی شک وشبہہ نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان ٹکرائو حلال چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لئے جن آرائشوں یا نعمتوں کو حلال قرار دیا ہے انہیں حرام قرار دیدیاجائے بلکہ اسکا معاملہ حلال و حرام کے ٹکرائوکے معاملات سے بالکل الگ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ یہ اسلامی افکارکے مختلف انوکھے نظریات میں سے ایک نظریہ ہے ۔
____________________
(۱)سورئہ انسان آیت ۲۷۔
آئندہ سطروں میں ہم اس بارے میں موجود روایات ذکر کرینگے اور اسکے بعد انکی وضاحت
اور تفسیر بھی پیش کریںگے۔
روایات
حضرتعمر کا بیان ہے کہ میں نے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خدمت میںعرض کی کہ اے ﷲ کے رسول ،خدا سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت کو بھی فراوانیاں عطا کرے ۔ اللہ نے فار س و روم کو تو خوب نواز رکھا ہے حالانکہ وہ قومیں خدا کی عبادت بھی نہیں کرتی ہیں۔پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم سیدھے ہوکر بیٹھ گئے اور فرمایا:
(أفیشک أنت یابن الخطاباُو قوم عُجّلت لهم طیبا تهم فی الحیاةالدنیا )( ۱ )
''اے ابن خطاب تم کس شک میں مبتلا ہو ؟ان قوموں نے اپنے طیبات کو اسی زندگانی دنیا میں پالیا ہے ''
پیغمبر اکرم کی خدمت میں ''خبیص''(ایک قسم کا حلوہ )پیش کیا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار فرمادیا حاضرین نے پوچھا۔کیا آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں ؟آپ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا نفس اسکاشوقین ہوجائے :
پھر آپ نے اس آیۂ کریمہ کی تلاوت فرمائی:
(أذهبتم طیبا تکم فی الحیاةالدنیا )( ۲ )
''تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑاچکے ''
____________________
(۱)کنز العمال :ح۴۶۶۴۔
(۲)نورالثقلین ج۵ص ۱۵۔
عمر بن خطاب کابیان ہے کہ میںنے حضور سے باریابی کی اجازت طلب کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا آپ مشربۂ ام ابراہیم (ایک جگہ کا نام)میں اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے جسم مبارک کے بعض حصے خاک پر تھے آپ کے سر کے نیچے کھجور کی پتیوں کا تکیہ تھا، میں سلام کرکے بیٹھ گیا اور عرض کی :اے رسول خدا آپ ﷲ کے نبی،اسکے منتخب بندے اور بہترین خلق خدا ہیں۔قیصر وکسری سونے کے تخت اور حریر و دیباکے فرش پر آرام کرتے ہیں(اور آپ کا یہ عالم ہے ؟)رسول خدا نے فرمایا:
(اُولٰئک قوم عُجّلت طیباتهم وهی وشیکة الانقطاع،وانما اُخّرت لناطیبا تنا )( ۱ )
''ان اقوام کے طیبات یہیں عطا کردئے گئے ہیںجوبہت جلد منقطع ہوجائیں گے۔ اورہمارے طیبات کو آخرت پر اٹھارکھا گیا ہے ''
روایت ہے کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم اصحاب صفہ کے پاس پہونچے تو وہ اپنے کپڑوں میں چمڑے کا پیوند لگارہے تھے اور ان کے پاس پیوند لگانے کے لئے کپڑے کا ٹکڑا نہیں تھا تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دن تمہارے لئے بہتر ہے یا وہ دن جب صبح کو تم بہترین حلے پہنے ہوگے اور شام کے وقت دوسرا پہن لو گے اور صبح کو ایک پیالا اور شام کو دوسرا پیالا استعمال کروگے اور اپنے گھر پر اس طرح غلاف چڑھائے ر کھوگے جس طرح کعبہ پر غلاف چڑھارہتا ہے ؟تو انھوں نے جواب دیا کہ ہمارے لئے وہی دن بہتر ہے تو آپ نے فرمایا :نہیں بلکہ تم آج ہی بہتر ہو۔( ۲ )
پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم نے جناب فاطمہصلىاللهعليهوآلهوسلم کو دیکھا کہ آپ اونٹ کے بالوںسے بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اوراپنے ہاتھوں سے چکی چلارہی ہیں اوراپنے بچے کودودھ پلارہی ہیں تو پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور آپ نے فرمایا:
____________________
(۱)نورالثقلین ج۵ص۱۵۔
(۲)نورالثقلین ج۵ص۱۷۔
(یابنتاه تعجّلی مرارة الدنیا بحلاوة الآخرة )
''اے بیٹی آج تلخی دنیا کے بدلے آخرت کی حلاوت خرید لو''
جناب فاطمہصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
(یارسول ﷲ الحمدﷲ علیٰ نعمائه،والشکرﷲ علیٰ آلائه )
''اے رسول خدا ،تمام تعریفیں ﷲ کے لئے ہیں اسکی نعمتوں پر ،اور اسکی عنایات پراس کا شکر ہے
تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی:
(ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ )( ۱ )
''عنقریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گاکہ آپ خوش ہوجائیں گے''
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :
(انّا لنحبّ الدنیا،وأن لانؤتاها خیرمن أن نؤتاها،وما أوتی ابن آدم منها شیئاً الا نقص حَظّه من الآخرة )( ۲ )
''ہمیںدنیا سے محبت ہے اور ہماری نگاہ میں دنیا کا نہ ملنا اس کے ملنے سے بہتر ہے کیونکہ فرزند آدم کو جس مقدار میں دنیا ملتی ہے آخرت سے اسکا اتنا ہی حصہ کم ہوجاتا ہے ''
امام جعفر صادق سے منقول ہے :
(آخرنبی یدخل الجنة سلیمان بن داؤد عليهالسلام وذلک لما اُعطی فی الدنیا )( ۳ )
''جنت میں داخل ہونے والے آخری نبی سلیمان بن دائود ہوں گے کیونکہ دنیامیںانہیں
____________________
(۱)نورالثقلین ج۵ص۵۹۴ومیزان الحکمت ج۳:ص۳۲۶۔۳۲۷۔
(۲)بحارالانوار ج۷۱ ص۸۱ ومیزان الحکمت ج۲:ص۳۲۶۔
(۳) بحارالانوار ج۱۴ص ۷۴۔
بہت کچھ عطا کردیا گیا تھا ''
امیر المومنین حضرت علی کا ارشا د ہے:
(کلمافاتک من الدنیا شی ئ فهوغنیمة )( ۱ )
''دنیا میں جو چیز بھی تم سے فوت ہوجائے وہ غنیمت ہے ''
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:
(مرارة الدنیاحلاوةالآخرة،وحلاوةالدنیامرارةالآخرةوسوء العقبیٰ )( ۲ )
''دنیا کی تلخی آخرت کی حلاوت و شیرینی ہے اور دنیا کی حلاوت آخرت کی تلخی اور بری عاقبت ہے ''
آپ نے ارشاد فرمایا :
(من طلب من الدنیاشیئاً فاته من الآخرة أکثرمما طلب )( ۳ )
''جو دنیا میں کسی شے کو طلب کرتا ہے اس سے زیادہ اسکا آخرت میں گھاٹاہوجاتا ہے ''
آپ ہی سے منقول ہے :
(مازادفی الدنیا نقص فی الآخرة،ومانقص من الدنیا زاد فی الآخرة )( ۴ )
''دنیا کی زیادتی آخرت کا نقصان اور دنیا کا نقصان آخرت کی زیادتی ہے ''
امام جعفر صادق نے حضرت امام زین العابدین کا یہ قول نقل کیا ہے :
(ماعرض لی قط أمران،أحدهما للدنیا،والآخر للآخرة،فآثرت
____________________
(۱)غررالحکم ج۲ص۱۱۱۔
(۲)نہج البلاغہ حکمت ۲۴۳۔
(۳)غررالحکم ج۲ص۲۲۱۔
(۴)غررالحکم ج۲ص۲۶۸۔
الدنیا الا رأیت ما أکره قبل أن اُمسی )
''میرے سامنے جب بھی کبھی دو کام آتے ہیں ایک دنیا سے متعلق اور دوسرا آخرت سے متعلق ،اگر میں نے ان میںدنیا وی کام کو ترجیح دیدی تو شام ہونے سے قبل ناپسندیدہ اور مکروہ شے کا مشاہدہ کرلیتا ہوں ''
پھر امام جعفر صادق نے فرمایا:
(لبَنی اُمیة أنهم یؤثرون الدنیا علیٰ الآخرة منذ ثمانین سنة ولیس یرون شیئاً یکرهونه )( ۱ )
''اور یہ بنی امیہ اسّی سال سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں اور انہیں کسی بھی چیز سے کراہت محسوس نہیں ہوتی ہے ''
اس مسئلہ کی وضاحت امیر المومنین کے اس قول سے ہوجاتی ہے :
(واعملوا أن مانقص من الدنیا،وزاد فی الآخرة خیرمما نقص من الآخرة وزاد فی الدنیا،فکم من منقوصفا تقواﷲحق تقا ته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون )( ۲ )
''یاد رکھو کہ دنیا میں کسی شے کا کم ہونا اورآخرت میں زیادہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں زیادہ ہو اور آخرت میں کم ہو جائے کہ کتنے ہی کمی والے فائدہ میں رہتے ہیں اور کتنے ہی زیادتی والے گھاٹے میں رہ جاتے ہیں ۔بیشک جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان میں زیادہ وسعت ہے بہ نسبت ان چیزوں کے جن سے روکا گیا ہے اور جنہیں حلال کیا گیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۳ص۱۲۷۔
(۲)نہج البلاغہ خطبہ ۱۱۳۔
جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے لہٰذا قلیل کو کثیر کے لئے اور تنگی کو وسعت کی خاطر چھوڑدو ۔پروردگار نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا ایسا نہ ہو کہ جس کی ضمانت لی گئی ہے اسکی طلب اس سے زیادہ ہوجائے جس کو فرض کیا گیا ہے ۔خدا گواہ ہے کہ تمہارے حالات کو دیکھ کر شبہ ہونے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شائد جس کی ضمانت لی گئی ہے وہ تم پر واجب کیا گیا ہے اور جس کا حکم دیا گیا ہے اسے ساقط کردیاگیا ہے ۔خدا را عمل کی طرف سبقت کرو اورموت کے اچانک وارد ہوجانے سے ڈرو اس لئے کہ موت کے واپس ہونے کی وہ امید نہیںہے جس قدر رزق کے پلٹ کر آجانے کی ہے ۔جو رزق آج ہاتھ سے نکل گیا ہے اس میں کل اضافہ کا امکان ہے لیکن جو عمر آج نکل گئی ہے اسکے کل واپس آنے کا بھی امکان نہیں ہے ۔امید آنے والے کی ہوسکتی ہے جانے والے کی نہیں اس سے تو مایوسی ہی ہوسکتی ہے ''ﷲسے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور خبر دار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہوجائو''
روایات کا تجزیہ
مذکورہ روایات میں سند یا متن کے لحاظ سے شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ تعدادکے اعتبار سے بہت زیادہ اورسند کے لحاظ سے مستفیضہ ہیںلہٰذاان سب کے بارے میں شک کا امکان نہیں ہے یہ روایا ت فقط حرام امور سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ حرام وحلال دونوں قسم کی لذتوں کو بیان کرتی ہیں ان روایات کے مطابق دنیا و آخرت کا ٹکرائو صرف حرام اشیاء میں ہی نہیں بلکہ اس ٹکرائو میں حلال لذتیں بھی شامل ہیں ان کے معانی و مطالب واضح اور ظاہر ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ صرف حرام لذتوں سے منع کر رہی ہیں جس کی بناپر خداوند عالم کایہ قول :
(یاأیهاالنّاس کلواممافی الارض حلالاً طیّباولا تتبعواخطوات الشیطان انه لکم عدومبین )( ۱ )
''اے انسانو:زمین میں جوکچھ بھی حلال وطیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے ''
یا دوسرے مقام پر ارشاد ہے :
(قل من حرّم زینة ﷲ التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق،قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیاخالصة یوم القیامة )( ۲ )
''پیغمبر آپ پوچھئے کہ کس نے اس زینت کوجسے خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کردیا ہے اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں ''
مذکورہ دونوںاقوال صرف خداوند عالم کی حلال کردہ طیبات سے مخصوص ہوجائیں جبکہ یہ روایات حرام چیزوں کے علاوہ زندگانی دنیا کی آسائشوں (متاع)سے استفادہ کرنے سے بھی منع کررہی ہیں۔
تو ہم ان روایات سے کیا نتیجہ اخذ کریں؟ایک جانب یہ روایات ہیں اور دوسری طرف قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جن میں خداوند عالم اپنے بندوں کو طیب وطاہر رزق سے استفادہ کی دعوت دے رہا ہے اور طیبات الٰہی کو حرام قرار دینے والوں کو ٹوک رہا ہے ؟
ذیل میں ہم چند نکات کے ذریعہ اس سوال کا جواب پیش کرنے کی کوشش کریںگے امید ہے کہ ان نکات کے ساتھ ہمیںبہ ترتیب اسکاصحیح جواب مل جائے گا :
۱ ۔ذرادیر پہلے ہم نے جو روایات پیش کی ہیں ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام نعمات
____________________
(۱)سورئہ بقرہ آیت ۱۶۸۔
(۲)سورئہ اعراف آیت ۳۲۔
الٰہیہ اور طیب وطاہر رزق کو مسلمانوں کے لئے ممنوع قرار دیتا ہے ۔ ﷲ نے اپنے بندوں کے لئے جو اسباب زینت اور طیبات خلق کئے وہ بندوں کے لئے جائز اور مباح ہیں مگر یہ کہ خود پروردگار منع کردے خداوند عالم فرماتاہے:
( قل من حرّم زینة ﷲ التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الد نیاخالصة یوم القیامة وکذ الک نفصل الآیات لقوم یعلمون ) ( ۱ )
''کہو کہ کس نے اس زینت کو جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور پاکیزہ رزق کو حرام کردیا ہے ۔اور بتائیے کہ یہ چیزیں روز قیامت صرف ان لوگوں کے لئے ہیںجو زندگانی دنیا میں ایمان لائے ہیں ''
ان روایات کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان روئے زمین پر سعی و کوشش ہی نہ کرے بلکہ اس سلسلہ میں خدا کا حکم تو یہ ہے کہ :
( فاذاقُضیت الصلوٰة فانتشروا فی الارض وابتغوامن فضل ﷲ ) ( ۲ )
''پھر جب نماز تمام ہوجائے تو زمین میں منتشر ہوجائو اور فضل خدا کو تلاش کرو''
لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کا ہی ہوکر رہ جائے اور اسکی تمام تر کوششوں کا ماحصل صرف دنیا ہو بلکہ انسان کا اصل مقصد سلو ک الی ﷲ ہونا چاہئیے اور اسی کے ضمن میں دنیا کے لئے بھی کوشش کرتا رہے ۔
( وابتغِ فیماآتاک ﷲ الدارالآخرة ولاتنسنصیبک من الدنیا ) ( ۳ )
____________________
(۱)سورئہ اعراف آیت ۳۲۔
(۲)سورئہ جمعہ آیت ۱۰۔
(۳)سورئہ قصص آیت ۷۷۔
''اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جائو''
لہٰذا بنیادی طورپر انسان کی حرکت خدا اور آخرت کے جانب ہونا چاہئیے مگر دنیا میں اپنے حصہ کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہئیے۔
۲۔اس وضاحت کے باوجود مسئلہ مکمل طورپر حل نہیں ہوجاتا کیونکہ دنیا اور آخرت کا ٹکرائو صرف محرمات کی حد تک نہیں ہے بلکہ حلال چیزوں میں بھی یہ ٹکڑائوپایا جاتا ہے ۔
امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں :
(ان الدنیاوالآخرةعدوّان متفاوتان،وسبیلان مختلفان،فمن أحبّ الدنیا وتولّاها أبغض الآخرةوعاداها،وهمابمنزلةالمشرق والمغرب،وماشٍ بینهماکلما قرب من واحد بَعُدَ من الآخر،وهمابعدضرّتان! )( ۱ )
''یاد رکھو دنیا و آخرت آپس میں دو ناسازگار دشمن ہیں اور دو مختلف راستے ۔لہٰذا جو دنیا سے محبت اور تعلق خاطررکھتا ہے وہ آخرت کا دشمن ہوجاتا ہے اور یہ دونوں مشرق ومغرب کی طرح ہیں کہ جو راہرو ایک سے قریب تر ہوتا ہے وہ دوسرے سے دورتر ہوجاتا ہے پھریہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی سوت جیسی ہیں ''
انسان اس دنیا کی نعمتوں اور حلال لذتوں سے چاہے جتنااستفادہ کرلے خدا اسے سزا نہیں دے سکتا کیونکہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیںالبتہ جتنا دنیا میں نعمتوں سے استفادہ کرتا جائے گا اسی مقدار میں جنت کی نعمتوں سے محروم ہوتاجائے گاکیونکہ لذائذ دنیا سے استفادہ کرنے کی وجہ سے آخرت کو پانے کے مواقع کم ہوتے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حلال لذتوں کے اعتبار سے بھی دنیا وآخرت میں ٹکرائو پایاجاتا ہے مندرجہ ذیل چند مثالوں کے ذریعہ اس بات کی وضاحت ہوجائے گی ۔
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت ۱۰۰۔
۱۔ﷲ نے بندوں کوجو معین عمرعطا فرمائی ہے اس میں انسان مسلسل روزے رکھ سکتا ہے روزہ اگر چہ صرف ماہ رمضان میں ہی واجب ہے لیکن سال کے بقیہ دنوں میں مستحب ہی نہیں بلکہ''مستحب مؤکد ''ہے ۔
امام محمد باقر نے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے حوالہ سے خداوند عالم کا یہ قول نقل کیا ہے ۔
(الصوم لی وأنا اجزی به )( ۱ )
''روزہ میرے لئے ہے اورمیں ہی اسکی جزادوں گا ''
اس طرح سال کے دوران روزہ چھوڑدینے سے انسان کتنے عظیم ثواب سے محروم ہوتا ہے ؟ اسے خدا کے علاوہ کوئی نہیںجانتا ۔اب انسان جس دن بھی روزہ نہ رکھکرﷲکی جائزاور حلال نعمتیں استعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ جنت کی کتنی نعمتوںسے محروم ہواہے ؟اسکا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے اگر چہ یہ طے ہے کہ جو کچھ اس نے کھایا وہ رزق حلال ہی تھا لیکن اس تھوڑے سے رزق کے باعث بہر حال آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا موقع اسکے ہاتھ سے جاتا رہا ۔حلال لذتوں کے باعث دنیا و آخرت کے درمیان ٹکرائو کی یہ ایک مثال ہے ۔
۲۔جب انسان رات میں نیند کی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے تو بلا شبہ یہ زندگانی دنیا کی حلال اور بہترین لذت ہے لیکن جب انسان پوری رات سوتے ہوئے گذاردیتا ہے تو اس رات نماز شب اور تہجد کے ثواب سے محروم رہتا ہے ۔
فرض کیجئے خدا نے کسی کو ستر برس کی حیات عطا کی ہو تو اس کے لئے ستر سال تک یہ ثواب ممکن ہے لیکن جس رات بھی نماز شب قضا ہوجاتی ہے آخرت کی نعمتوں میں سے ایک حصہ کم ہوجاتاہے اگر (خدا نخواستہ )پورے ستر سال اسی طرح غفلت میں بسر ہوجائیں تو نعمات اخروی
____________________
(۱)بحارالانوار ج۹۶ص ۲۵۴ ،۲۵۵، ۲۴۹ ۔
حاصل کرنے کا موقع بھی ختم ہوجائے گا اور پھر انسان افسوس کرے گا کہ ''اے کاش میں نے اپنی پوری عمر عبادت الٰہی میں بسر کی ہوتی ''
۳۔اگر خداوند عالم کسی انسان کومال عطا کرے تو اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرکے کافی مقدار میں اخروی نعمتیں حاصل کرنے کاامکان ہے انسان جس مقدار میںدنیاوی لذتوں کی خاطرمال خرچ کرتا ہے اتنی ہی مقدار میںآخرت کی نعمتوں سے محروم ہوسکتا ہے کہ اسی مال کو راہ خدا میں خرچ کرکے دنیا کے بجائے آخرت کی لذتیں اور نعمتیں حاصل کرسکتا تھا لہٰذا اگر انسان اپنا پورا مال دنیاوی کاموں کے لئے خرچ کردے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس مال سے اخروی نعمتیں حاصل کرنے کا موقع گنوادیا ۔چاہے اس نے یہ مال حرام لذتوں میں خرچ نہ کیا ہو ۔
اسی طرح انسان کے پاس آخرت کی لذتیں اورنعمتیں حاصل کرنے کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں ۔مال ،دولت، عمر، شباب، صحت ،ذہانت ،سماجی حیثیت اور علم جیسی خداداد نعمتوں کے ذریعہ انسان آخرت کی طیب وطاہر نعمتیں کما سکتا ہے لیکن جیسے ہی اس سلسلہ میں کو تاہی کرتا ہے اپنا گھاٹا کر لیتا ہے خدا وندعالم نے ارشاد فرما یا ہے :
( والعصرِ٭انّ الا نسان لفی خسر ) ( ۱ )
''قسم ہے عصر کی بیشک انسان خسارہ میں ہے ''
آیۂ کر یمہ نے جس گھا ٹے کا اعلان کیا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے جن چیز وں کی ضرورت ہے خداوندعالم نے وہ تمام چیزیں اپنے بندوں کو (مفت ) عطا کردی ہیں اور انھیں خدا داد نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کا بھی انتظام کردیا ہے اس کے باوجود انسان کوتاہی کرتا ہے اور ان نعمتوں کو خواہشات دنیا کے لئے صرف کر کے آخرت کما نے کا
____________________
(۱)سورئہ عصر آیت۱۔۲۔
موقع کھودیتا ہے تو یقیناگھاٹے میں ہے ۔
اس صور ت حال کی منظر کشی امیر المو منین حضرت علی نے بہت ہی بلیغ انداز میں فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے :
(واعلم أن الد نیاداربلیّة،لم یفرغ صاحبها فیها قط ساعة لاکانت فرغته علیه حسرة یوم القیامة )( ۱ )
''آگاہ ہو جا ئو یہ دنیا دار ابتلاہے اس میںا گر کوئی ایک ساعت بے کار رہتا ہے تو یہ ایک ساعت کی بے کاری روز قیامت حسرت کا باعث ہوگی''
یہاں بے کاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذکر خدا نہ کرے اور اسکی خوشنودی کے لئے کوئی عمل نہ بجالا ئے اور اسکے اعضاء وجوارح بھی قربت خدا کے لئے کوئی کام نہ کر رہے ہوں یا یاد خدا میں مشغول نہ ہوں ۔
اب اگر ایک گھنٹہ بھی اس طرح خالی اوربے کار رہے چاہے اس دوران کوئی گنا ہ بھی نہ کرے تواسکی بناپر قیامت کے دن اسے حسرت کا سامناکرنا ہوگا اس لئے کہ اس نے عمر ،شعور اور قلب جیسی نعمتوں کو معطل رکھا اورانہیں ذکرو اطاعت خدا میں مشغول نہ رکھ کر اس نے رضا ئے خدا اور نعمات اخروی حاصل کرنے کا وہ موقع گنوادیا ہے جسکا تدارک قطعا ممکن نہیں ہے بعد میں چاہے وہ جتنی اخروی نعمتیں حاصل کرلے لیکن یہ ضائع ہوجانے والا موقع بہر حال نصیب نہ ہوگا ۔
۳۔سنت الٰہی یہ ہے کہ انسان ترقی وتکامل اور قرب الٰہی کی منزلیں سختیوں اورمصائب کے ذریعہ طے کر تا ہے ۔ارشاد الٰہی ہے :
( أحَسِبَ الناس أن یُترکوا أن یقولواآمنّا وهم لایُفتنون ) ( ۲ )
____________________
(۱) نہج البلاغہ مکتوب ۵۹۔
(۲)سورئہ عنکبوت آیت۲۔
''کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دئے جائیں گے کہ و ہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا''
دوسرے مقام پرارشاد ہوتا ہے :
( ولنبلونّکم بشیٔ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات ) ( ۱ )
''اور ہم یقیناتمہیں تھوڑاخوف تھوڑی بھوک اور اموال ونفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے ۔۔۔''
نیزارشاد خداوندی ہے :
( فأخذناهم بالبأساء والضرّاء لعلهم یتضرّعون ) ( ۲ )
''۔۔۔اسکے بعد ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑگڑائیں''
یہ آخری آیت واضح الفاظ میں ہمارے لئے خدا کی طرف انسانی قافلہ کی حرکت اور ابتلاء وآز مائش ،خوف، بھوک اور جان ومال کی کمی کے درمیان موجود رابطہ کی تفسیر کر رہی ہے کیونکہ تضرع وزاری قرب الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے اور تضرع کی کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان جان ومال کی کمی، بھوک ،خوف اور شدائد ومصائب میں گرفتار ہوتاہے اس طرح انسان کے پاس دنیاوی نعمتیں جتنی زیادہ ہو ں گی اسی مقدار میں اسے تضرع سے محرومی کاخسارہ اٹھانا پڑے گا اور نتیجتاً وہ قرب الٰہی کی سعادتوں اور اخروی نعمتوں سے محروم ہوجا ئے گا ۔
زندگانی دنیا کے مصائب ومشکلات کبھی تو خدا اپنے صالح بندوں کو مرحمت فرماتا ہے تا کہ وہ تضرع وزاری کیلئے آمادہ ہوسکیں اور کبھی اولیائے الٰہی اوربند گان صالح خود ہی ایسی سخت زندگی
____________________
(۱)سورئہ بقرہ آیت۱۵۵۔
(۲)سورئہ انعام آیت ۴۲۔
کواختیار کر لیتے ہیں ۔
۴۔لذائذ دنیا سے کنار کشی کا ایک سبب یہ ہو تا ہے کہ انسان کبھی یہ خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں لذائذ دنیا کا عادی ہوکر وہ بتدریج حب دنیا میں مبتلا نہ ہو جا ئے اوریہ حب دنیاا سے خدا اور نعمات اخروی سے دور نہ کردے ۔اس لئے کہ لذائذ دنیا اورحب دنیا میں دوطرفہ رابطہ پایا جاتا ہے یہ لذ تین انسان میںحب دنیا کا جذبہ پیدا کر تی ہیں یااس میں شدت پیدا کر دیتی ہیں اس کے بر عکس حب دنیا انسان کودنیاوی لذتوں کو آخرت پر ترجیح دینے اوران سے بھر پور استفادہ کرنے بلکہ اسکی لذتوں میںبالکل ڈوب جانے کی دعوت دیتی ہے ۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان لا شعوری طور پر حب دنیا کا شکار ہو جائے لہٰذا لذائذ دنیاسے ہو شیار رہنا چاہئے کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ لذتین اسے اسکے مقصد سے دور کردیں ۔
۵۔کبھی ہمیں روایات میں ایسی بات بھی نظر آتی ہے کہ جو مذ کور ہ وضاحتوں سے الگ ہے جیسا کہ مولا ئے کائنات حضرت علی نے جناب محمدبن ابی بکر کو مصر کا حاکم مقرر کرتے وقت (عہد نامہ میں)ان کے لئے یہ تحریر فرما یاتھا:
(واعلمواعبادﷲأن المتّقین ذهبوا بعاجل الدنیا وآجل الآخرة ،۔۔۔)( ۱ )
''بندگان خدا !یا د رکھو کہ پرہیزگار افراد دنیا اور آخرت کے فوائد لے کرآگے بڑھ گئے ۔وہ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے لیکن اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک نہ ہوسکے۔وہ دنیا میں بہترین انداز سے زندگی گذار تے رہے جو سب نے کھایا اس سے اچھاپاکیزہ کھانا کھایااور وہ تمام لذتیںحاصل کرلیں جو عیش پرست حاصل کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پالیا جو جابراور متکبر افراد کے حصہ میں آتا ہے ۔اسکے بعد وہ زادراہ لے کر گئے جو منزل تک پہونچادے اور وہ تجارت کرکے گئے
____________________
(۱)نہج البلا غہ مکتوب ۲۷۔
جس میں فائدہ ہو۔دنیا میں رہ کر دنیا کی لذت حاصل کی اور یقین رکھے رہے کہ آخرت میں پروردگار کے جوار رحمت میں ہوںگے۔جہاں نہ ان کی آواز ٹھکرائی جائے گی اور نہ کسی لذت میں ان کے حصہ میں کوئی کمی ہوگی''
ان جملات میں متقین اور غیر متقین کا مواز نہ کیا گیا ہے جبکہ جن روایات کا ہم تجز یہ پیش کررہے تھے انمیں درجات متقین کا مو از نہ ہے،نہ کہ متقین اور غیر متقین کا!ظا ہر ہے کہ یہ دو نوں الگ ا لگ چیزیں ہیں لہٰذا ان دو نوں کا حکم بھی الگ ہو گا ۔
با طن بیں نگاہ
دنیا کے بارے میں سر سری اور سطحی نگاہ سے ہٹ کر ہم دنیا پر زیادہ گہرائی اور سنجیدگی کے سا تھ نظر کر سکتے ہیں ۔جسے ہم (الرؤ یة النافذة) کا نام دے سکتے ہیں اس رویت میں ہم دنیا کے ظاہر سے بڑ ھ کر اس کے با طن کا نظارہ کر سکتے ہیں ۔ جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کا ظا ہراگر حبّ دنیا کی طرف لے جا تا ہے اور انسان کو فر یب دیتا ہے تو اس کے بر خلا ف دنیا کا باطن انسان کو زہداور دنیا سے کنارہ کشی کی دعوت دیتا ہے ۔باطن بیں نگاہ ظا ہر سے بڑھکر دنیا کی اندرو نی حقیقت کو عیاں کر کے یہ بتا تی ہے کہ متاع دنیا بہر حال فنا ہو جا نے والی ہے نیز یہ کہ انسان کا دنیا میں انجام کیا ہو گا ؟ یوں انسان خو د بخود زہدا ختیار کر لیتا ہے ۔
روایات میںکثرت سے یہ تا کید کی گئی ہے کہ دنیا کو اس (نظر) سے دیکھنا چا ہئے، انسان مو ت کی طرف متو جہ رہے اورہمیشہ مو ت کو یاد رکھے، طویل آرزووں اور مو ت کی طرف سے غا فل ہو نے سے منع کیا گیاہے ۔
مو ت در اصل اس با طنی دنیا کا چہرہ ہے جس سے انسان فرار کرکے موت کو بھلا نا چا ہتا ہے چنا نچہ روایت میں وارد ہو ا ہے کہ (موت سے بڑھ کر کو ئی یقین ، شک سے مشا بہ نہیں ہے ) اس لئے کہ موت یقینی ہے ،اسمیں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس کے با وجود انسان اس سے گر یزاں ہے
اور اسے بھلا ئے رکھنا چا ہتا ہے ۔
حا لا نکہ روایات میں اس کے با لکل بر عکس نظر آتا ہے امام محمد با قر کا ارشاد ہے:
(أکثروا ذکرالموت، فانه لم یُکثرالانسان ذکرالموت الازهد فی الدنیا )( ۱ )
'' مو ت کو کثرت سے یا د کرو کیو نکہ انسان جتنا کثرت سے موت کو یا د کر تا ہے اس کے زہد میں اتنا ہی اضا فہ ہو تا ہے''
امیر امو منین حضرت علی کا ار شاد گر امی ہے :
(من صوّرالموتَ بین عینیه هان أمرالدنیا علیه )( ۲ )
''جس کی نگا ہوں کے سا منے مو ت ہو تی ہے دنیا کا مسئلہ اس کے لئے آسان ہو تا ہے''
آپ ہی کا ار شاد ہے :
(أحقّ الناس بالزهادة من عرف نقص الدنیا )( ۳ )
''جو دنیا کے نقائص سے آگاہ ہے وہ زہد کا زیادہ حقدار ہے ''
امام مو سیٰ کا ظم کا ارشاد ہے:
(ان العقلاء زهدوا فی الدنیا،ورغبوا فی الآخرة ۔۔۔)( ۴ )
''بے شک صاحبان عقل دنیا میں زاہد اور آخرت کی جا نب راغب ہو تے ہیں انھیں معلوم ہے کہ دنیا طالب بھی ہے مطلوب بھی ،اسی طرح آخرت بھی طالب اور مطلوب ہو تی ہے ۔جو آخرت کا طلبگار ہو تا ہے اسے دنیا طلب کرتی ہے اور اپنا حصہ لے لیتی ہے ۔جو دنیا کا طلبگار ہو تا ہے آخرت اس
____________________
(۱) بحارالانوار ج۷۳ص۶۴۔
(۲)غرر الحکم ج۲ص۲۰۱۔
(۳) غرر الحکم ج۱ص۱۹۹۔
(۴)بحارالانوار ج ۷۸ ص ۳۰۱۔
کی طالب ہو تی ہے پھر جب مو ت آتی ہے تو اس کی دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جا تی ہیں ''
روا یت میں ہے کہ امام مو سی ٰ کا ظم ایک جنا زہ کے سر ہا نے تشریف لا ئے تو فر ما یا:
(ان شیئاً هذا أوّله لحقیق أن یُخاف آخره )( ۱ )
''جس چیز کا آ غازیہ (مر دہ لاش )ہو اس کے انجام کا خوف حق بجا نب ہے ''
ان روا یات میں ذکر مو ت اور زہد کے در میان واضح تعلق نظر آ تا ہے بالفاظ دیگران روایات میںنظر یہ یاتھیوری اورپریکٹیکل کے در میان تعلق کو ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ موت کا ذکر اور اسے یاد رکھنا ایک قسم کا نظر یہ اور تھیوری ہے اور زھد اس نظریہ کے مطابق راہ وردش یاپر یکٹیکل کی حیثیت رکھتا ہے امیر المو منین حضرت علی لوگوں کو دنیا کے بارے میں صحیح اور حقیقی نظریہ سے روشناس کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :
(کونواعن الدنیا نُزّاها،والیٰ الآخرة ولّاهاولاتشیموا بٰارقها،ولا تسمعواناطقها،ولاتجیبواناعقها،ولاتستضیئواباشراقها،ولاتفتنواباعلاقها،فن برقهاخالب،ونطقهاکاذب ،واموالها محروبة،واعلاقها مسلوبة )( ۲ )
''دنیا سے پاکیزگی اختیار کرو اور آخرت کے عاشق بن جائو۔۔۔ اس دنیا کے چمکنے والے بادل پر نظر نہ کرو اور اسکے ترجمان کی بات مت سنو ،اسکے منادی کی بات پر لبیک مت کہو اور اسکی چمک د مک سے روشنی مت حاصل کرو اور اسکی قیمتی چیزوں پر جان مت دو اس لئے کہ اسکی بجلی فقط چمک دمک ہے اور اسکی باتیں سراسر غلط ہیں اسکے اموال لٹنے والے ہیں اور اسکا سامان چھننے والا ہے ''
آپ ہی کاارشاد گرامی ہے:
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۸ ص۳۲۰ ۔
(۲)نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۱ ۔
(وأخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم )( ۱ )
''دنیا سے اپنے دلوں کو نکال لو قبل اس کے کہ تمہارے بدن دنیا سے نکالے جائیں ''
دنیا سے دل نکال لینے کا مطلب ،دنیا سے قطع تعلق کرنا ہے جسے ہم (ارادی اور اختیاری موت)کا نام دے سکتے ہیں اس کے بالمقابل( قہری اور غیر اختیاری موت )ہے جسمیں ہمارے بدن دنیا سے نکالے جائیں گے ۔امام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قہری موت سے پہلے ارادی موت اختیارکرلیں اور دنیا سے قطع تعلق کا ہی دوسرا نام ''زہد''ہے ۔۔۔دنیا کے باطن کو دیکھنے والی نظر اور زہد سے اسکے رابطہ کو سمجھنے کے لئے خود زہد کے بارے میںجاننااور گفتگوکرنا ضروری ہے ۔
زہد
زہد،حب دنیا کے مقابل حالت ہے ۔طور وطریقہ اور سلوک کی یہ دونوں حالتیں دو الگ الگ نظریوں سے پیداہوتی ہیں ۔
حب دنیا کی کیفیت اس وقت نمودار ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا کے فقط ظاہرپر نظر رکھتا ہے اس کے بر خلاف اگر انسان کی نظر دنیا کے باطن کو بھی دیکھ رہی ہے تو اس سے زہد کی کیفیت جنم لیتی ہے ۔
چونکہ حب دنیا کا مطلب دنیا سے تعلق رکھنا ہے اور زہد اس کے مقابل کیفیت کا نام ہے تو زہد کا مطلب ہوگا دنیا سے آزاد البتہ اس کے معنی کی وضاحت ضروری ہے ۔حب دنیا کے مفہوم کو سمیٹ کر دو لفظوں میںیوں بیان کیا جاسکتا ہے :
۱۔فرحت ومسرت
۲۔حزن وملال
حب دنیا کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کولذائذ دنیا میں جب کچھ بھی نصیب ہو تا ہے تووہ خوش
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۴۔
ہوجاتا ہے اور جب وہ کسی نعمت سے محروم رہتا ہے یااس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تووہ محزون ہوجاتاہے چونکہ زہد حب دنیا کے مقابل کیفیت کا نام ہے لہٰذا زہد کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا سے اتنا آزاداور بے پرواہ ہوکہ دنیا میں سب کچھ مل جانے پربھی خوشی محسوس نہ کرے اور کچھ بھی نہ ملنے پر مغموم و محزون نہ ہو ۔
خدا وند عالم فر ماتا ہے :
(۔۔۔لکیلا تحزنوا علیٰ مافاتکم ولامااصابکم ۔۔۔)( ۱ )
''۔۔۔تاکہ تم نہ اس پر رنجیدہ ہو جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اور نہ اس مصیبت پر جو نازل ہوگئی ہے ۔۔۔''
دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے :
(۔۔۔لکیلا تاسوا علیٰ مافاتکم ولا تفرحوا بماآتاکم ۔۔۔)( ۲ )
''تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اسکا افسوس نہ کرو اور جو مل جائے اس پر غروراور فخر نہ کرو ۔۔۔''
امیر المو منین حضرت علی سے مروی ہے :
(الزهدکله فی کلمتین من القرآن )
''پورا زہد قرآن کے دو لفظوں میں سمٹا ہوا ہے جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے :
(لکیلا تأسواعلیٰ مافاتکم )( ۳ )
''تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اسکا افسوس نہ کرو''
____________________
(۱)سورئہ آل عمران آیت ۱۵۳۔
(۲)سورئہ حدید آیت۲۳۔
(۳)سورئہ حدید آیت ۲۳۔
(فمن لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآ تی فهوالزاهد )( ۱ )
جو انسان ماضی پرافسوس نہ کرے اور ہاتھ آجانے والی چیز پر خوش نہ ہووہ زاہد ہے ''
ایک دوسرے مقام پر آپ سے روایت ہے :
''الزهدکلمة بین کلمتین من القرآن قال اللّٰه:(لکیلا تأسوا)فمن لم یأس علیٰ الماضی،ولم یفرح بالآ تی،فقد اخذ الزهد بطرفیه ''( ۲ )
''زہد قرآن کے دو لفظوں کا مجمو عہ ہے خدا وند عالم فر ماتا ہے :
(لکیلا تأسوا ۔۔۔)''تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اسکا افسوس نہ کرو''
لہٰذاجو انسان ماضی پر افسوس نہ کرے اور ہاتھ آجانے والی چیز پر خوش نہ ہو اس نے پورا زہد حاصل کرلیا ہے ''
امیرالمو منین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(من اصبح علی الدنیا حزیناً،فقد أصبح لقضاء اللّٰه ساخطاً،ومن لهج قلبه بحب الدنیاالتاط قبله منها بثلاث:همّ لایُغِبُّه،وحرص لایترکه،وأمل لایدرکه )( ۳ )
''جو دنیا کے بارے میں محزون ہو گا وہ قضا و قدر الٰہی سے ناراض ہو گا جس کا دل محبت دنیا کا دلدادہ ہوجائے اسکے دل میں یہ تین چیزیں پیوست ہوجاتی ہیں وہ غم جو اس سے جدا نہیں ہوتا ہے ،وہ لالچ جو اسکا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے وہ امید جسے وہ کبھی حاصل نہیں کرسکتا ہے ''
یہ بھی حزن و فر حت سے آزادی کا ایک رخ ہے کہ دنیا کے بارے میں حزن وملال ،قضا وقدر الٰہی سے ناراضگی کے باعث ہوتا ہے اس لئے کہ انسان دنیا میں جن چیزوں سے بھی محروم ہوتا
____________________
(۱)بحا ر الانوار ج ۷۸ ص ۷۰۔
(۲)بحارالانوار ج ۷۰ ص ۳۲۔
(۳)نہج البلاغہ حکمت ۲۲۸۔
ہے وہ در حقیقت قضا وقدر الٰہی کے تحت ہی ہوتا ہے نیز حب دنیا انسان میں تین صفتیں پیدا کرتی ہے ہم وغم ،حرص وطمع، آرزو۔ اس طرح وہ انسان کو ظلم وستم اور عذاب کے پنجوں میں جکڑدیتی ہے ۔
امیر المومنین حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا :
(ایهاالناس انماالدنیا ثلا ثة:زاهدوراغب وصابر،فأماالزاهدفلا یفرح بشیٔ من الدنیا أتاه،ولایحزن علیٰ شیٔ منها فاته وامّاالصابرفیتمنّاها بقلبه،فان ادرک منهاشیئاصرف عنها نفسه،لما یعلم من سوء عاقبتها وامّا الراغب فلایبالی من حِلٍّ اصابها أم من حرام )( ۱ )
''اے لوگو: دنیا کے افرادتین قسم کے ہیں :۱۔زاہد ۲۔صابر ۳۔راغب
۱۔زاہد وہ ہے جو کسی بھی چیز کے مل جانے سے خوش یا کسی بھی شے کے نہ ملنے سے محزون نہیں ہوتا ۔صابر وہ ہے جو دل ہی دل میں دنیا کی تمنا تو کرتا ہے لیکن اگر اسے دنیا مل جاتی ہے تو چونکہ اسکے برے انجام سے واقف ہے لہٰذا اپنامنھ اس سے پھیر لیتا ہے اور راغب وہ ہے کہ جسے یہ پروا نہیں ہے کہ اسے دنیا حلال راستہ سے مل رہی ہے یا حرام راستہ سے ''
زہدکے معنی ،لوگوں کی تین قسموںاور ان قسموں پر زاہد ین کی تقسیم کے سلسلہ میں یہ حدیث عالی ترین مطالب کی حامل ہے ۔اسکے مطابق لوگوں کی تین قسمیں ہیں :
زاہد ،صابر اور راغب۔
زاہد وہ ہے کہ جو دنیا اور اسکی فرحت وملال سے آزاد ہو۔
صابر وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے آزاد تو نہیں ہے مگر حب دنیا ،دنیاوی فرحت ومسرت اور حزن وملال سے نجات پانے کے لئے کوشاںہے ۔
____________________
(۱)بحارالانوار ج۱ص۱۲۱۔
راغب وہ ہے کہ جو دنیا کا اسیر اور اسکی فرحت ومسرت اور حزن و ملال کے آگے سرتسلیم خم کئے ہوئے ہے۔
ان میں پہلا اور تیسراگروہ ایک دوسرے کے بالکل مقابل ہے کہ ایک مکمل طریقہ سے آزاد اور دوسراہر اعتبار سے مطیع و اسیرجبکہ تیسرا گروہ درمیانی ہے ۔
امیر المومنین حضرت علی لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی فرحت و ملال کا رخ دنیا سے آخرت کی جانب موڑدیں یہی بہترین چیز ہے کیونکہ اگر ہماری کیفیت یہ ہوکہ ہم اطاعت خدا کرکے خوشی محسوس کریں اور اطاعت سے محرومی پر محزون ہوں تو یہ بہترین بات ہے اس لئے کہ اس خوشی اورغم کا تعلق آخرت سے ہے ۔
مولائے کائنات حضرت علی، ا بن عباس کے نام اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:
''اما بعد !انسان کبھی کبھی ایسی چیز کو پاکر بھی خوش ہوجاتا ہے جو ہاتھ سے جانے والی نہیںتھی اور ایسی چیز کو کھوکر رنجیدہ ہوجاتا ہے جو ملنے والی نہیں تھی لہٰذا خبر دار تمہارے لئے دنیا کی سب سے بڑی نعمت، کسی لذت کا حصول یا جذبۂ انتقام ہی نہ بن جائے بلکہ بہترین نعمت باطل کو مٹانے اور حق کو زندہ کرنے کو سمجھو اور تمہیں ان اعمال سے خوشی ہو جنہیں پہلے بھیج دیا ہے اور تمہارا افسوس ان امور پر ہو جنہیں چھوڑکر چلے گئے ہو اور تمام تر فکر موت کے مرحلہ کے بارے میں ہونی چاہئیے''( ۱ )
زہد،تمام نیکیوں کا سرچشمہ
جس طرح حیات انسانی میں حب دنیا تمام برائیوں کی جڑہے اسی طرح تمام نیکیوں اور اچھائیوں کا سرچشمہ ''زہد''ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حب دنیا انسان کو دنیا اور اسکی خواہشات کا اسیر بنادیتی ہے اور دنیا خود تمام برائیوں اور پستیوں کی بنیاد ہے لہٰذا حب دنیابھی انسان کو برائیوںاور
____________________
(۱)نہج البلاغہ مکتوب ۶۶۔
پستیوں کی طرف لے جاتی ہے جبکہ زہد کا مطلب ہے دنیااور خواہشات دنیا سے آزاد ہونا اور جب انسان برائیوں کی طرف لے جانے والی دنیا سے آزاد ہوگا تو اسکی زندگی خود بخود نیکیوں اور اچھائیوں کا سرچشمہ بن جائے گی ۔
روایات معصومین میں اس چیز کی طرف متعدد مقامات پر مختلف اندازسے اشارہ کیا گیا ہے بطور نمونہ ہم یہاں چند احادیث پیش کر رہے ہیں۔
امام صادق کا ارشاد ہے:
(جُعل الخیرکله فی بیت وجُعل مفتاحه الزهد فی الدنیا )( ۱ )
''تمام نیکیاں ایک گھر میں قرار دی گئی ہیں اور اسکی کنجی دنیا کے سلسلہ میں زہد اختیار کرنا ہے ''
امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(الزهد أصل الدین )( ۲ )
''دین کی اصل، زہد ہے ''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(الزهد اساس الدین )( ۳ )
''دین کی اساس اور بنیاد، زہد ہے ''
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :
(الزهد مفتاح باب الآخرة،والبرا ئة من النار،وهو ترکک کل شیٔ
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۳ص۴۹۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۲۹۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۳۰۔
یشغلک عن اللّٰه من غیرتأسف علیٰ فوتها ولا أعجاب فی ترکها،ولاانتظارفرج منها،ولاطلب محمدة علیها،ولاعوض منهابل تریٰ فواتهاراحة،وکونهاآفة،وتکون أبداً هارباً من الآفة،معتصماً بالراحة )( ۱ )
''زہد،باب آخرت کی کنجی اورجہنم سے نجات کا پروانہ ہے ۔زہد کا مطلب یہ ہے کہ تم ہراس چیز کو ترک کردو جو تمہیں یاد خدا سے غافل کردے اور تمہیں اسکے چھوٹ جانے کا نہ کوئی افسوس ہو اور نہ اسے ترک کرنے میں کوئی زحمت ہو ۔اس کے ذریعہ تمہاری کشادگی کی توقع نہ ہو،نہ ہی اس پر تعریف کی امید رکھو، نہ اسکا بدلہ چاہو بلکہ اسکے فوت ہوجانے میں ہی راحت اور اسکی موجود گی کو آفت سمجھوایسی صورت میں تم ہمیشہ آفت سے دوراورراحت وآرام کے حصارمیںرہو گے''
حضرت علی نے فرمایا ہے :
(الزهد مفتاح الصلاح )( ۲ )
''زہد صلاح کی کنجی ہے ''
زہد کے آثار
حیات انسانی میں زہد کے بہت عظیم آثار و نتائج پائے جاتے ہیں جنہیں زاہد کے نفس اور اسکے طرز زندگی میں بخوبی محسوس کیا جاسکتا ہے ۔
۱۔آرزووں میں کمی
حب دنیا کا نتیجہ آرزووں کی کثرت ہے اور زہد کا نتیجہ آرزووں میں کمی۔ جب انسان کا تعلق دنیا سے کم ہو اوروہ خواہشات دنیا سے آزاد ہوتو طبیعی طور پر اسکی آرزوئیں بھی مختصر ہوںگی وہ دنیا میں
____________________
(۱) بحا ر الا نو ا ر ج ۰ ۷ ص۳۱۵۔
(۲)غررالحکم ص۹۹،۳۷۔۸۔
زندگی بسر کرے گا متاع زندگانی اوردنیاوی لذتوںسے استفادہ کرے گا لیکن ہمیشہ موت کو بھی یاد رکھے گا اور اسی طرح یہ بات بھی اسکے پیش نظر رہے گی کہ ان چیز وں کا سلسلہ کسی بھی وقت اچانک ختم ہوجائے گا۔
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ارشاد ہے :
(من یرغب فی الدنیا فطال فیها أمله،أعمیٰ ﷲ قلبه علیٰ قدررغبته فیها، ومن زهد فیها فقصرفیهاأمله،أعطاه ﷲعلماًبغیرتعلّم،وهدیً بغیرهدایة،وأذهب عنه العمائ،وجعله بصیرا )( ۱ )
''جو شخص دنیا کی طرف راغب ہوتاہے اسکی آرزوئیں طولانی ہوتی ہیں اور دنیا کی طرف اسکی رغبت کے مطابق ﷲ اسکے قلب کو اندھا کردیتاہے اور جو دنیا میں زاہد ہوتاہے اسکی آرزوئیں مختصر ہوتی ہیں اور ﷲ اسے تعلیم کے بغیر علم اوراسباب ہدایت کے بغیر ہدایت عطا کرتاہے۔اوراس سے اندھے پن کو دور کرکے اسکو بصیر بنا دیتاہے ''
اس روایت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ زہد ،سے آرزوئیںکم ہوجاتی ہیں اور اس کمی سے بصیرت اورہدایت ملتی ہے اسکے برعکس دنیا کی جانب رغبت سے آرزووں میں کثرت پیدا ہوتی ہے اور یہ کثرت اندھے پن کا سبب ہے تو آخر آرزووں کی قلت اور بصیرت کے درمیان کیا تعلق ہے ؟
اسکا راز یہ ہے کہ طویل آرزوئیںانسان کو دنیا میں اس طرح جکڑدیتی ہیں کہ انسان اس سے بیحدمحبت کرنے لگتا ہے اوردنیاکی محبت ا انسان اور خدا کے درمیان حجاب بن جاتی ہے اور جب آرزوئیں مختصر ہوتی ہیں تو یہ حجاب اٹھ جاتا ہے۔اور ظاہر ہے کہ جب قلب کے حجابات دور ہوجائیں گے تواس میں بصیرت پیدا ہوجائے گی ۔
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ارشاد گرامی ہے :
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۷ص۲۶۳۔
(الزهد فی الدنیا قصرالأمل،وشکرکل نعمة،والورع عن کل ماحرّم ﷲ )( ۱ )
''دنیا میں زہد کا مطلب یہ ہے کہ آرزوئیں قلیل ہوں،ہر نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور محرمات الٰہی سے پرہیز کیا جائے''
امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(الزهد تقصیرالآمال،واخلاص الاعمال )( ۲ )
''آرزووںمیںکمی اور اعمال میں خلوص کا نام زہد ہے ''
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :
(أیهاالناس،الزهادة قصرالأمل،والشکرعندالنعم،والتورع عندالمحارم،فانْ عزب ذلک عنکم،فلایغلب الحرام صبرکم،ولاتنسواعندالنعم شکرکم،فقدأعذرﷲالیکم بحججٍ مسفرةظاهرة،وکتبٍ بارزةالعذرواضحة )( ۳ )
''اے لوگوں:زہد امیدوں کے کم کرنے ،نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے اور محرمات سے پرہیز کرنے کا نام ہے ۔اب اگر یہ کام تمہارے لئے مشکل ہوجائے تو کم ازکم اتنا کرناکہ حرام تمہاری قوت برداشت پر غالب نہ آنے پائے اور نعمتوں کے موقع پر شکر کو فراموش نہ کردینا کہ پروردگار نے نہایت درجہ واضح اور روشن دلیلوں اور حجت تمام کرنے والی کتابوں کے ذریعہ تمہارے ہر عذر کا خاتمہ کردیا ہے ''
۲۔دنیاوی تاثرات سے نجات اورآزادی
دنیاوی نعمتیں ملنے سے نہ انسان خوشی محسوس کرے گا اور نہ ان سے محرومی پر محزون ہوگا ۔
امیرالمومنین حضرت علی کا ارشاد ہے :
____________________
(۱)بحارالانوارج۷۷ص۱۶۶۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۹۳۔
(۳)نہج البلاغہ خطبہ ۸۱۔
(فمن لم یأس علیٰ الماضی،ولم یفرح بالآ تی فقد أخذ الزهد بطرفیه )( ۱ )
''جو شخص ماضی پر افسوس نہ کرے اور ہاتھ آنے والی چیزوں سے مغرور نہ ہوجائے اس نے سارا زہدسمیٹ لیا ہے ''
امیر المومنین کے ہر کلام کی مانند حیات انسانی میں زہد کے نتائج کے بارے میں شاہکار کلام پایا جاتا ہے ہم یہاں اس کلام کو نہج البلاغہ سے نقل کر رہے ہیں ۔''اپنے کانوں کو موت کی آواز سنادو قبل اسکے کہ تمہیں بلالیاجائے دنیا میں زاہدوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل روتا رہتاہے اور وہ ہنستے بھی ہیںتوان کا رنج و اندوہ شدیدہوتاہے۔وہ خود اپنے نفس سے بیزاررہتے ہیںچاہے لوگ ان کے رزق سے غبطہ ہی کیوں نہ کریں ۔افسوس تمہارے دلوں سے موت کی یاد نکل گئی ہے اور جھوٹی امیدوں نے ان پر قبضہ کرلیا ہے۔اب دنیا کا اختیار تمہارے اوپر آخرت سے زیادہ ہے اور وہ عاقبت سے زیادہ تمہیں کھینچ رہی ہے ۔تم دین خدا کے اعتبار سے بھائی بھائی تھے۔ لیکن تمہیں باطن کی خباثت اور ضمیر کی خرابی نے الگ الگ کردیا ہے کہ اب نہ کسی کا بوجھ بٹاتے ہو۔نہ نصیحت کرتے ہو۔نہ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہواور نہ ایک دوسرے سے واقعاًمحبت کرتے ہو۔آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ معمولی سی دنیا کو پاکر خوش ہوجاتے ہو اور مکمل آخرت سے محروم ہوکر رنجیدہ نہیں ہوتے ہو۔تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو پریشان ہوجاتے ہو اور اسکا اثر تمہارے چہروں سے ظاہر ہوجاتاہے اور اس کی علیٰحدگی پر صبر نہیں کرپاتے ہو جیسے وہی تمہاری منزل ہے اور جیسے اس کا سرمایہ واقعی باقی رہنے والا ہے۔تمہاری حالت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی دوسرے کے عیب کے اظہارسے باز نہیں آتا ہے مگر صرف اس خوف سے کہ وہ بھی اسی طرح پیش آئے گا ۔تم سب نے آخرت کو نظر انداز کرنے اور دنیا کی محبت پر اتحاد کرلیاہے اور ہر ایک کا دین زبان کی چٹنی بن کر رہ گیا
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۰ص۳۲۰،نہج البلاغہ حکمت ۴۳۹۔
ہے ۔ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب نے اپنا عمل مکمل کرلیا ہے اور اپنے مالک کو واقعا خوش کرلیا ہے۔''( ۱ )
۳۔دنیاپرعدم اعتماد
انسانی نفس کے اوپر زہد کے آثار میں سے ایک اثریہ بھی ہوتا ہے کہ زاہد کبھی بھی دنیا پر اعتماد نہیں کرتا ۔انسان جب دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کا نفس دنیا میں الجھ جاتا ہے تو وہ دنیا پر بھروسہ کرتا ہے اوردنیا کو ہی اپناٹھکانہ اوردائمی قیام گا ہ مان لیتا ہے لیکن جب انسان کے اندر زہد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اوروہ اپنے دل سے حب دنیا کونکال دیتا ہے تو پھراسے دنیا پر اعتبار بھی نہیں رہ جاتا اور وہ دنیا کو محض ایک گذرگاہ اور آخرت کے لئے ایک پُل تصور کرتاہے ۔
دنیا کے بارے میں لوگوں کے درمیان دو طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں ۔کچھ افراد دنیا کو قیام گاہ مان کر اس سے دل لگالیتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا کو گذر گاہ اور آخرت کے لئے ایک پل سمجھ کر اس سے دل نہیں لگاتے ۔دو نوںقسم کے افراد اسی دنیا میں رہتے ہیں اورخدا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں مگر ان کے درمیان فر ق یہ ہے کہ پہلے گروہ کامنظور نظر خود دنیا ہوتی ہے اور وہ اسی کو سب کچھ مانتے ہیں یہاںتک کہ موت ان سے دنیا کو الگ کردیتی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس سے دل نہیں لگاتا بلکہ اسے گذر گاہ اور پل کی حیثیت سے دیکھتا ہے لہٰذا جب موت آتی ہے تو دنیا کی مفارقت ان پر گراں نہیں گذرتی ہے۔
دنیا میں انسان کی حالت او راس میں اسکے قیام کی مدت کو روایات میں بہترین مثالوں کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے ایک مثال کے بموجب دنیامیں انسان کا قیام ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سوار راستہ میںسورج کی گرمی سے پریشان ہوکر کسی سایہ داردرخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر آرام کے بعد پھر اپنے کام کے لئے چل پڑتا ہے ۔ کیا ایسی صورت میں دنیا کو اپنا ٹھکانہ، دائمی قیام گاہ سمجھنا اور
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۱۱۳
اس سے دل لگانا صحیح ہے ؟
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ارشاد ہے :
(مالی وللدنیا،انما مَثَلی کمثل راکبٍ مرّللقیلولة فی ظلّ شجرة فی یوم صائف ثم راح وترکها )( ۱ )
''دنیا سے میرا کیا تعلق ؟میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جوتیز ہوائوں کے تھپیڑوں کے درمیان آرام کی خاطر کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور پھر اس جگہ کو چھوڑکر چل دیتا ہے ''
امیر المومنین حضرت علی نے اپنے فرزند امام حسن کو یہ وصیت فرمائی ہے :
(یابنیّ انی قدأنباتک عن الدنیا وحالها،وزوالها،وانتقالها،وأنبأتک عن الآخرةومااُعدّ لأهلها فیها،وضربتلک فیهماالأمثال،لتعتبربها، وتحذو علیها،انمامثل من خبرالدنیاکمثل قوم سفرنبا بهم منزل جذیب فأمّوا منزلاًخصیباً، وجناباً مریعاً،فاحتملواوعثاء الطریق،وفراق الصدیق،وخشونةالسفرومَثَل من اغترّبهاکمثل قوم کانوابمنزل خصیب فنبابهم الیٰ منزل جذیب،فلیس شیء أکره الیهم ولاأفضع عندهم من مفارقة ماکانوا فیه الیٰ مایهجمون علیه ویصیرون الیه )( ۲ )
''۔۔۔اے فرزند میں نے تمہیں دنیااوراسکی حالت اوراسکی بے ثباتی و ناپائیداری سے خبردار کردیا ہے ۔اور آخرت اور آخرت والوں کے لئے جو سروسامان عشرت مہیّاہے اس سے بھی آگاہ کردیا ہے اور ان دونوں کی مثالیںبھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۳ص۱۱۹۔
(۲)نہج البلاغہ مکتوب ۳۱۔
اور ان کے تقاضے پر عمل کرو۔جن لوگوں نے دنیا کو خوب سمجھ لیا ہے ان کی مثال ان مسافروںکی سی ہے جن کا قحط زدہ منزل سے دل اچاٹ ہوا،اور انھوں نے راستے کی دشواریوں کو جھیلا، دوستوںکی جدائی برداشت کی،سفر کی صعوبتیںگواراکیں،اور کھانے کی بد مزگیوںپر صبر کیاتاکہ اپنی منزل کی پہنائی اور دائمی قرارگاہ تک پہنچ جائیں ۔اس مقصد کی دھن میں انھیں ان سب چیزوں سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔اور جتنا بھی خرچ ہوجائے اس میں نقصان معلوم نہیں ہوتا۔انھیں سب سے زیادہ وہی چیز مرغوب ہے جو انہیں منزل کے قریب اور مقصدسے نزدیک کردے اور اسکے برخلاف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دنیا سے فریب کھایاان لوگوں کی سی ہے جو ایک شاداب سبزہ زار میں ہوں اور وہاں سے دل برداشتہ ہوجائیں اور اس جگہ کا رخ کرلیں جو خشک سالیوں سے تباہ ہو۔ان کے نزدیک سخت ترین حادثہ یہ ہوگا کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑکرادھر جائیںکہ جہاں انھیں اچانک پہنچناہے اور بہر صورت وہاںجاناہے ۔۔۔ ''
حضرت عمر ، پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ ایک بورئیے پر آرام فرمارہے ہیں اور آپ کے پہلو پر اسکا نشان بن گیاہے توعرض کی اے نبی خدا:
(یانبیّ ﷲ،لواتخذت فراشاً أوثر منه؟فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم :مالی وللدنیا،مامَثلی ومثَل الدنیا الاکراکب سارفی یوم صائف فاستظلّ تحت شجرة ساعة من نهار،ثم راح وترکها )( ۱ )
اگر آپ اس سے بہتربستر بچھالیتے تو کیا تھا ؟پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا :''دنیا سے میرا کیا تعلق؟میری اور دنیا کی مثال ایک سوار کی سی ہے جوتیز ہوائوں کے درمیان چلا جارہا ہو اور دن میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے کسی سایہ داردرخت کے نیچے رک جائے اور پھر اس جگہ کوچھوڑ کرآگے بڑھ جائے''
____________________
(۱)بحارالانوارج ۷۳ص۱۲۳۔
امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(ان الدنیالیست بدارقرارولامحلّ اقامة،انّما أنتم فیهاکرکب عرشوا وارتاحوا،ثم استقلّوا فغدوا وراحوا،دخلوهاخفافاً،وارتحلواعنها ثقالاً،فلم یجدواعنهانزوعاً،ولاالی ما ترکوبهارجوعاً )( ۱ )
''یہ دنیا دار القرار اور دائمی قیام گا ہ نہیں ہے تم یہاں سوار کی مانند ہو 'جنہوں نے کچھ دیرکیلئے خیمہ لگایا اور پھر چل پڑے پھر دوسری منزل پر تھوڑا آرام کیا اور صبح ہوتے ہی کوچ کر گئے ، ہلکے پھلکے (آسانی سے)اترے اور لاد پھاندکر مشکل سے روانہ ہوئے نہ انہیں اسکا کبھی اشتیاق ہوا اور جس کو ترک کرکے آگئے نہ اسکی طرف واپسی ممکن ہوئی ''
نبی اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا :انسان دنیا میں کیسے زندگی بسر کرے ؟آپ نے فرمایا جیسے قافلہ گذرتا ہے۔ دریافت کیا گیا اس دنیا میں قیام کتنا ہے ؟آپ نے فرمایا جتنی دیر قافلہ سے چھوٹ جانے والا رہتا ہے ۔دریافت کیا گیا! دنیا وآخرت میں فاصلہ کتنا ہے ؟آپ نے فرمایا پلک جھپکنے کا۔( ۲ ) اور اس آیۂ کریمہ کی تلاوت فرمائی :
(کأنّهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الاساعة من نهار )( ۳ )
''تو ایسا محسوس کرینگے جیسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں ''
امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(الدنیاظلّ الغمام،وحلم المنام )( ۴ )
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۸ص۱۸۔
(۲)بحارالانوار ج۷۳ص۱۲۲۔
(۳)سورئہ احقاف آیت ۳۵۔
(۴)غررالحکم ج۱ص۱۰۲۔
''دنیا بادل کا سایہ اورسونے والے کا خواب ہے ''
امام محمد باقر نے فرمایا :
(انّ الدنیاعند العلماء مثل الظل )( ۱ )
''اہل علم کے نزدیک دنیا سایہ کے مانند ہے ''
امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(ألاوان الدنیادارلایسلم منها الافیها،ولاینجیٰ بشی ء کان لها،اُبتلی الناس فیها فتنة فماأخذوه منهالهاأخرجوامنه وحوسبواعلیه،وماأخذوهُ منها لغیرها، قدموا علیه وأقاموا فیه،فانهاعند ذوی العقول کفیٔ الظلّ بینا تراه سابغاً حتیٰ قلص،وزائداً حتیٰ نقص )( ۲ )
''یاد رکھو یہ دنیا ایسا گھر ہے جس سے سلامتی کا سامان اسی کے اندر سے کیا جاسکتا ہے اور کوئی ایسی شے وسیلہ نجات نہیں ہوسکتی ہے جو دنیا ہی کے لئے ہو۔لوگ اس دنیا کے ذریعہ آزمائے جاتے ہیں جو لوگ دنیا کا سامان دنیا ہی کے لئے حاصل کرتے ہیں وہ وہاں جاکر پالیتے ہیں اور اسی میں مقیم ہوجاتے ہیں ۔یہ دنیا در حقیقت صاحبان عقل کی نظر میں ایک سایہ جیسی ہے جو دیکھتے دیکھتے سمٹ جاتا ہے اور پھیلتے پھیلتے کم ہوجاتا ہے ''
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۳ص۱۲۶۔
(۲)نہج البلاغہ خطبہ ۶۳۔
دنیا ایک پل
دین اسلام مسلمان کو دنیا کے بارے میں ایک ایسے نظریہ کا حامل بنانا چاہتا ہے کہ اگر اسکے دل میں یہ عقیدہ و نظریہ راسخ ہوجائے توپھر دنیا کو ایک ایسے پل کے مانند سمجھے گا جس کے اوپر سے گذر کر اسے جانا ہے اور اس مسلمان کی نگاہ میں یہ دنیا دار القرار نہیں ہوگی ۔جب ایسا عقیدہ ہوگا تو خود بخود مسلمان دنیا پرفریفتہ نہ ہوگا اور اسکی عملی زندگی میں بھی اس کے نتائج نمایاں نظر آئیںگے۔
حضرت عیسیٰ کا ارشاد ہے :
(انما الدنیا قنطرة )( ۱ )
''دنیا ایک پل ہے ''
امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے :
(أیهاالناس انماالدنیادارمجازوالآخرة دار قرار،فخذوامن ممرّکم لمقرّکم،ولاتهتکواأستارکم عند من یعلم أسرارکم )( ۲ )
''اے لوگو !یہ دنیا گذر گاہ ہے اور آخرت دار قرارہے لہٰذا اپنے راستہ سے اپنے ٹھکانے کے لئے تو شہ اکٹھا کرلواور جو تمہارے اسرار کو جانتا ہے اس کے سامنے اپنے پردوں کو چاک نہ کرو ''
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :
(الدنیا دارممرّولادار مقرّ،والناس فیهارجلان:رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها )( ۳ )
''دنیا گذرگاہ ہے دارالقرار نہیں اس میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں کچھ وہ ہیں جنھوں نے دنیا کے ہاتھوں اپنا نفس بیچ دیا تو وہ دنیا کے غلام ہوگئے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کوخرید لیااور دنیا کو آزاد کردیا''
____________________
(۱)بحارالانوار ج۱۴ص۳۱۹۔
(۲)نہج البلاغہ خطبہ۲۰۳۔
(۳)شرح نہج البلاغہ ج۱۸ص۳۲۹۔
اسباب ونتائج کا رابطہ
اسلامی فکر کا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسانی مسائل سے متعلق اسباب و نتائج کو ایک دوسرے سے لاتعلق قرار نہیں دیتی بلکہ انھیں آپس میں ملاکر دیکھنے اور پھراس سے نتیجہ اخذ کرنے کی قائل ہے جب ہم انسانی اسباب و نتائج کے بارے میں غورکرتے ہیں تو ان مسائل میں اکثر دو طرفہ رابطہ نظر آتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے پراثر انداز ہوتے ہیں ۔انسانی مسائل میںایسے دوطرفہ رابطوں کی مثالیں بکثرت موجود ہیں مثلاًآپ زہد اور بصیرت کو ہی دیکھئے کہ زہد سے بصیرت اور بصیرت سے زہد میں اضافہ ہوتا ہے ۔
یہاں پر ہم ان دونوں سے متعلق چند روایات پیش کر رہے ہیں ۔
زہد وبصیرت
(أفمن شرح ﷲصدرہ للاسلام فھوعلیٰ نورٍمِن ربَّہِ)کی تفسیر کے ذیل میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا :
(ان النوراذاوقع فی القلب انفسح له وانشرح)،قالوا یارسول ﷲ:فهل لذٰلک علامةیعرف بها؟قال:(التجافی من دارالغرور،والانابة الیٰ دارالخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت )
''قلب پر جب نور کی تابش ہوتی ہے تو قلب کشادہ ہوجاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہوجاتی ہے عرض کیا گیا یا رسول ﷲ اسکی پہچان کیا ہے ؟
آپ نے فرمایا :
''دار الغرور(دنیا)سے دوری ،دارالخلود(آخرت)کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اسکے لئے آمادہ ہوجانا ہے ''( ۱ )
امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(أحقّ الناس بالزهادة،من عرف نقص الدنیا )( ۲ )
''جو دنیا کے نقائص سے آگاہ ہے اسے زیادہ زاہد ہونا چاہئے''
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :
(من صوّرالموت بین عینیه،هان أمرالدنیا علیه )( ۳ )
''جس کی دونوں آنکھوں کے سامنے موت کھڑی رہتی ہے اس کے لئے دنیا کے امور آسان ہوجاتے ہیں ''
نیز آپ نے فرمایا :(زهدالمرء فیمایفنیٰ،علی قدر یقینه فیما یبقیٰ )( ۴ )
''فانی اشیائ(دنیا)کے بارے میں انسان اتناہی زاہد ہوتا ہے جتنا اسے باقی اشیاء (آخرت )کے بارے میں یقین ہوتا ہے ''
زہدو بصیرت کا رابطہ
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے حضرت ابوذر (رح)سے فرمایا :
(یاأباذر:مازهد عبد فی الدنیا،الاأنبت ﷲ الحکمة فی قلبه،وأنطق بهالسانه ،ویبصّره عیوب الدنیا وداء ها ودواء ها،وأخرجه منهاسالماًالی دارالسلام )( ۵ )
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۳ص۱۲۲۔
(۲)غررالحکم۔
(۳)غررالحکم ۔
(۴)بحارالانوار ج۷۰ص۳۱۹۔
(۵)بحارالانوار ج۷۷ص۸۔
''اے ابوذر جو شخص بھی زہداختیار کرتاہے ﷲ اس کے قلب میں حکمت کا پودا اگا دیتا ہے اور اسے اسکی زبان پر جاری کر دیتا ہے اسے دنیا کے عیوب ،اوردرد کے ساتھ انکاعلاج بھی دکھا دیتا ہے اور اسے دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام لے جاتا ہے ''
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے مروی ہے :
(من یرغب فی الدنیا فطال فیهاأمله،أعمیٰ ﷲ قلبه علیٰ قدررغبته فیها، ومن زهد فیها فقصُرأمله أعطاه ﷲعلماًبغیرتعلّم،وهدیً بغیرهدایة،وأذهب عنه العماء وجعله بصیراً )( ۱ )
جو دنیا سے رغبت رکھتا ہے اسکی آرزوئیں طویل ہوجاتی ہیں اوروہ جتنا راغب ہوتا ہے اسی مقدار میں خدا اسکے قلب کوا ندھا کر دیتا ہے اور جو زہد اختیار کر تا ہے اسکی آرزوئیں قلیل ہوتی ہیں ﷲ اسے تعلیم کے بغیرعلم اور رہنما ئی کے بغیرہدایت عطا کرتا ہے اور اس کے اند ھے پن کو ختم کر کے اسے بصیر بنا دیتا ہے ''
ایک دن پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم لوگوں کے درمیان آئے اور فرمایا:
(هل منکم من یریدأن یؤتیه ﷲ علماًبغیرتعلّم،وهدیاًبغیرهدایة؟هل منکم من یریدأن یذهب عنه العمیٰ و یجعله بصیراً؟ألاانه من زهد فی الدنیا،وقصرأمله فیها،أعطاه ﷲعلماًبغیرتعلّم،وهدیاً بغیرهدایة )( ۲ )
''کیا تم میں سے کوئی اس بات کا خواہاں ہے کہ ﷲ اسے تعلیم کے بغیر علم اور رہنمائی کے بغیرہدایت دیدے۔ تم میں سے کوئی اس بات کا خواہاں ہے کہ ﷲ اس کے اندھے پن کو دور کر کے اسے بصیر بنادے ؟آگاہ ہو جائو جو شخص بھی دنیا میں زہدا ختیار کر ے گااور اپنی آرزوئیں قلیل رکھے گا
____________________
(۱)بحارالانوارج۷۷ص۲۶۳۔
(۲)درالمنثورج۱ص۶۷۔
ﷲاسے تعلیم کے بغیرعلم اور رہنمائی کے بغیرہدایت عطاکر ے گا ''
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا :
(یاأباذراذارأیت أخاک قدزهد فی الدنیا فاستمع منه،فانه یُلقّیٰ الحکمة )( ۱ )
''اے ابوذراگر تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ وہ دنیا میں زاہد ہے تو اسکی باتوںکو(دھیان سے ) سنو کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے ''
ان روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ زہد وبصیرت میں دو طرفہ رابطہ ہے ،یعنی زہد کا نتیجہ بصیرت اور بصیرت کا نتیجہ زہد ہے ۔اسی طرح زہد اور قلتِ آرزو کے مابین بھی دو طرفہ رابطہ ہے زہد سے آرزووں میں کمی اور اس کمی سے زہد پیدا ہوتا ہے زہد اورقلت آرزو کے درمیان رابطہ کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے :(الزهدیخلق الابدان،ویحدّدالآمال،ویقرّب المنیة،ویباعدالاُمنیة،من ظفر به نصب،ومن فاته تعب )( ۲ )
'' زہد،بدن کو مناسب اور معتدل ،آرزووں کو محدود،موت کو نگاہوں سے نزدیک اور تمنائوں کو انسان سے دور کردیتا ہے جو اسکو پانے میں کامیاب ہوگیا وہ خوش نصیب ہے اور جو اسے کھو بیٹھا وہ در دسر میں مبتلاہوگیا''
آرزووں کی کمی اورزہد کے رابطہ کے بارے میں امام محمد باقر کا ارشاد ہے:
(استجلب حلاوة الزهادة بقصرالامل )( ۳ )
''آرزو کی قلت سے زہد کی حلاوت حاصل کرو''
ان متضاد صفات کے درمیان دو طرفہ رابطہ کا بیان اسلامی فکر کے امتیازات میں سے ہے
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۷ص۸۰ ۔
(۲)بحارالانوارج ۷۰ص۳۱۷۔
(۳)بحارالانوار ج۷۸ص۱۶۴۔
زہد وبصیرت یا زہد وقلتِ آرزو کے درمیان دو طرفہ رابطہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر ایک دوسرے کے ذریعہ اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس سے انسان ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کہ بصیرت سے زہد کی کیفیت پیدا ہو تی ہے اور جب انسان زاہد ہو جاتا ہے تو بصیرت کے اعلیٰ مراتب حاصل ہو جاتے ہیں نیزبصیرت کے ان اعلیٰ مراتب سے زہد میں اضافہ ہوتا ہے اور اس زہد سے پھر بصیرت کے مزید اعلیٰ مراتب وجود پاتے ہیں۔اسطرح انسان ان دونوں صفات وکمالات کے ذریعہ بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔
مذموم دنیا اور ممدوح دنیا
۱۔مذموم دنیا
اس سے قبل ہم نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کے دو چہرے ہیں:
( ۱ ) ظاہری
( ۲ ) باطنی
دنیا کا ظاہر ی چہرہ فریب کا سر چشمہ ہے ۔یہ چہرہ انسانی نفس میں حب دنیا کا جذبہ پیدا کرتا ہے جبکہ باطنی چہرہ ذریعۂ عبرت ہے یہ انسان کے نفس میں زہدکا باعث ہوتا ہے روایات کے مطابق دنیا کا ظاہری چہرہ مذموم ہے اور باطنی چہرہ ممدوح ہے ۔
ایسا نہیں ہے کہ واقعاً دنیا کے دو چہرے ہیں یہ فرق در حقیقت دنیا کو دیکھنے کے انداز سے پیدا ہوتا ہے ورنہ دنیا اور اسکی حقیقت ایک ہی ہے ۔فریب خور د ہ نگاہ سے اگر دنیا کو دیکھا جائے تو یہ دنیا مذموم ہوجاتی ہے اور اگر دیدئہ عبرت سے دنیا پر نگاہ کی جائے تو یہی دنیاممدوح قرار پاتی ہے ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لذات وخواہشات سے لبریز دنیا کا ظاہری چہرہ ہی مذموم ہے ۔
یہاں پر دنیا کے مذموم رخ کے بارے میں چند روایات پیش کی جارہی ہیں ۔
امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا:
(الدنیا سوق الخسران )( ۱ )
''دنیا گھاٹے کا بازار ہے ''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(الدنیا مصرع العقول )( ۲ )
''دنیا عقلوں کا میدان جنگ ہے ''
آپ کا ہی ارشاد ہے :
(الدنیا ضحکة مستعبر )( ۳ )
''دنیا چشم گریاں رکھنے والے کے لئے ایک ہنسی ہے ''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(الدنیا مُطَلَّقةُ الاکیاس )( ۴ )
''دنیاذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(الدنیا معدن الشرور،ومحل الغرور )( ۵ )
''دنیا شروفسا دکا معدن اور دھوکے کی جگہ ہے''
____________________
(۱)غررا لحکم ج ۱ص۲۶۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۴۵۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۲۶۔
(۴)غررالحکم ج۱ص۲۸۔
(۵)غررالحکم ج۱ص۷۳۔
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(الدنیالا تصفولشارب،ولا تفی لصاحب )( ۱ )
''دنیا کسی پینے والے کے لئے صاف وشفاف اور کسی کے لئے باوفا ساتھی نہیں ہے ''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(الدنیا مزرعة الشر )( ۲ )
''دنیا شروفسا دکی کا شت کی جگہ ہے''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(الدنیا مُنیة الاشقیائ )( ۳ )
''دنیا اشقیا کی آرزوہے''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(الد نیا تُسْلِمْ )( ۴ )
''دنیا دوسرے کے حوالے کر دیتی ہے''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(الدنیا تُذِلّْ )( ۵ )
''دنیا ذلیل کرنے والی ہے''
____________________
(۱)غررالحکم ج۱ص ۸۵۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۲۶۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۳۷۔
(۴)غررالحکم ج۱ص۱۱۔
(۵)غررالحکم ج۱ص۱۱۔
دنیا سے بچائو
امیر المو منین حضرت علی ہمیں دنیا سے اس انداز سے ڈراتے ہیں :
(أُحذّرکم الدنیافانّهالیست بدارغبطة،قدتزیّنت بغرورها،وغرّت بزینتهالمن ان ینظرالیها )( ۱ )
''میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں کیونکہ یہ فخرومباہات کاگھر نہیں ہے ۔یہ اپنے فریب سے مزین ہے اور جو شخص اسکی طرف دیکھتا ہے اسے اپنی زینت سے دھوکے میں مبتلاکردیتی ہے ''
ایک اور مقام پر آپ کا ارشاد گرامی ہے :
(أُحذّرکم الدنیافانها حُلوة خضرة،حُفّت بالشهوات )( ۲ )
''میں تمہیں اس دنیا سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں کہ یہ دنیا سرسبز وشیریں اورشہوتوں سے گھری ہوئی ہے ''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(احذروا هذه الدنیا،الخدّاعة الغدّارة،التی قد تزیّنت بحلیّها،وفتنت بغرورها،فأصبحت کالعروسة المجلوة،والعیون الیها ناظرة )( ۳ )
''اس دھو کے باز مکار دنیا سے بچو یہ دنیا زیورات سے آراستہ اور فتنہ ساما نیوں کی وجہ سے سجی سجائی دلہن کی مانندہے کہ آنکھیں اسی کی طرف لگی رہتی ہیں ''
ب :ممدوح دنیا
دنیا کا دوسرا رخ اوراس کے بارے میں جو دوسرانظر یہ ہے وہ قابل مدح وستائش ہے البتہ
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۸ ص۲۱۔
(۲)بحارالانوار ج۷۳ص۹۶۔
(۳)بحارالانوارج۷۳ص۱۰۸۔
یہ قابل ستائش رخ اس دنیا کے باطن سے نکلتا ہے جو قابل زوال ہے جبکہ مذموم رخ ظاہری دنیا سے متعلق تھا ۔
بہر حال یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا کے دورخ ہیں ایک ممدوح اور دوسرا مذموم ۔ممدوح رخ کے اعتبار سے دنیا نقصان دہ نہیں ہے بلکہ نفع بخش ہے اورمضر ہونے کے بجائے مفید ہے اسی رخ سے دنیا آخرت تک پہو نچانے والی ،مومن کی سواری ،دارصدق اوراولیاء کی تجارت گاہ ہے۔لہٰذادنیا کے اس رخ کی مذمت صحیح نہیں ہے روایات کے آئینہ میں دنیا کے اس رخ کوبھی ملا حظہ فرما ئیں ۔
۱۔دنیا آخرت تک پہو نچانے والی
امام زین العابدین نے فرمایا :
(الدنیا دنیاءان،دنیابلاغ،ودنیاملعونة )( ۱ )
''دنیا کی دو قسمیں ہیں ؟دنیا ئے بلاغ اور دنیا ئے ملعونہ ''
دنیائے بلاغ سے مراد یہ ہے کہ دنیا انسان کو آخرت تک پہو نچاتی ہے اور خدا تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ۔بلاغ کے یہی معنی ہیں اوریہ دنیا کی پہلی قسم ہے ۔
دوسری دنیا جو ملعون ہے وہ دنیا وہ ہے جوانسان کو ﷲسے دورکرتی ہے اس لئے کہ لعن بھگانے اور دور کرنے کو کہتے ہیں اب ہرانسان کی دنیااِنھیں دومیں سے کوئی ایک ضرورہے یاوہ دنیا جو خدا تک پہونچاتی ہے یاوہ دنیا جو خدا سے دور کرتی ہے ۔
اسی سے ایک حقیقت اور واضح ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا میں کسی ایک مقام پر ٹھہر انہیں رہتا ہے بلکہ یا تووہ قرب خداکی منزلیں طے کرتا رہتا ہے یا پھر اس سے دور ہوتا جاتا ہے ۔
امیر المو منین حضرت علی کا ارشاد ہے :
____________________
(۱)بحارالانوارج۷۳ص۲۰۔
(لاتسألوافیها فوق الکفاف،ولاتطلبوامنها أکثرمن البلاغ )( ۱ )
''اس دنیا میں ضرورت سے زیادہ کا سوال مت کرو اور نہ ہی کفایت بھر سے زیادہ کا مطالبہ کرو ''
اس طرح اس دنیا کا مقصد (بلاغ)ہے اور انسان دنیا میں جو بھی مال ومتاع حاصل کرتا ہے وہ صرف اس مقصد تک پہونچنے کیلئے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے اس طرح انسان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں صرف اتنا ہی طلب کرے جس سے اپنے مقصود تک پہنچ سکے لہٰذا اس مقدار سے زیادہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وسیلہ کو مقصد بنانا چا ہئے اور یہ یادر کھنا چاہئے کہ دنیا وسیلہ ہے آخری مقصد نہیں ہے بلکہ آخری مقصد آخرت اور خدا تک رسائی ہے ۔
امیرا لمو منین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(الدنیاخلقت لغیرها،ولم تخلق لنفسها )( ۲ )
''دنیا اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے غیر (آخرت تک رسائی )کیلئے خلق کی گئی ہے''
وسیلہ کو مقصد قرار دے دیاجائے یہ بھی غلط ہے اسی طرح واسطہ کو وسیلہ اور مقصد(دونوں ) قرار دینا بھی غلط ہے اسی لئے امیرالمو منین نے فر مایا ہے کہ دنیاکو صرف اس مقدارمیںطلب کرو جس سے آخرت تک پہونچ سکو ۔
لیکن خود حصول دنیا کے سلسلہ میں آپ نے فرمایا کہ صرف بقدر ضرورت سوال کرو ۔امام کے اس مختصر سے جملے میں حصول رزق کے لئے سعی و کو شش کے سلسلہ میں اسلام کا مکمل نظریہ موجود ہے ۔چونکہ مال و متاع ِ دنیا آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے لہٰذا کسب معاش اور تحصیل رزق ضروری ہے لیکن اس تلاش و جستجو میں ''بقدر ضرورت ''کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ''بقدر ''ضرورت سے مراد وہ
____________________
(۱)بحارالانوارج ۷۳ص۸۱۔
(۲)نہج البلاغہ حکمت ۴۵۵۔
مقدار ہے کہ جس کے ذریعہ دنیاوی زندگی کی ضرورتیں پوری ہو تی رہیں اور آخرت تک رسائی ہو سکے
انسا نی ضرورت واقعی اور ضروری بھی ہو تی ہے اور غیر واقعی یا وہمی بھی ۔یعنی اسے زندہ رہنے اور آخرت تک رسائی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ حقیقی ضرورتیں ہیں ۔اوران کے علاوہ کچھ غیر ضروری چیزیں بھی احتیاج وضرورت کی شکل میں انسان کے سامنے آتی ہیںجو در حقیقت حرص و طمع ہے اوران کا سلسلہ کبھی ختم ہو نے والا نہیں ہے اگر انسان ایک مرتبہ ان کی گرفت میں آگیا تو پھر ان کی کو ئی انتہا ء نہیں ہوتی ۔ان کی راہ میں جد وجہد کرتے ہوئے انسان ہلاک ہو جاتا ہے مگر اس جد و جہد سے اذیت و طمع میں اضافہ ہی ہوتا ہے ۔
حضرت امام جعفر صادق نے اپنے جد بزرگوار حضرت علی کا یہ قول نقل فرمایاہے:
یابن آدم:ان کنت ترید من الدنیامایکفیک فان أیسرما فیهایکفیک،و ان کنت انما ترید مالیکفیک فان کل ما فیهایکفیک ( ۱ )
''اے فرزند آدم اگر تو دنیا سے بقدر ضرورت کا خواہاں ہے تو تھوڑا بہت ،جو کچھ تیرے پاس ہے وہی کا فی ہے اور اگر تو اتنی مقدار میں دنیا کا خواہاں ہے جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی نا کافی ہے ''
دنیا کے بارے میں یہ دقیق نظریہ متعدد اسلامی روایات اور احا دیث میں وارد ہوا ہے ۔
امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے:
ألا وان الدنیادار لا یُسلَم منها الا فیها،ولاینجیٰ بشی ء کان لها،ابتلی الناس بها فتنة،فما أخذوه منها لهااُخرجوا منه وحوسبوا علیه،
____________________
(۱)اصول کافی ج۲ص۱۳۸۔
وما أخذوه منهالغیرها قدمواعلیه وأقاموا فیه )( ۱ )
''آگاہ ہو جا ئو کہ یہ دنیا ایسا گھرہے جس سے سلامتی کا سامان اسی کے اندر سے کیا جاسکتا ہے اور کو ئی ایسی شئے وسیلۂ نجات نہیں ہو سکتی ہے جو دنیا ہی کے لئے ہو ۔لوگ اس دنیا کے ذریعہ آزمائے جاتے ہیں ۔جو لوگ دنیا کا سامان ،دنیا ہی کیلئے حاصل کرتے ہیں وہ اسے چھوڑکر چلے جاتے ہیں اور پھر حساب بھی دینا ہوتا ہے اور جولوگ یہاں سے وہاںکیلئے حاصل کرتے ہیں وہ وہاں جاکر پالیتے ہیں اور اسی میں مقیم ہوجاتے ہے یہ دنیا در حقیقت صاحبان عقل کی نظر میں ایک سایہ جیسی ہے جو دیکھتے دیکھتے سمٹ جاتا ہے اور پھیلتے پھیلتے کم ہوجاتا ہے ''
ان کلمات میں اختصار کے باوجود بے شمار معانی ومطالب پائے جاتے ہیں (دارلایسلم منها اِلا فیها )اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان سے فرار اور خدا تک رسائی کے لئے دنیا مومن کی سواری ہے اس کے بغیر اسکی بارگاہ میں رسائی ممکن نہیں ہے عجیب وغریب بات ہے کہ دنیا اور لوگوں سے کنا رہ کشی کرنے والا قرب خدا کی منزل مقصود تک نہیں پہونچ سکتا بلکہ ﷲ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اسی دنیا میں رہ کر اسی دنیا کے سہارے اپنی منزل مقصود حاصل کرے۔لہٰذا ان کلمات سے پہلی حقیقت تو یہ آشکار ہوئی ہے کہ دنیا واسطہ اور وسیلہ ہے اس کو نظر انداز کرکے مقصدحاصل نہیںکیاجاسکتا۔
لیکن یہ بھی خیال رہے کہ دنیا مقصد نہ بننے پائے۔ اگر انسان دنیا کو وسیلہ کے بجائے ہدف اور مقصد بنالے گا تو ہرگز نجات حاصل نہیں کرسکتا (ولاینجی لشی کان لھا) اس طرح اگر انسان نے دنیا کواس کی اصل حیثیت ''واسطہ ووسیلہ''سے الگ کردیا اور اسی کو ہدف بنالیا تو پھر دنیاشیطان سے نجات اور خدا تک پہنچانے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے یہ دوسری حقیقت ہے جوان
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۶۲ ۔
کلمات میں موجود ہے ۔
اور پھراگر انسان دنیا کو خدا ،قرب خدا اور رضائے الٰہی حاصل کرنے کے بجائے خود دنیا کی خاطر اپناتا ہے تو یہی دنیا اسکو خدا سے دور کردیتی ہے ۔اس دنیا کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے یعنی اگر انسان اسے وسیلہ اور خدا تک رسائی کا ذریعہ قرار دیتا ہے تو یہ دنیا اس کے لئے ذخیرہ بن جاتی ہے اور اس کے لئے باقی رہتی ہے نیز دنیا وآخرت میں اس کے کام آتی ہے لیکن اگر وسیلہ کے بجائے اسے مقصد بنالے تو یہ ﷲ سے غافل کرتی ہے ۔خدا سے دور کردیتی ہے موت کے بعدانسان سے جدا ہوجاتی ہے اور بارگاہ الٰہی میں اسکا سخت ترین حساب لیا جاتاہے ۔
یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ فرق کمیت اور مقدار کا نہیں ہے بلکہ کیفیت کا ہے اور عین ممکن ہے کہ انسان وسیع و عریض دنیا کا مالک ہو لیکن اسکا استعمال راہ خدا میں کرتا ہو اس کے ذریعہ قرب خدا کی منزلیں طے کرتا ہو ایسی صورت میں یہ دنیا اس کے لئے ''عمل صالح''شمار ہوگی اس کے برخلاف ہوسکتا ہے کہ مختصر سی دنیا اور اسباب دنیاہی انسان کے پاس ہوں لیکن اسکا مقصد خود وہی دنیا ہو تو یہ دنیا اس سے چھین لی جائے گی اسکا محاسبہ کیا جائے گا ۔یہ ہے ان کلمات کا تیسرا نتیجہ۔
اگر خود یہی دنیا انسان کے مد نظر ہوتو اسکی حیثیت ''عاجل''''نقد''کی سی ہے جو کہ اسی دنیا تک محدود ہے اور اس کا سلسلہ آخرت سے متصل نہ ہوگابلکہ زائل ہو کر جلد ختم ہوجائے گی لیکن اگر دنیا کو دوسرے (آخرت )کے لئے اختیار کیا جائے تو اسکی حیثیت''آجل''''ادھار''کی سی ہوگی کہ جب انسان حضور پروردگار میں پہونچے گا تو وہاںدنیا کو حاضر وموجود پائے گا ۔ایسی دنیا زائل ہونے والی نہیں بلکہ باقی رہے گی''وماعندﷲ خیر وأبقی''امیر المومنین کے اس فقرہ''وماأخذ وہ منھا لغیرھا قدموا علیہ وأقاموا فیہ'' سے یہ چوتھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے ۔
زیارت امام حسین سے متعلق دعا میں نقل ہوا ہے:
(ولاتشغلنی بالاکثارعلیّ من الدنیا،تلهینی عجائب بهجتها،وتفتننی زهرات زینتها،ولا بقلالٍ یضرّ بعملی،ویملأ صدری همّه )( ۱ )
''کثرت دنیا سے میرے قلب کو مشغول نہ کردینا کہ اسکے عجائبات مجھے تیری یاد سے غافل کردیں یا اسکی زینتیں مجھے اپنے فریب میں لے لیں اور نہ ہی دنیا میں میرا حصہ اتنا کم قرار دینا کہ میرے اعمال متاثر ہوجائیں اور میرا دل اسی کے ہم وغم میں مبتلا رہے ''
دنیا اوراس سے انسان کے تعلق، بقاء و زوال ،اسکے مفید ومضر ہونے کے بارے میں اس سے قبل جو کچھ بیان کیا گیا وہ کیفیت کے اعتبار سے تھا کمیت ومقدار سے اسکا تعلق نہیں تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ کمیت و مقدار بھی اس میں دخیل ہے کثرت دنیا اور اسکی آسا ئشیںانسان کو اپنے میں مشغول کرکے یاد خدا سے غافل بنادیتی ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑاحصہ ہونے کے باوجود انسان دنیا میں گم نہ ہو یا یہ زیادتی اسے خدا سے دور نہ کردے اسکے لئے سخت جد وجہد درکار ہوتی ہے اور اسی طرح اگر دنیا وی حصہ کم ہو،دنیا روگردانی کر رہی ہو تو یہ بھی انسان کی آزمائش کا ایک انداز ہوتا ہے کہ انسان کا ہم وغم اور اس کی فکریں دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں اور وہ خدا کو بھول جاتا ہے اسی لئے اس دعا میں حد متوسط کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نہ تو اتنی کثرت ہو جس سے انسان یاد خدا سے غافل ہوجائے اور نہ اتنی قلت ہوکہ انسان اسی کی تلاش میں سرگرداں رہے اور خدا کو بھول بیٹھے۔
۲۔دنیا مومن کی سواری
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے مروی ہے :
(لاتسبّوا الدنیا فنعمت مطیة المؤمن،فعلیها یبلغ الخیر وبها ینجو من الشر )( ۲ )
____________________
(۱)بحارالانوار ج۱۰۱ ص۲۰۸۔
(۲)بحارالانوار ج۷۷ص۱۷۸۔
''دنیا کو برا مت کہو یہ مومن کی بہترین سواری ہے اسی پر سوار ہوکر خیر تک پہنچاجاتا ہے اور اسی کے ذریعہ شرسے نجات حاصل ہوتی ہے ''
اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا سواری کی حیثیت رکھتی ہے جس پر سوار ہوکر انسان خدا تک پہونچتا اور جہنم سے فرار اختیار کرتا ہے ۔
یہ دنیاکاقابل ستائش رخ ہے اگر دنیانہ ہوتی توانسان رضائے الٰہی کے کام کیسے بجالاتا ، کیسے خدا تک پہونچتا ؟اولیاء خدا اگر قرب خداوند ی کے بلند مقامات تک پہونچے ہیں تو وہ بھی اسی دنیا کے سہارے سے پہونچے ہیں ۔
۳۔دنیا صداقت واعتبار کا گھر ہے ۔
۴۔دنیا دار عافیت۔
۵۔دنیا استغنا اور زاد راہ حاصل کرنے کی جگہ ہے ۔
۶۔دنیا موعظہ کا مقام ہے ۔
۷۔دنیا محبان خدا کی مسجدہے ۔
۸۔دنیا اولیاء الٰہی کے لئے محل تجارت ہے ۔
امیر المومنین حضرت علی نے جب ایک شخص کو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا :
(أیهاالذام للدنیاالمغترّبغرورهاالمنخدع بأباطیلها!أتغتر بالدنیاثم تذمّها،أنت المتجرّم علیهاأم هی المتجرّمةعلیک؟متیٰ استهوتک؟أم متیٰ غرّتک؟ )( ۱ )
''اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اسکے فریب میں مبتلا ہوکر اسکے مہملات میں دھوکا کھا
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت ۱۲۶۔
جانے والے !تو اسی سے دھوکا بھی کھاتا ہے اور اسکی مذمت بھی کرتا ہے ؟یہ بتائو کہ تجھے اس پر الزام لگانے کا حق ہے یا اسے تجھ پر الزام لگانے کا حق ہے ؟آخر اس نے کیا تجھ سے تیری عقل کو چھین لیا تھا اور کب تجھ کو دھوکہ دیا تھا؟کیا تیرے آبا ء و اجداد کی کہنگی کی بناء پر گرنے سے دھوکا دیا ہے یا تمہاری مائوں کی زیر خاک خواب گاہ سے دھوکا دیا ہے ؟کتنے بیمار ہیںجن کی تم نے تیمار داری کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے انکا علاج کیا ہے اور چاہاکہ وہ شفا یاب ہوجائیں اور اطباء سے رجوع بھی کیا ہے ۔اس صبح کے ہنگام جب نہ کوئی دوا کام آرہی تھی اور نہ رونا دھونافائدہ پہنچارہا تھا۔نہ تمہاری ہمدردی کسی کوکوئی فائدہ پہنچاسکی اور نہ تمہارا مقصد حاصل ہوسکا اور نہ تم موت کو دفع کرسکے۔اس صورت حال میں دنیا نے تم کو اپنی حقیقت دکھلادی تھی اور تمھیں تمہاری ہلاکت سے آگاہ کردیا تھا (لیکن تمھیں ہوش نہ آیا)یاد رکھو کہ دنیا باورکرنے والے کے لئے سچائی کا گھر اور سمجھ دار کے لئے امن وعافیت کی منزل اور نصیحت حاصل کرنے والے کیلئے نصیحت کا مقام ہے ۔یہ دوستان خدا کے لئے سجود کی منزل اور ملائکہ ٔ آسمان کا مصلی ہے یہیں وحی الٰہی کانزول ہوتا ہے اور یہیں اولیاء خدا آخرت کا سودا کرتے ہیںجس کے ذریعہ رحمت کو حاصل کرلیتے ہیں اور جنت کو فائدہ میں لے لیتے ہیں کسے حق ہے کہ اسکی مذمت کرے جبکہ اس نے اپنی جدائی کا اعلان کردیا ہے اور اپنے فراق کی آواز لگادی ہے اور اپنے رہنے والوں کی سنانی سنادی ہے اپنی بلاسے ان کے ابتلا کا نقشہ پیش کیا ہے اور اپنے سرور سے آخرت کے سرور کی دعوت دی ہے ۔اسکی شام عافیت میں ہوتی ہے تو صبح مصیبت میں ہوتی ہے تاکہ انسان میںرغبت بھی پیدا ہو اور خوف بھی ۔اسے آگاہ بھی کردے اور ہوشیار بھی بنادے ۔کچھ لوگ ندامت کی صبح اسکی مذمت کرتے ہیں اور کچھ لوگ قیامت کے روز اسکی تعریف کریں گے۔جنہیں دنیا نے نصیحت کی تو انھوںنے اسے قبول کرلیا اس نے حقائق بیان کئے تو اسکی تصدیق کردی اور موعظہ کیا تو اسکے موعظہ سے اثر لیا''
۹۔دنیا بازار ہے
حضرت امام علی نقی نے فرمایا ہے :
(الدنیا سوق ربح فیها قوم وخسرآخرون )( ۱ )
''دنیا ایک بازار ہے جہاںایک قوم فائدہ میں ہے اوردوسری قوم خسارہ میں ''
۱۰۔دنیا آخرت کے لئے مددگار ہے ۔
امام محمد باقر کا ارشاد ہے :
(نعم العون الد نیا علیٰ الآخرة )( ۲ )
''دنیا آخرت کے لئے بہترین مددگار ہے ''
۱۱۔دنیا ذخیرہ (خزانہ )ہے ۔
امیر المومنین کا ارشاد ہے :
(الدنیا ذخر والعلم دلیل )( ۳ )
''دنیا خزانہ ہے اور علم رہنما''
۱۲۔دنیا دارالمتقین ہے ۔
قول پروردگار ''ولنعم دارالمتقین''کی تفسیر کے ذیل میںامام محمد باقر نے فرمایا کہ:
''اس سے مراد ''دنیا ''ہے ۔
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۸ص۳۶۶۔
(۲)بحارالانوار ج۷۳ص۱۲۷۔
(۳)غررالحکم۔
۱۳۔دنیاکا ماحصل آخرت ۔
حضرت علی نے فرمایا ہے :
(بالدنیا تحرز الآخرة)( ۱ )
'' دنیاکے ذریعہ آخرت حاصل کی جاتی ہے''
اس طرح اسلام کی نگاہ میں دنیا قابل مدح وستائش، اولیائے الٰہی کی محل تجارت ،محبان خدا کی مسجد ،آخرت تک رسائی کا ذریعہ اور مومنین کے لئے زاد آخرت حاصل کرنے کا مقام ہے لیکن یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ جب دنیا سے عبرت و نصیحت حاصل کی جائے لیکن اگر دنیا کومنظورنظر بنا لیا جائے تو پھر یہی دنیا انسان کو اندھا بنا دیتی ہے جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے :
منقول ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا :
(أیهاالذام الدنیا أنت المتجرّم علیها أم هی المتجرّمه علیک؟قال قائل: بل أناالمتجرّم علیهایاامیرالمؤمنین فقال:''فلم ذممتها؟ألیست دارصدق لمن صدقها؟ )( ۲ )
''اے دنیا کی مذمت کرنے والے!تو نے اسکے اوپر تہمت لگائی ہے یا اس نے تیرے اوپر تہمت لگائی ہے ؟''تو اس شخص نے کہا :اے امیر المومنین میں نے اس پر تہمت لگائی ہے! تو آپ نے فرمایا :
''تو پھرتم دنیا کی کیوں مذمت کرتے ہو؟کیا یہ دنیا تصدیق کرنے والوں کیلئے دار صدق نہیں ہے ''
____________________
(۱) بحارالانوارج ۶۷ص۶۷۔
(۲)بحارالانوار ج۷۸ ص۷ ۱۔
ج۔اسکے دل کو اسکا دلدادہ بنا دونگاجرم اور سزا کے درمیان تبادلہ
''اور اسکے دل کو دنیا سے وابستہ کردوں گا'' یہ ان لوگوں کی تیسری سزا ہے جو خدا سے منھ موڑ کر اپنی خواہشات کی جانب دوڑتے ہیں یہاں سزا اور جرم ایک ہی طرح کے ہیں ۔اور جب جرم وسزا کی نوعیت ایک ہوتی ہے تو وہ کوئی قانونی سزا نہیں بلکہ''تکوینی''سزا ہوتی ہے اور تکوینی سزا زیادہ منصفانہ ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا امکان بھی نہیں ہوتا ۔ جرم یہ ہے کہ انسان خدا کو چھوڑکر خواہشات سے دل لگارہاہے اور سزا بھی ایسی ہی ہے یعنی خدا بندہ کو دنیا میں ہی مشغول کردیتا ہے ''واشغلت قلبہ بھا ''
اس طرح جرم و سزا میںدو طرفہ رابطہ ہے اور دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں خدا کو چھوڑکر''خواہشات میں الجھنے''کی سزا ''دنیا میں الجھنا ''ہے اس سزا سے جرم میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جرم میں اضافہ ،مزید سزا کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ سلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے اس طرح نہ صرف یہ کہ سزا وہی ملتی ہے جو جرم کیا ہے بلکہ خود سزا جرم کو بڑھاتی ہے اور اسے شدید کردیتی ہے نتیجتاً انسان کچھ اورشدید سزا کا مستحق ہوجاتا ہے ۔
انسان جب پہلی مرتبہ جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس وقت اسکے پاس گناہوں سے اجتناب اور سقو ط وانحراف سے بچانے والی خدا داد قوت مدافعت کا مکمل اختیارہوتا ہے لیکن جب گناہوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے اور انسان اپنے نفس کو نہیں روکتا تو خدا بھی سزا کے طورپراسے اسی جرم کے حوالہ کردیتا ہے اوراس سے گناہوں سے اجتناب کرنے اور نفس پر تسلط قائم رکھنے کی فطری اور خدا داد صلاحیت کوسلب کرلیتا ہے ۔
اور سزا کا درجہ جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان اتنا ہی جرم کے دلدل میں پھنستا رہتا ہے ،اپنے نفس پر اسکی گرفت کمزور ہوتی رہتی ہے اور گناہوں سے پرہیز کی صلاحیت دم توڑتی جاتی ہے یہاں تک کہ خداوند عالم اس سے گناہوں سے اجتناب کی فطری صلاحیت اور نفس پر تسلط و اختیار کو مکمل طریقہ سے سلب کرلیتا ہے ۔
اس مقام پر یہ تصور ذہن میں نہیں آنا چاہئیے کہ جب مجرم کے پاس نفس پر تسلط اور گناہوں سے اجتناب کی صلاحیت بالکل ختم ہوگئی اور گویا اسکا اختیار ہی ختم ہوگیا تو اب سزا کیسی ؟یہ خیال ناروا ہے اس لئے کہ ابتداء میں مجرم نے جب جرم کا ارتکاب کیا تھا اس وقت تواسکے پاس یہ صلاحیت اور نفس کے اوپر تسلط بھرپور طریقہ سے موجودتھا اور وہ مکمل اختیار کا مالک تھا جو شخص اپنے ہاتھوں دولت اختیار ضائع کردے اسے بے اختیار نہیں کہاجاتا جیسے بلندی سے کود نے والا گرنے کے بعد یقینابے اختیار ہوجاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص خود جان بوجھ کربلندی سے چھلانگ لگائے تو اسکے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بے اختیار ہے اوراسکے پاس بچنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔
دنیاداری کے دورخ یہ بھی!
جب انسان دنیا داری میں مشغول ہوجاتا ہے تو اس کا پہلا اثر اور ایک رخ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سارا ہم وغم اسکی دنیا ہی ہوتی ہے اور یہ کیفیت ایک خطرناک بیماری کی شکل اختیار کرکے قلب انسانی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے ۔
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے ایک دعا میں منقول ہے :
(اللّهم أقسم لنامن خشیتک مایحول بیننا وبین معاصیک،ولاتجعل الدنیا أکبرهمنا،ولامبلغ علمنا )( ۱ )
''پروردگارا! ہمیںوہ خوف وخشیت عطا فرما جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل
____________________
(۱)بحارالانوارج۹۵ص۳۶۱۔
ہوجائے اور ہمارے لئے دنیا کو سب سے بڑا ہم وغم اور ہمارے علم کی انتہا قرار مت دینا ''
اگرانسان دنیاوی معاملات کو اہمیت دے تواس میں کوئی قباحت نہیں لیکن دنیا کو اپنا
سب کچھ قرار دینااور اسکو اپنے قلب کا حاکم اور زندگی کا مالک تسلیم کرلینا غلط ہے کیونکہ ایسی صورت میں وہ اپنے اشاروں پر انسان کو نچاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صورت حال قلب کے لئے بیمار ی کا درجہ رکھتی ہے ۔
امیر المومنین حضرت علی نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کے نا م اپنی وصیت میں فرمایاہے :
(ولا تکن الدنیا أکبرهمک )( ۱ )
''دنیا تمہارا سب سے بڑا ہم وغم نہ ہونے پائے ''
دنیا داری میں مشغول ہونے کامنفی رخ یہ ہے کہ خدا سے انسان کا تعلق ختم ہوجاتا ہے ۔ معاملات دنیا میں کھوجانے کا مطلب خدا سے قطع تعلق کرلینا ہے اورفطری بات ہے کہ جب انسان کا ہم وغم اسکی دنیا ہوگئی تو پھر انسان کے ہر اقدام کا مقصد دنیا ہوگی نہ کہ رضائے الٰہی ،اس طرح انسانی قلب پر دنیا کے دریچے جس مقدار میں کھلتے جائیں گے اسی مقدار میں الٰہی دریچے بند ہوتے جائیں گے لہٰذا اگر انسان کی نگاہ میںدنیاوی کاموں کی سب سے زیادہ اہمیت ہوگی تو خدا کی جانب تو جہ کمترین درجہ تک پہونچ جائے گی ۔اور جب سب ہم وغم اور فکر وخیال دنیا کے لئے ہوجائے گا تو یہ کیفیت در حقیقت گذشتہ صورت حال کا نتیجہ اور قلب انسانی کی بدترین بیماری ہے ۔
قرآن کریم نے اس خطرناک بیماری کو متعدد مقامات پر مختلف عناوین کے ذریعہ بیان کیا ہے ۔ہم یہاں پر آیات قرآن کے ذیل میں چند عناوین کا تذکرہ کررہے ہیں :
____________________
(۱)بحارالانوار ج۴۲ص۲۰۲۔
دل کے اوپر خدائی راستوں کی بندش کے بعض نمونے
۱۔غبار اور زنگ
( کلا بل ران علیٰ قلوبهم ماکانوا یکسبون ) ( ۱ )
''نہیں نہیں بلکہ انکے دلو ں پر انکے (برے )اعمال کا زنگ لگ گیا ہے ''
راغب اصفہانی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ''ان کے دلوں کی چمک دمک زنگ آلودہوگئی لہٰذا وہ خیروشرکی پہچان کرنے سے بھی معذورہوگئے ہیں۔
۲۔الٹ،پلٹ
یہ ایک طرح کا عذاب ہے جس میں خدا، غافل دلوں کو اپنی یاد سے دور کردیتا ہے جیسا کہ ﷲتعالی کا ارشاد ہے :
( صرف ﷲ قلو بهم بأنهم قوم لایفقهون ) ( ۲ )
''تو خدا نے بھی انکے قلوب کو پلٹ دیا ہے کہ وہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں ''
۳۔زنگ یامُہر
خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( ونطبعُ علیٰ قلوبهم فهم لایسمعون ) ( ۳ )
''ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر انھیں کچھ سنائی نہیں دیتا ''
____________________
(۱)سورئہ مطففین آیت۱۴۔
(۲)سورئہ توبہ آیت ۱۲۷۔
(۳)سورئہ اعراف آیت ۱۰۰۔
یعنی ان کو غیر خدائی ر نگ میںرنگ دیاہے اور وہ ہویٰ وہوس اور دنیا کا رنگ ہے ۔
۴۔مہُر
خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( ختم ﷲ علیٰ قلوبهم وعلیٰ سمعهم وعلیٰ أبصارهم غشاوة ) ( ۱ )
''خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور انکی آنکھوں پر بھی پر دے پڑگئے ہیں ''
ختم(مہر)طبع (چھاپ لگنے)سے زیادہ محکم ہوتی ہے کیونکہ کسی چیز کومُہر کے ذریعہ سیل بند کردینے کو ''ختم''کہتے ہیں ۔
۵۔قفل
خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( أفلا یتد بّرون القرآن أم علیٰ قلوب أقفالها ) ( ۲ )
''تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پرقفل پڑے ہوئے ہیں ''
۶۔غلاف
خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( وقالوا قلوبنا غُلْف بل لعنهم ﷲ بکفرهم ) ( ۳ )
''اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں بیشک ان کے کفر کی بنا
____________________
(۱)سورئہ بقرہ آیت۷۔
(۲) سورئہ محمدآیت ۲۴۔
(۳)سورئہ بقرہ آیت ۸۸۔
پر، ان پر ﷲکی مار ہے ''
دوسرے مقام پر ارشاد ہے :
( وقولهم قلوبناغلف بل طبع ﷲ علیهابکفرهم ) ( ۱ )
''اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلو ں پر فطرتا غلاف چڑھے ہوئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ خدانے ان کے کفر کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے ''
۷۔پردہ
ﷲتعالی کا ارشاد ہے :
( وقالوا قلوبنافی أکنّة مماتدعونا الیه وفی آذاننا وقر ) ( ۲ )
''اور وہ کہتے ہیں کہ تم جن باتوں کی طرف دعوت دے رہے ہو ہمارے دل ان کی طرف سے پردہ میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے ''
دوسری جگہ ارشاد ہے :
( وجعلناعلیٰ قلوبهم أکنّة أن یفقهوه وفی آذانهم وقراً ) ( ۳ )
''لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پرد ے ڈال دئے ہیں ۔وہ سمجھ نہیں سکتے ۔اور ان کے کانوں میں بھی بہراپن ہے ''
۸۔سختی
خداوند عالم کا ارشاد ہے :
____________________
(۱)سورئہ نساء آیت ۱۵۵۔
(۲)سورئہ فصلت آیت ۵۔
(۳)سورئہ انعام آیت ۲۵۔
( ربنا اطمس علیٰ أموالهم واشد د علیٰ قلوبهم ) ( ۱ )
''خدا یا ان کے اموال کو برباد کردے اوران کے دلوں پر سختی فرما''
۹۔قساوت
( فویل للقاسیة قلوبهم من ذکرﷲ ) ( ۲ )
''افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا ( کینہ کرنے )سے سخت ہوگئے ہیں ''
خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم ) ( ۳ )
''تو ایک عرصہ گذرنے کے بعد ان کے دل سخت ہوگئے ''
یہ انسانی دل کے اتار،چڑھائو،اور بند ہونے یا ذکر خدا سے روگرداںہونے کی وہ صورت حال ہے جس کو قرآن مجید نے مختلف انداز سے ذکر کیا ہے ۔
دنیا قید خانہ کیسے بنتی ہے ؟
جب قلب انسانی پر الٰہی راستہ مکمل طریقہ سے بند ہوجائے تو یہی دنیا انسان کے لئے قید خانہ بن جاتی ہے انسان پر ہوس اس طرح غالب آجاتی ہے کہ اس کے لئے رہائی حاصل کرنا ممکن نہیں رہ جاتا ۔کیونکہ قیدخانہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نکلنا ممکن نہیںہوتا اور اسکی حرکتیں محدود ہو جاتی ہیں یہی حالت اس وقت ہوتی ہے کہ جب دنیا انسان کے لئے قید خانہ بن جاتی ہے کہ انسان اسی میں مقید ہوکررہ جاتا ہے حرکتیں محدود ہو جاتی ہیں اور اس سے ہرطرح کی آزادی سلب ہوجاتی ہے اور وہ اسکے
____________________
(۱)سورئہ یونس آیت ۸۸۔
(۲)سورئہ زمر آیت ۲۲۔
(۳)سورئہ حدیدآیت۱۶۔
لئے اہتمام اوراسکی حرص ولالچ کی بناپر خداوند عالم سے بالکل الگ ہوجاتا ہے ۔یہی تفصیلات روایات میں بھی وارد ہو ئی ہیں۔حضرت امام محمد باقر کی دعا کا فقرہ ہے:
(ولاتجعل الدنیا علیّ سجناً )( ۱ )
'' دنیا کو میرے لئے قید خانہ قرارمت دینا ''
حضرت امام جعفر صادق کی دعا ہے :
(ولاتجعل الدنیاعلیّ سجناً،ولا تجعل فراقها لی حزناً )( ۲ )
''دنیا کو میرے لئے قید خانہ اور اس کے فراق کو میرے لئے حزن و ملال کا باعث مت قرار دینا ''
یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے کہ قیدی پر قیدخانہ کا فراق گراں گذر رہا ہے اور وہ رہائی پانے کے بعد حزن و ملال میں مبتلا ہے ؟اس کا راز یہ ہے کہ یہ قید خانہ دو سرے قید خانوں کے مانند نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ایسا قید خانہ ہے کہ انسان اس سے انس و الفت کی وجہ سے خود اپنے آپ کوقیدی بناتا ہے چونکہ خود قید کو اختیار کرتا ہے لہٰذا وہ اس سے جدائی گوارا نہیں کرتا اور اگر اسے قید سے جدا کردیا جائے تواس رہا ئی سے اسے حزن وملال ہوتا ہے اور قید کا فراق اس کیلئے دشوار اور باعث زحمت ہو تا ہے ۔
جب انسان اپنا اختیار دنیا کے حوالے کر دیتا ہے تو دنیا اسے کیکڑے کے مانند اپنے چنگل میں د بوچ کر اس کے ہاتھ اور پیر وںکوجکڑ دیتی ہے اور اس کی حرکتوں کو مقید و محدود کرکے اسے اپنا اسیر بنا لیتی ہے ۔
امیر المو منین حضرت علی کا ارشاد گرا می ہے :
(ان الدنیا کالشبکة تلتفّ علیٰ من رغب فیها )
''دنیا جال کے مانند ہے جو اس کی طرف راغب ہو گا اسی میںالجھتا جا ئے گا ''
____________________
(۱)بحارالانوارج ۹۷ص۳۷۹۔
(۲)بحارالانوار ج۹۷ص۳۳۸۔
(۳)غررالحکم۔
آپ کا یہ قول ہمارے سامنے ایک بار پھر قید خانہ اور قیدی کے تعلق اور رابطہ کو اجا گر کرتا ہے ''تلتف علیٰ من رغب فیھا ''جو اسکی طرف راغب ہوا وہ اسی پر لپٹتا چلاجائے گا۔
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(من أحبّ الدینار والدرهم فهوعبد الدنیا )( ۱ )
''جو درہم و دینار سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کا غلام ہے ''
اہل دنیا
کچھ افراد دنیا دارہو تے ہیں اور کچھ '' اہل آخرت ''دنیا داروہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو دائمی زندگی سمجھ کراسی کے دلداہ ہو تے ہیںاور دنیا کی فرقت انھیں اسی طرح نا گوار ہو تی ہے جیسے انسان کو اپنے اہل و عیال کی جدائی برداشت نہیں ہو تی ہے ۔
اہل آخرت ،دنیا میں اسی طرح رہتے ہیں جیسے دوسرے رہتے ہیں ۔اوردنیا کی حلال لذتوں سے ایسے ہی لطف اندوز ہو تے ہیں جیسے دوسرے ان سے مستفیدہو تے ہیں بس فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو دا ئمی زند گی مان کر اس سے دلبستگی کا شکار نہیں ہو تے ۔ایسے افراد درحقیقت '' اہل ﷲ '' ہو تے ہیں ۔
اہل آخرت اوردنیا داروںکے صفات ایک دوسرے سے الگ ہیں ۔چنانچہ حدیث معراج میں دنیا داروںکے صفات یوں نظر آتے ہیں جیسا کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے مروی ہے :
(أهل الدنیا من کثر أ کله وضحکه ونومه وغضبه،قلیل الرضا،لایعتذر الیٰ من أساء الیه،ولایقبل معذرة من اعتذرالیه،کسلان عند الطاعة ۔)( ۲ )
'' دنیاداروں کی غذا ،ہنسی ، نیند ،اور غصہ زیادہ ہو تا ہے ۔یہ لوگ بہت کم راضی ہو تے ہیں،
____________________
(۱)بحارالانوار ج۱۰۳ ص۲۲۵ ۔
(۲)بحارالانوارج ۷۷ص ۲۴۔
جس کے ساتھ ناروابرتائو کرتے ہیں اس سے معذرت نہیں کرتے ۔کو ئی ان سے معذرت کاخواہاں ہو تو اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتے، اطاعت کے مو قع پر سست اور معصیت کے مقام پر بہادر ہو تے ہیں ان کے یہاں امن مفقود اور موت نزدیک ہو تی ہے ۔کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے ، ان کے یہاں منفعت برائے نام ،باتیں زیادہ اور خوف کم ہو تا ہے یقینادنیا دارنہ آسا ئشوں میں شکر خدا کرتے ہیں اور نہ ہی مصیبت کی گھڑی میں صبر ۔جو کام انجام نہیں دیتے اس پر اپنی تعریف کرتے ہیں ، جو صفا ت ان میں نہیں پائے جاتے ان کے بھی مد عی ہوتے ہیں،جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں لوگوں کے عیوب تو ذکر کرتے ہیں مگر ان کی خوبیاںبیان نہیں کرتے ''
دنیادار دنیا سے سکون حاصل کرتے ہیں اسی سے مانوس ہو تے ہیں اور اسی کو اپنا دائمی مستقر سمجھتے ہیں حالانکہ دنیا ''دارالقرار ''نہیں ہے ۔چنانچہ جب کوئی انسان اس سے مانوس ہوکر تسکین قلب حاصل کرلے تو وہ فریب دنیا کے شرک میں مبتلاہوجاتا ہے کیونکہ وہ اسے دارالقرار سمجھتے ہیں جبکہ وہ ایسی نہیں ہے ۔
امیر المو منین حضرت علی فر ماتے ہیں :
(واعلم انک انماخُلقت للآخرة لا للدنیا،وللفناء لاللبقائ،وللموت لاللحیاة،وأنک فی منزل قلعة وداربلغة،وطریق الیٰ الآخرة وایاک أن تغترّبما تریٰ من اخلادأهل الدنیاالیها،وتکالبهم علیها،فقدنبّأک ﷲعنها،ونَعَتْلک نفسها،وتکشّفت لک عن مساویها )( ۱ )
''۔۔۔اوربیٹا!یادرکھو کہ تمہیں آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے دنیا کے لئے نہیں اور فنا کے لئے بنایاگیا ہے دنیا میں باقی رہنے کے لئے نہیں ،تمہاری تخلیق موت کے لئے ہوئی ہے زندگی کے
____________________
(۱)نہج البلاغہ مکتوب ۳۱۔
لئے نہیں تم اس گھر میں ہوجہاں سے بہر حال اکھڑنا ہے اور صرف بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے اور تم آخرت کے راستہ پر ہو ۔۔۔اور خبر داردنیاداروں کو دنیا کی طرف جھکتے اور اس پر مرتے دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آجاناکہ پروردگار تمہیں اسکے بارے میں بتاچکا ہے اور وہ خود بھی اپنے مصائب سناچکی ہے اور اپنی برائیوں کو واضح کرچکی ہے ۔۔۔''
دنیا کابہروپ
یہ ایک بہروپ ہی ہے کہ انسان دنیا کو دارالقرار سمجھ کر اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس سے دل لگا بیٹھتا ہے حالانکہ دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے ۔نہ خوددنیا کو قرار ہے اورنہ ہی دنیا میںکسی کیلئے قرار ممکن ہے ۔یہاں انسان کی حیثیت مسافر کی سی ہے کہ جہاں چند دن گذار کر آخرت کے لئے روانہ ہوجاتا ہے تعجب ہے کہ اس کے باوجودبھی انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اسے دائمی قیام گاہ مان لیتا ہے ۔
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا :
(کن فی الدنیاکانک غریب،أوکأنک عابرسبیل )( ۱ )
''دنیا میںایک مسافر کی طرح رہو جیسے کہ راستہ طے کر رہے ہو ''
امیر المو منین حضرت علی کا ارشاد ہے:
(أیهاالناس انّماالدنیادارمجاز،والآخرةدارقرار،فخذوامن ممرّکم لمقرّکم )( ۲ )
'' اے لوگو !یہ دنیا ایک گذرگاہ ہے قرار کی منزل آخرت ہی ہے لہٰذا اسی گذرگاہ سے وہاں کا
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۳ ص۹۹۔
(۲)نہج البلاغہ خطبہ ۲۰۳۔
سامان لے کر آگے بڑھو جو تمہارا دار قرار ہے ''
اس مسئلہ پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے ۔جو انسان راستہ سے گذر تار ہے وہ کبھی راستہ کا ہو کر نہیں رہ جاتا اسکے برخلاف گھر میں رہنے والے انسان کو گھر سے محبت ہو تی ہے اور آدمی گھر کا ہوتا ہے اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم کا ایک معرکة ا لآرا جملہ نقل کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ نے فر مایا ہے :
(من ذا الذی یبنی علیٰ موج البحرداراً،تلکم الدنیا فلا تتخذوها قراراً )( ۱ )
''سمندر کی لہروں پر کون گھر بناتا ہے ؟دنیا کا بھی یہی حال ہے لہٰذا دنیا کو قرار گاہ مت بنائو ''
جیسے سمند ر کی لہروں کو قرار و بقا نہیں ہے ایسے ہی دنیا بھی ہے۔توپھر نفس اس سے کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے اوراسے کیسے دائمی تسلیم کر سکتا ہے کیا واقعا کو ئی انسان سمندر کی لہروں کے اوپراپنا گھر بنا سکتا ہے ؟
روایت ہے کہ جناب جبرئیل نے حضرت نوح سے سوال کیا :
(یا أطول الانبیاء عمراً،کیف وجدت الدنیا؟قال:کدار لها بابان،دخلت من أحدهما،وخرجت من الآخر )( ۲ )
''اے طویل ترین عمر پانے والے نبی خدا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا ؟حضرت نوح نے جواب دیا ''ایک ایسے گھر کی مانند جس میں دو دروازے ہوں کہ میں ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل آیا ''
عمر کے آخری حصہ میں شیخ الانبیائ(حضرت نوح ) کا دنیا کے بارے میں یہ احساس در اصل اس شخص کا صادقانہ احساس ہے کہ جو فریب دنیا سے محفوظ رہا ہو ۔
____________________
(۱)بحارالانوار ج۱۴ص۳۲۶۔
(۲)میزان الحکمت ج۳ ص۳۳۹۔
لیکن اگر انسان دنیا سے مانوس ہو جا ئے اور دنیا اس کے لئے وجہ سکون بن جائے تو پھر یہ احساس تبدیل ہو جاتا ہے اور دنیا اس کو اپنے جال میں الجھا لیتی ہے انسان فریب دنیا کا شکار ہو کر شرک دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے ۔یہ '' ان دنیا داروں''کا حال ہو تا ہے جن کے خیال خام میں دنیا دارالقرار اور وجہ سکون ہے۔
تیسری فصل
جو شخص خداوند عالم کی مرضی کو
اپنی خواہشات کے اوپر ترجیح دیتا ہے
گذشتہ فصل میں ہم نے ''اپنی خواہش کو خدا کی مرضی کے اوپر ترجیح دینے والے شخص کے بارے میں ''تفصیلی گفتگو کی ہے اور اب انشاء ﷲ''خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دینے والے کے بارے میں ''گفتگو کریں گے ۔لیکن اصل بحث چھیڑنے سے پہلے ہم ان تمام روایات کوان کے حوالوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جن میں اس حدیث قدسی کا تذکرہ ہے ۔
شیخ صدوق(رح)نے اپنی کتاب''خصال''میں اپنی سند کے ساتھ امام محمد باقر سے روایت نقل کی ہے آپ نے فرمایا کہ :
(ان ﷲعزوجل یقول:بجلالی وجمالی وبهائی وعلا ئی وارتفاعی لایؤثر عبد هوای علیٰ هواه الاجعلت غناه فی نفسه،وهمّه فی آخرته،وکففت عنه ضیعته،وضمنت السموات والارض رزقه،وکنت له من وراء تجارةکل تاجر )( ۱ )
خداوند عالم کا ارشاد ہے :''میرے جلال وجمال،حسن ،ارتفاع اوربلندی کی قسم کوئی بندہ اپنی خواہش پر میری مرضی کو ترجیح نہیں دیگامگر یہ کہ میں اسکے نفس کے اندر استغناپیدا کردوںگا اور اسکی پونجی کا ذمہ دار رہوں گا۔زمین وآسمان اسکے رزق کے ضامن ہیں اور میں اسکے لئے ہر تاجر کی تجارت سے بہتر ہوں''
شیخ صدوق نے ''ثواب الاعمال''میں امام زین العابدین سے یہ روایت مع سند نقل کی ہے
____________________
(۱)بحار الانوار ج۷۰ ص۷۵ ۔
(انّ ﷲعزّوجل یقول:وعزّتی وعظمتی وجلالی و بهائی وعلوّی وارتفاع مکانی لایؤثرعبد هوای علیٰ هواه الاجعلت همه فی آخرته،وغناه فی قلبه،وکففت علیه ضیعته،وضمنت السمٰوات والارض رزقه،وأتته الدنیا وهی راغمة )( ۱ )
''آپ نے فرمایا کہ خداوند عزوجل ارشاد فرماتا ہے: میری عزت،عظمت،جلالت،جمال، رفعت اور میرے مکان کی بلندی اور ارتفاع کی قسم کوئی بندہ میری مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح نہیں دیگامگر یہ کہ میں اس کی کل فکر اس کی آخرت کے لئے قرار دیدونگااوراسکے قلب میں استغنا پیدا کر دونگااور اس کی پونجی کا ذمہ دار رہونگا ۔ آسمان و زمین اسکے رزق کے ضامن ہیں اور اسکے سامنے جب دنیا آئے گی تو اسکی ناک رگڑی ہوئی ہوگی''
ابن فہد حلی(رح)نے اپنی کتاب ''عدةالداعی''میں رسول ﷲصلىاللهعليهوآلهوسلم سے یہ روایت نقل کی ہے :کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :
(وعزّتی وجلالی وعظمتی وکبریائی ونوری وعلوّی وارتفاع مکانی لایؤثرعبد هوای علیٰ هواه،الا استحفظته ملا ئکتی وکفّلت السمٰوات والارض رزقة،وکنت له من وراء تجارةکل تاجر،وأتته الدنیا وهی راغمة )( ۲ )
''میری عزت ،جلالت،عظمت،کبریائی،نور،بلندی اور رفیع مقام کی قسم کوئی بندہ میری (خواہش )مرضی کو اپنی خواہش پر ترجیح نہیں دیگامگر یہ کہ ملائکہ اسکی حفاظت کرینگے ۔آسمان اور زمین اسکے رزق کے ذمہ دار ہیں اور ہر تاجر کی تجارت کے پس پشت میں اسکے ساتھ موجود ہوں اور دنیا اسکے سامنے ذلت و رسوائی کے ساتھ حاضر ہوگی''
____________________
(۱) بحارالانوار ج۷۰ص۷۷از ثواب الاعمال۔
(۲)بحارالانوار ج۷۰ص۷۸۔
شیخ کلینی نے اصول کافی میں سند کے ساتھ یہ روایت امام محمد باقر سے یوںنقل کی ہے :
(۔۔۔الاکففت علیہ ضیعتہ وضمنت السموات والارض رزقہ،وکنت لہ وراء تجارةکل تاجر)( ۱ )
''مگر یہ کہ میں اسکے ضروریات زندگی (پونجی)کا ذمہ دارہوں اور آسمان و زمین اسکے رزق کے ضامن ہیں اور میںہر تاجر کی تجارت کے پس پشت اسکے ساتھ ہوں ''
مرضی خدا کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا
اس ترجیح دینے کے معنی یہ ہیں کہ انسان خداوند عالم کے ارادہ کو اپنی خواہشات کے اوپر حاکم بنالے اور احکام الٰہیہ کے مطابق اپنے نفس کو اسکی خواہش سے روکتا رہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے :
( وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهویٰ فان الجنة هی الماوی ٰ ) ( ۲ )
''اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، جنت اسکا ٹھکانہ اور مرکز ہے ''
تقویٰ اور فسق وفجور (برائیوں)کے راستے جس نقطہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں وہ نقطہ وہی ہے جہاں خداوند عالم کی خواہش (اسکا حکم اور قول)اور انسان کی خواہش (ہوس)کے درمیان ٹکرائو پیدا ہوتا ہے ۔چنانچہ جب انسان خدا کی خواہش (مرضی )کو اپنی خواہش کے اوپر ترجیح دیتا ہے تو وہ تقوے کے راستہ پر چلنے لگتاہے اور جب اپنی خواہشوں کو خداکی مرضی کے اوپر ترجیح دینے لگتا ہے تو فجور(برائیوں)کے راستے پر لگ لیتا ہے ۔
____________________
(۱)بحار الانوار ج۷۰ص۷۹۔
(۲)سورئہ نازعات آیت ۴۰۔۴۱۔
۱۔جعلت غناہ فی نفسہ
''اسکے نفس میں استغنا پیدا کردوں گا''
لوگوں کے درمیان عام تاثر یہ ہے کہ فقر وغنی ٰکا تعلق سونے اور چاندی اور زروجواہرات سے ہے اور نفس و قلب سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اسلام میں فقرو غنیٰ کا مفہوم اسکے برعکس ہے اسلام کی نگاہ میں فقر اور غنیٰ کا تعلق نفس سے ہے نہ کہ مال ودولت سے، لہٰذا ہوسکتاہے کہ ایک ایساانسان غنی ہوجومالی اعتبار سے فقیر ہو اور ہوسکتا ہے کوئی انسان فقیر ہوچاہے وہ مالی اعتبار سے ثروتمند ہی کیوں نہ ہو ۔
امام حسین کی دعائے عرفہ میں وارد ہواہے:
(اللّٰهم اجعل غنای فی نفسی،والیقین فی قلبی،والاخلاص فی عملی، والنور فی بصری،والبصیرة فی دینی )
''پروردگار میرے نفس کو غنی بنادے ،میرے قلب کو یقین،عمل میں اخلاص ،آنکھوں میں نور اور دین میں بصیرت عطافرما''
آخر فقر و غنی کا مفہوم مال ودولت کے بجائے نفس سے متعلق کیسے ہوتاہے؟اسکاراز کیا ہے ؟ در حقیقت تبدیلی کا یہ راز دین اسلام کے پراسرار عجائبات میں شامل ہے۔ہمیں گاہے بگاہے اسکے بارے میں غوروخوض کرنا چاہئے۔
افکار کی تبدیلی میں اسلامی اصطلاحات کا کردار
''فقر''اور''استغنا''دواسلامی اصطلاحیں ہیں اور اسلام اپنی اصطلاحات کے لئے بہت اہمیت کا قائل ہے اسی لئے اسلام نے دور جاہلیت کی کچھ اصطلاحوں کو کا لعدم قرار دیا ہے اور انکی جگہ پر بہت سی نئی اصطلاحات پیش کی ہیں اور انھیں اصطلاحات کے ذریعہ فکروخیال میں تبدیلی کی ہے اور قدروقیمت کا نیا نظام پیش کیاہے۔دورجاہلیت میں اقدار کے اصول جدا تھے جبکہ اسلام کے اصول الگ ہیں۔
کبھی اسلام دور جاہلیت کی قدروں کو مکمل طریقہ سے ختم کرتا ہے اور ان کی جگہ پر سماجی زندگی کے جدید اقدار کوروشناس کراتاہے ۔زمانہ جاہلیت میں جس چیز کو سیاسی،اخلاقی اورسماجی زندگی میں بے قیمت سمجھاجاتاتھا اسلام نے اسی چیز کو سیاسی،سماجی اور اخلاقی طور پر بیش قیمت بناکر پیش کیاہے۔
مثلاً دور جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت اور قدروقیمت نہیں تھی لوگ لڑکیوں کے وجودکو ننگ وعار سمجھتے تھے لیکن اسلام نے اسی بے قیمت سمجھی جانے والی چیز کو عظیم ترین بلندی عطا کی۔
قدروقیمت کا اختلاف در اصل قدروقیمت کے نظام میں اختلاف کی بنیاد پر سامنے آتاہے کیونکہ تمام اقدار حقیقتاًکسی نہ کسی اصول اورنظام کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں جن کی معرفت کے بغیر اقدار کی معرفت ممکن نہیں ہے ۔
دین اسلام نے اپنی اصطلاحات کے ذریعہ اقدار کے اصول ونظام کو تبدیل کیا ہے جسکے نتیجہ میں اقدار خودبخود تبدیل ہوجاتے ہیں اورسماج میں تبدیلی آجاتی ہے بطور نمونہ فقط اس تبدیلی کی جانب اشارہ کردینا کافی ہے جو اسلام نے فقروغنی کے معیار میں کی ہے جس کے نتیجہ میں ان کے مفہوم میں بھی تبدیلی پیدا ہوگئی ہے۔
فقرواستغنا اور اقدار کے اسلامی اصول
عام طورسے لوگوں کے درمیان فقر وغنی کا مطلب مال ودولت کی قلت وکثرت ہے۔یعنی جسکے پاس زیادہ سونا چاندی نہ ہو وہ فقیرہے اور جس کے پاس سونا چاندی و افر مقدار میں ہوا سے غنی کہاجاتاہے اور مالداری کے درجات بھی مال کی مقدارسے طے ہوتے ہیں۔یعنی جس شخص کی قوت خرید جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی بڑا مالدار شمار کیا جاتا ہے اسکے برخلاف جس کے پاس روپے پیسوں کی قلت ہووہ اتناہی غریب سمجھاجاتاہے۔اس طرح عام لوگوں کے خیال میں فقر واستغنا کا تعلق کمیّت''مال کی مقدار'' سے ہے۔
دور جاہلیت کا نظام قدروقیمت
فقرواستغناکے ان معنی میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے اور اگر بات یہیں تمام ہوجاتی تو اسلام اسکی مخالفت نہ کرتا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ جاہلیت کے نظام کے تحت ثروتمندی سے سماجی اور سیاسی اقدار بھی جڑجاتے ہیں اور ثروتمندانسان معززو محترم کہلاتاہے اسکی سماجی حیثیت اوراسکے سیاسی نفوذ میں اضافہ ہوجاتاہے وہ لوگوں کا معتمدبن جاتاہے وغیرہ۔۔۔اس طرح نظام جاہلیت میں واضح طور پر کمیت( Quantity )کیفیت( Quality )میں تبدیلی ہوجاتی ہے۔
جب بھی ہم غور کریں گے تو ہمیں صاف محسوس ہوگاکہ یہاں زروجواہر کی مقدارو کمیت ( Quantity )سماجی اور سیاسی کیفیت میں تبدیلی ہوگئی ہے بلاشبہ اجتماعی اور سماجی زندگی میں مقداروکمیت( Quantity )اور کیفیت میں براہ راست تعلق پایاجاتا ہے اور اس تعلق اور رابطہ کو ختم کرنایا اسکا انکار ناممکن ہے اور اسلام بھی اس تعلق اور رابطہ کو ختم کرنا نہیں چاہتابلکہ اس رابطہ کو الٹ دینا چاہتا ہے یعنی کمیت اور مقدار کو کیفیت کا تابع قرار دیتا ہے نہ کہ کیفیت کو کمیت کا۔
مثلاًاقتصادی اور کاروباری معاملات کی بنیاد صداقت اور تقویٰ ہوناچاہئے اور اسی بنیاد پر کاروبار کو وسعت دینا چاہیے یا سیاسی میدان میں بھی ہرچیزکی بنیاد صداقت اور تقویٰ ہوناچاہئیے اوراسی بنیاد پرووٹ حاصل کرنا چاہیے کہ یہی چیزیںصحتمند معاشرے کی پہچان ہیں۔
لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو اور سماجی یا سیاسی زندگی میں کمیت ومقدار معیار بن جائے تو سماج میں پائے جانے والے اقدار و اصول کا وجود خطرہ میں پڑجاتاہے۔دور جاہلیت میں بعینہ یہی صورت حال موجود تھی کہ مادیت پرروحانیت کی حکومت ہونے کے بجائے مادیت،روحانیت پر حاکم ہوگئی تھی اور قدروقیمت کا تعیّن مادیت سے ہوتاتھا نہ کہ معنویت سے۔
اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ یہی صورت حال مسلمانوں کے سامنے بھی آئی اسلام نے قدروقیمت کا ایسا نظام پیش کیا تھا کہ جو دور جاہلیت کے پروردہ لوگوں کے لئے نامانوس تھا۔ اس نظام میں اسلام نے قدروقیمت اورمنزلت کا معیار روحانیت کو قرار دیا تھا اور مادیت کو روحانیت کا تابع بنایاتھا۔لیکن جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور قیصر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور سرحدوں کی وسعت کے ساتھ دولت میں بھی بے پناہ اضافہ ہواتو مادیت غالب آگئی اور قدروقیمت کا نظام پس پشت چلاگیا۔اور دوبارہ زروجواہر ہی تمام اقدار کا معیار بن گئے اور انکی حالت اس عہد کی سی ہوگئی جس میں خداوند عالم نے رسول اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کو مبعوث کیا تھا اور آپ کو قائدوپیشوا اور رسول بنا کر بھیجاتھا۔
عثمان بن عفان کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب جب حاکم مسلمین ہوئے تو آپ نے محسوس کیا کہ اسلامی معاشرہ اس طرح منقلب ہوچکا ہے کہ جیسے کوئی اس طرح الٹا لباس پہن لے جسکا اندرونی حصہ باہر،اور ظاہری حصہ اندر ،اوپری حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر ہوگیا ہو۔ چنانچہ امیر المومنین بنی امیہ کے بارے میں فرماتے ہیں:
(ولُبس الاسلام لُبسَ الفرومقلوباً )( ۱ )
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۱۰۸۔
''اسلام یوں الٹ دیا جائے گا جیسے کوئی الٹی پوستین پہن لے''
جیسا کہ آپ نے ان الفاظ میں اسکی عکاسی کی ہے :
(ألا وان بلیّتکم قدعادت کهیئتها یوم بعث اللّٰه نبیکم،والّذی بعثه بالحقّ لتبلبلنّ بلبلةً ولتغربلنّ غربلةً،ولَتساطُنّ سَوطَ القدرحتّی یعود اسفلکم أعلاکم )( ۱ )
''یاد رکھو! تمہارا امتحان بالکل اسی طرح ہے جس طرح پیغمبر کی بعثت کے دن تھا اس ذات کی قسم جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا تم بری طرح تہ وبالا کئے جائو گے اور اس طرح چھانے جائو گے جس طرح چھنّی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے اور اس طرح خلط ملط کئے جائو گے جس طرح پتیلی کے کھانے کو پلٹاجاتا ہے یہاں تک کہ تمہارے ادنیٰ اعلیٰ اور اعلیٰ ادنیٰ ہوجائیںگے ''۔
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عنقریب یہ قوم اسلامی اقدار ومفاہیم اور اصول کو چھوڑ کر ایک عظیم فتنہ میں مبتلا ہونے والی ہے اور اسکی وہ حالت ہوجائے گی جو کھولتے ہوئے شوربہ کی ہوتی ہے کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہوجاتاہے۔
فتوحات کی وسعت اور خدا کی جانب سے رزق میں فراوانی کے باعث امت اسلامیہ کی یہی حالت ہوگئی تھی جیسا کہ مال و نعمت کی زیادتی کے باعث عہد جاہلیت کی بھی یہی افسوسناک حالت تھی۔
دور جاہلیت کے نظام قدروقیمت کو تبدیل کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لئے اسلام نے فقر اوراستغنا کی نئی اصطلاحیں ایجاد کیں اور انہیں نئی اصطلاحوں اور نئے مفاہیم کے ذریعہ دور جاہلیت کے نظام قدروقیمت کو تبدیل کردیا۔
قدروقیمت کا اسلامی نظام
لفظ غنی یا استغنا کے معنی کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے ۔ایک بیان کے مطابق استغنا کا
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۱۶۔
مطلب ہے ''انسان کے پاس زر وجواہر کا بکثرت موجود ہونا''اس طرح غنی کے معنی کا تعلق عالم محسوسات سے ہے اور یہ مطلب لفظ ''ثروتمند''کے مترادف ہے۔
دوسرے بیان کے مطابق حقیقتاً استغنا سے مراد''دل کا مستغنی ہونا'' ہے جو کہ ﷲ تعالیٰ پر ایمان اور توکل سے حاصل ہوتا ہے اور اس معنی کا مال کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عین ممکن ہے کہ انسان کے پاس بے پناہ مال ودولت ہو مگر پھر بھی وہ فقیر ہو اور ہوسکتا ہے کہ مال ودولت بالکل نہ ہو پھر بھی انسان غنی ہو۔
فقر واستغنا کے یہ معنی،لغوی اور رائج معنی سے بالکل مختلف ہیں۔اور ان معنی کے لحاظ سے استغنا کا تعلق نفس انسانی سے ہے نہ کہ مال ودولت اور خزانہ سے۔
دین اسلام لفظ فقر واستغنا کو نئے معنی و مفاہیم دے کر در اصل دور جاہلیت کے نظام قدروقیمت کو تبدیل کرکے اسکے مقابلہ میں جدید نظام پیش کرنا چاہتا ہے۔
اسکی مزید وضاحت کے لئے ہم استغنا اور فقر کے بارے میں اسلامی روایات کی روشنی میں پہلے لفظ استغنا کا مطلب بیان کریں گے اور پھر اس جدید نظام کی وضاحت کریں گے جو اسلام نے قدروقیمت کے سلسلہ میں پیش کیا ہے۔
اسلامی روایات میں استغنا کا مفہوم
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:
(لیس الغنیٰ عن کثرة العرَض،ولکن الغنیٰ غنیٰ النفس )( ۱ )
''مال ومتاع کی کثرت کانام استغنانہیں بلکہ استغناکا مطلب نفس کا مستغنی ہونا ہے''
____________________
(۱)تحف العقول ص۴۶۔
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:
(الغنیٰ فی القلب،والفقر فی القلب )( ۱ )
''استغنا بھی دل میں ہوتا ہے اور فقر بھی دل ہی میں ہوتا ہے''
امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا ہے:
(الغنی من استغنیٰ بالقناعة )( ۲ )
''غنی وہ ہے جو قناعت کے باعث مستغنی ہو''
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:
(لاکنز اغنیٰ من القناعة )( ۳ )
''غنی(ہونے)کے لئے قناعت سے بڑھکر کوئی خزانہ نہیں ہے''
نیز آپ نے فرمایا ہے:
(طلبت الغنیٰ فماوجدت الّاالقناعة،علیکم بالقناعة تستغنوا )( ۴ )
''میں نے استغنا کو تلاش کیا تو مجھے قناعت کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ تم بھی قناعت اختیار کروتو مستغنی ہوجائوگے''
امام محمد باقر کا ارشاد ہے:
(لا فقرکفقرالقلب،ولا غنیٰ کغنیٰ القلب )( ۵ )
____________________
(۱) بحارالانوار ج۷۲ص۶۸۔
(۲)غررالحکم ج۱ص۶۲۔
(۳)نہج البلاغہ حکمت ۳۷۱۔
(۴)سفینةالبحارج۲ص۸۷ ،الحیات جلد ۳ ص ۳۴۲۔
(۵)تحف العقول ص۲۰۸۔
''دل کی فقیری جیسا کوئی فقر نہیں ہے اور دل ہی کے استغناجیسی کوئی مالداری بھی نہیں ہے''
امام ہادی کا ارشاد ہے:
(الغنیٰ قلّة تمّنِیکَ،والرضا بمایکفیک )( ۱ )
''استغناکا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خواہشات کم ہوں اور جتنا تمہارے لئے کافی ہے اسی پر راضی رہو''( خواہشات کا کم ہونا اور' بقدر کافی 'پر راضی ہوجانااستغناہے۔)
اس طرح اسلام نے استغنا کا تعلق سونے چاندی ،زمین جائداد سے ختم کر دیا اور اسے نفس کے متعلق قرار دیا ہے بلکہ اسلامی رو ایات تو اس سے بڑھ کریہاں تک بیان کرتی ہیں کہ جو افراد مال ودولت کے لحاظ سے ثروتمند ہوتے ہیں اکثر وہ افراد دل کے چھوٹے اور فقیر ہوتے ہیں۔
عموماًجب انسان دنیاوی لحاظ سے مالدار ہوتا ہے تو دل کا چھوٹا اور فقیر ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ثروتمند ہونے اور نفس وقلب کے اعتبار سے چھوٹے اور فقیر ہونے میں کوئی معکوس رابطہ ہو۔نہیں ہرگز نہیں ان دونوں باتوں میں کوئی معکوس رابطہ نہیں ہے۔در حقیقت ایسی صورت حال ان عوارض کے باعث پیدا ہوتی ہے کہ جو عموماًمعاشرہ میں رائج ثروتمند ی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔
امیر المومنین حضرت علی سے روایت ہے:
(۔۔۔وغنِیّها(الدنیا)فقیر )( ۲ )
'' ۔۔۔اور دنیا کا غنی فقیر ہوتا ہے''
حضرت امام زین العابدین نے فرمایا :
____________________
(۱)بحارالانوار ج۸۷ص۳۶۸۔
(۲)بحارالانوار ج۷۸ص۱۴۔
(من اصاب الدنیا اکثر،کان فیها أشَدّ فقراً )( ۱ )
''جسے دنیازیادہ نصیب ہوجائے گی وہ دنیا میں زیادہ فقیر ہوگا''
جسے دنیازیادہ نصیب ہوجائے گی وہ دنیا میں زیادہ فقیر ہوگایہ لازم و ملزوم کیوں ہیں ؟ ثروتمندی اور استغنا دونوں لفظ غنی کے ہی معنی ہیں مگر ان کے درمیان معکوس رابطہ کیوں پایا جاتا ہے؟اس سوال کا جواب اوراس رابطہ کا سبب ہمیں امیر المومنین حضرت علی کی اس حدیث سے بخوبی معلوم ہو جائے گا آپ نے فرمایا :
(الغَنِیّ الشَّرِهُ فقیر )( ۲ )
''لالچی مالدار فقیر ہوتا ہے''
اس حدیث مبارک میں غنی سے مراد ثروتمند ہے اور فقیر سے مراد نفس و قلب کے اعتبار سے فقیر ہے اور اس حدیث میں جو لفظ''شرہ''حریص آیا ہے وہ اس معکوس رابطہ کو بیان کرتا ہے اس لئے کہ عام لوگوں کے لحاظ سے جس کے یہاں استغنا پایا جاتا ہے جو ثروتمند ہوتا ہے وہ عموماًحریص بھی ہوتا ہے اور عموماًجتنا مال ودولت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے آدمی کی حرص و ہوس میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہ طے شدہ ہے کہ جب حرص و طمع میں اضافہ ہوگا تو انسان کی اذیت و پریشانی میں اضافہ ہوگا انھیں دونوں حقیقتوں کی جانب قرآن کریم نے اس آیت میںاشارہ کیا ہے ارشاد رب العزت ہے:
(انما یرید اللّٰه لیعذّبهم بها فی الحیاة الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون )( ۳ )
''بس ﷲکا ارادہ یہ ہے کہ انہیں کے ذریعہ ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت
____________________
(۱)خصال صدوق ج ۱ صفحہ ۶۴۔
(۲)بحارالانوار ج۷۸ص۲۲۔
(۳) سورئہ توبہ آیت ۵۵۔
کفرہی میں ان کی جان نکل جائے ''
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:
(انما یرید اللّٰه أن یعذّبهم بها فی الدنیا )( ۱ )
''بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں کے ذریعہ ان پر دنیا میں عذاب کرے۔
حرص وطمع اسی وقت پایا جاتا ہے جب انسان قلب کے لحاظ سے فقیر ہو ۔نفس جتنا خالی ہو اور فقیر ہوگا حرص وہوس کا اظہار اتنا ہی شدید ہوگا ۔حضرت دائو د کے دور میں لوگوں کی یہی حالت تھی چنانچہ خداوند عالم نے انھیں تو بہ کرنے اور بارگاہ الٰہی میںواپس آنے کا حکم دیا۔
حرص و ہوس کس منزل تک پہونچ سکتے ہیں سورئہ ص کی یہ آیت اسکی بخوبی نشاندہی کرتی ہے:
(انّ هذا أخی له تسع وتسعون نعجة ولیَ نعجةً واحدة فقال:أکفلنیها و عزّنی فی الخطاب )( ۲ )
''یہ ہمارا بھائی ہے اسکے پاس ننّانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے یہ کہتا ہے وہ بھی میرے حوالے کردے اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے ''
اقدار کے نظام میں انقلاب
اس طرح اسلام نے استغنا کے نئے معنی پیش کئے اور استغناکا تعلق زروجواہر اور مال و
دولت سے ختم کرکے اسے نفس اور قلب سے جوڑدیا ہے اس طرح قدروقیمت کا معیار مال وثروت کے بجائے نفس کو قرار دیا ۔
اسلام کی نگاہ میں انسان کی قدروقیمت اسکے مال ودولت اور منقولہ وغیر منقولہ جائیداد سے
____________________
(۱) سورئہ توبہ آیت ۸۵۔
(۲)سورئہ ص آیت۲۳۔
نہیں طے کی جاسکتی جیسا کہ جاہل افراد آج بھی یہی سوچتے ہیں بلکہ اسلام کی نگاہ میں انسانی قدروقیمت کی بنیاد ﷲپرایمان ،تقویٰ ،علم اور دیگر اخلاقی اقدار ہیں ۔اسلام لفظ ثروتمندی اور فقر کے اصل معنی کا منکر نہیں ہے بلکہ اسلام نے اس معنی کے مفہوم میں اضافہ کیا ہے کہ قدروقیمت کے تعیّن کے وقت بے نیازی اور فقر کے معاشی رخ کو ملحوظ نہ رکھاجائے قدروقیمت کا معیار فقروغنی ہی ہیں مگر اس مفہوم میں کہ جو اسلام نے پیش کیا ہے ۔
امیر المومنین کا ارشاد ہے :
(لیس الخیرأن یکثرمالک،ولکن الخیرأن یکثرعلمک،وأن یعظم حلمک،وأن تباهی الناس بعبادة ربک،فان أحسنت حمدت ﷲ،وأن أسأت استغفرت ﷲ )( ۱ )
''بھلائی یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو۔حلم عظیم ہو اور عبادت پروردگار کو فخر ومباہات کا معیار قرار دو چنانچہ اگر تم نے اچھی طرح عبادت انجام دی ہوتو حمد خدا کرو اور اگر عبادت میں کمی کی ہوتو بارگاہ الٰہی میں استغفار کرو ''
چنانچہ جب قدروقیمت کا نظام بدل جائے گا تو خود بخود لوگوں کی سماجی اور سیاسی حیثیت میں بھی فرق آجائے گا اس لئے کہ کسی بھی تہذیب میں اگر اقدار ایک جانب اپنے نظام سے جڑے ہوتے ہیں تو دوسری جانب انکا تعلق سماجی ،سیاسی معاشی اور علمی حیثیت و منزلت سے بھی ہوتا ہے ۔
اگر آج ہمیں جاہلیت زدہ مغربی تہذیب میں یہ نظر آتا ہے کہ اس تہذیب میں سرمایہ داری کا دخل کتنا ہے ،سیاست ،معاشیات اور پروپیگنڈہ پر سرمایہ کا کتنا تسلط اور غلبہ ہے ،صدراور حکومت کے انتخابات میں سرمایہ داری کا کتنا اہم کردار ہے میڈیا یہاں تک کہ سیاسی روابط سبھی کچھ سرمایہ داری
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت ۹۴۔
کے تابع ہیں! ہماری نگاہ میں اسکا سبب یہ ہے کہ اس تہذیب کی بنیاد مادیت پر ہے نہ کہ اخلاقی اور روحانی اقدار پر۔ اسکے برخلاف اسلام کی نگاہ میں ان چیزوں کی بنیاد اخلاقی و روحانی اقدار ، بندہ کا اللہ سے رابطہ ،عدالت وتقوی اور علم پر استوار ہے ۔ارشاد پروردگار ہے:
( انّما یخشیٰ ﷲ من عباده العلمائُ ) ( ۱ )
''ﷲ سے ڈرنے والے اسکے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہیں ''
دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے :
( اِنّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقیٰکُمْ ) ( ۲ )
''بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے ''
اسلام ،قائدا و رہبرمسلمین کے لئے تقویٰ اور عدالت کو ضروری قرار دیتا ہے اسی طرح قاضی،پیش نماز اورامین (جس کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے ہیں) بہ الفاظ دیگر ان تمام افراد کے لئے تقوی و عدالت کو لازمی شرط قرار دیتا ہے جو سماج اور معاشرہ میں کسی بھی عنوان سے مقام ومنزلت کے مالک ہوں۔اسی لئے جب نظام اقدار میں تبدیلی آئے گی توخود بخودمعاشرہ کی سماجی،سیاسی،معاشی،علمی،دینی حیثیتوں میں تبدیلی ناگزیر ہے ۔
اس طرح تین مرحلوں میں یہ عمل انجام پاتا ہے :
۱۔نظام اقدار میں تبدیلی
۲۔اقدار میں تبدیلی
۳۔سماجی اور سیاسی حیثیت میں تبدیلی
____________________
(۱)سورئہ فاطر آیت ۲۸۔
(۲)سورئہ حجرات آیت ۱۳۔
اب جبکہ استغنا سے متعلق اسلامی نظریہ واضح ہو گیا اور لوگوں کی زندگی میں اس کے کردار کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگیا تو اب ہم نفس کے استغنا اور بے نیازی کے بارے میں کچھ بیان کرسکتے ہیں جس کے بارے میں حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں ''جعلت غناہ فی نفسہ ''
نفس کی بے نیازی
سوال یہ کہ نفس کی بے نیازی ہے کیا ؟اور ہم اپنے اندر یہ بے نیازی کیسے پیدا کرسکتے ہیں ؟
در اصل نفس کی بے نیازی اس میں مضمر ہے کہ انسان مادیات اور دنیا پر اعتماد نہ کرے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے اس لئے کہ دنیا فانی ہے اور ذات الٰہی دائمی ، ما دیات محدود ہیں اور خدا کی سلطنت لا محدود ۔
لہٰذا جب انسان اللہ پر توکل اور بھروسہ کے سہارے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو کبھی بھی کمزوری اور نا توانی محسوس نہیں کرے گا ۔حالات کتنے ہی منقلب کیوں نہ ہو جا ئیں ،آسانیاں سختیوں میں تبدیل کیوں نہ ہو جا ئیں اللہ پر توکل کرنے والے کے پائے ثبات متزلزل نہ ہوں گے کیونکہ ایسی بے نیازی نفس سے تعلق رکھتی ہے اور کسی بھی عالم میں نفس سے جدا نہیں ہو سکتی ہے ۔
مو لائے کائنات متقین کے صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :
(فی الزلازل وقور،وفی المکاره صبور )( ۱ )
''(متقین)مصائب وآلام میں با وقار اور دشواریوں میں صابر ہوتے ہیں''
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بے نیازی نفس کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے اور کو ئی بھی پریشانی یا سختی اس بے نیازی کو ان سے جدا نہیں کر سکتی اور یہ بے نیازی اللہ پر ایمان ،اعتماد ،توکل اور اس کی رضا پر راضی رہنے سے حاصل ہو تی ہے ۔در اصل بے نیازی یہی ہے اوراس سے بڑھکر کو ئی بے نیازی
۔____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۳۔
نہیں ہو سکتی ہے اور حالات کی تبدیلی اس پر اثر انداز نہیں ہو تی ہے ۔
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کاارشاد گرامی ہے :
(یا أباذراستغنِ بغنیٰ ﷲ تعالیٰ،یغنک ﷲ )( ۱ )
''ا ے ابوذراللہ کی بے نیازی کے ذریعہ مستغنی بنو اللہ (واقعاً)بے نیاز بنا دے گا ''
مولائے کائنات کا ارشاد ہے :
(الغنیٰ باللّٰه أعظم الغنیٰ،والغنیٰ بغیرﷲ أعظم الفقروالشقائ )( ۲ )
''اللہ کے ذریعہ استغناسب سے بڑا استغنا ہے اور اللہ کے بغیر استغنا سب سے بڑا فقر اور شقاوت ہے ''
اس معیار کے بموجب اللہ پر جتنا زیادہ توکل اور بھروسہ ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ مستغنی ہوگا
پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ارشاد گرا می ہے:
(مَن أحبّ أن یکون أغنیٰ الناس فلیکن بما فی ید اللّٰه أوثق منه مما فی یده )( ۳ )
''جو سب سے بڑا مستغنی ہو نا چا ہتا ہے اسے چاہئیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے ا س سے زیادہ اس پر بھروسہ کرے جو خدا کے پاس ہے ''
یہ بھی ملحوظ رہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب مادی اسباب کو نظر انداز کرنا نہیں ہے مادی اسباب کو نظر انداز کرنا سنت الٰہی سے انحراف ہے اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے ۔بلکہ توکل کا مطلب ہے غیر کے بجائے صرف اور صرف ذات پروردگار پر اعتماد و اعتبار کرنا ۔اگر یہ اعتماد ہے تو اپنے مقصود تک پہونچنے کے لئے کسی بھی طرح کے اسباب ووسائل اختیار کرنا توکل کے خلاف نہ ہوگا۔
____________________
(۱)مکارم الاخلاق ص ۵۳۳۔
(۲)غرر الحکم ج۱ ص۹۱۔۹۲۔
(۳)تحف العقول ص۲۶۔
بے نیازی(استغنا)کے ذرائع
جن چیزوں کے ذریعہ انسان بے نیازی حاصل کرسکتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم یہاں پر ان میں سے صرف اہم ترین عوامل کا تذکرہ کریں گے ۔
۱۔یقین:
ذات پروردگار پر یقین بے نیازی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اس لئے کہ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ خدا اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہے لطف و کرم کرتا ہے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اوریہ بھی یقین ہوکہ وہی رازق ہے رئووف ورحیم ہے ۔اسکی رحمت وعنایت کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والانہیں ہے اسکے خزانہ میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے اور کثرت عطا سے اسکے جود وکرم میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا ہے تو انسان کبھی بھی فقرواحتیاج کا احساس نہیں کرسکتا۔
فقرواحتیاج کا احساس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس ایسا یقین مفقود ہو اور ایمان، یقین کی منزل تک نہ پہونچاہو۔یقین ہی ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے بندوں کو ملنے والا سب سے بہترین رزق یقین ہے ۔
مولائے کائنات کا ارشاد گرامی ہے :
(مفتاح الغنیٰ الیقین )( ۱ )
''یقین بے نیازی کی کنجی ہے ''
امام محمد باقر کا ارشاد ہے :
(کفیٰ بالیقین غنیً،وبالعبادة شغلاً )( ۲ )
''بے نیازی کے لئے یقین کافی ہے اورعبادت بہترین مشغلہ ہے ''
____________________
(۱)بحارالانوار ج۷۸ ص۹۔
(۲)اصول کافی ج۲ص۸۵۔
۲۔تقویٰ:
بے نیازی کے اسباب وعوامل میں تقویٰ بھی اہم ترین عامل ہے ۔انسان جب احکام خداکا پابند ہوگا اور حدود الٰہیہ کا خیال رکھے گا تواللہ اس کے دل کو بے نیاز بنادے گا اور اس کے فقرواحتیاج کوختم کردے گا ۔
پیغمبر اکرم ْصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ارشاد گرامی ہے :
(کفیٰ بالتقیٰ غنیٰ )( ۱ )
''مستغنی ہونے کے لئے تقویٰ کافی ہے ''
امام محمد باقر نے فرمایا:
(یاجابر ان أهل التقویٰ هم الأغنیائ،أغناهم القلیل من الدنیا،فمؤنتهم یسیرة،ان نسیت الخیرذکّروک،وان عملت به أعانوک،أخّرواشهوا تهم و لذّا تهم خلفهم،وقدّموا طاعة ربّهم أمامهم )( ۲ )
''اے جابر صاحبان تقویٰ ہی مالدار ہیں ان میں بھی سب سے بڑا غنی وہ ہے دنیاجس کا میں تھوڑاحصہ ہو ان کے اسباب معیشت بہت مختصر ہوتے ہیں اگر تم عمل خیر کوبھول جائوتو یہ تمہیں یاد آوری کریں گے اگر تم عمل خیر کروگے تو تمہارے معاون ومددگار ہوںگے وہ اپنے خواہشات کو موخر اور لذتوں کو پس پشت رکھتے ہیں ان کے پیش نظر صرف اطاعت پروردگار ہوتی ہے اور وہ اسی کو مقدم رکھتے ہیں ''
ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق سے مروی ہے :
(من أخرجه ﷲ تعالیٰ من ذل المعاصی الیٰ عزّ التقویٰ،أغناه ﷲبلا مال،
____________________
(۱)تحف العقول ص۳۰۔
(۲) تحف العقول ص۲۰۸۔
وأعزّه بلا عشیرة،وآنسه بلا أنیس )( ۱ )
''خداجسے گناہوں کی ذلت سے نکال کر تقویٰ کی عزت سے سرافراز کرتاہے اسے بغیر مال کے غنی ،بغیر خاندان و قبیلہ کے عزیز اور ساتھیوں کے بغیر تسکین قلب اور انسیت عطا کردیتا ہے''
اس حدیث شریف میں نفس کی بے نیازی کے بعینہ وہی معنی پائے جائے ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں کہ نفس مال وثروت کے بغیر بھی غنی ہوسکتا ہے بغیر خاندان کے صاحب عزت بن سکتا ہے ہم نوا اور مونس کے بغیر بھی اپنی وحشتناک تنہائی کا مداوا کرسکتا ہے ۔اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بے نیازی کا منبع و سرچشمہ تقویٰ الٰہی ہے اسی تقوے کے ذریعہ نفس انسانی اپنے اندر عزت وانس کا احساس کرتا ہے اس لئے کہ جب انسان متقی اور حدود و احکام الٰہیہ کا پابند ہوگا تواللہ بھی اسکے نفس کو غنی بنادے گا اور اس سے فقروذلت اور وحشت کو دور رکھے گا۔
جس حدیث قدسی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں:
(لایؤثرهوای علیٰ هواه الاجعلت غناه فی نفسه )
''کوئی بندہ میری مرضی کو اپنی خواہشات پر ترجیح نہیں دے گا مگر یہ کہ میں اسکے نفس میں استغنا پیدا کردوںگا''
اور مخالفت نفس کا ہی نام تقویٰ ہے جس کا دوسرا نام اطاعت پروردگار ہے ۔
۳۔شعور :
یقین و تقویٰ اگر بے نیازی اور استغنا کی کنجی ہیں تو فہم و شعور یقین و تقویٰ کی کنجی اور ان تک پہونچنے کا راستہ ہے انسان فقط جہالت کے باعث ہی تقویٰ اور یقین سے محروم ہو سکتا ہے یہاں فہم و شعور سے ہماری مراد تدبر و تعقل ہے اسلامی روایات میں یہ معنی کثرت سے پائے جاتے ہیں ۔
____________________
(۱)وسائل الشیعہ ج۱۱ص۱۹۱۔
(۲)عدّةالداعی،ابن فھد حلی۔
امیر المو منین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(لاغنیٰ مثل العقل )( ۱ )
''عقل کے مانند کو ئی بے نیازی نہیں ہے ''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
(ان أغنیٰ الغنیٰ:العقل )( ۲ )
''سب سے بڑی بے نیازی عقل ہے ''
نیز آپ نے فرمایا ہے :
(غنیٰ العاقل بعلمه،وغنی الجاهل بماله )( ۳ )
''عاقل اپنے علم اور جا ہل اپنے مال کے ذریعہ مستغنی ہوتا ہے''
مشہور و معروف حدیث کے مطابق امام مو سیٰ کاظم نے اپنے صحابی ہشام بن حکم سے فرمایا :
(یاهشام:من أراد الغنیٰ بلا مال،وراحة القلب من الحسد،والسلامة فی الدین،فلیتضرّع الیٰ ﷲ فی مسألته بأن یکمل عقله )( ۴ )
''اے ہشام جو انسان مال کے بغیر بے نیازی کا خواہاں ہو،اپنے قلب کو حسد سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو ،دین کی سلامتی چاہتا ہو اس کو تضرع و زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا چاہئے کہ خداوند عالم اس کی عقل کو سالم کردے ''
____________________
(۱)تحف العقول ص۱۴۲۔
(۲)نہج البلاغہ حکمت ۳۸۔
(۳)غررالحکم ج۲ص۴۷۔
(۴)تحف العقول ص۲۸۶۔
حیات انسانی میں بے نیازی کے آثار
انسانی زندگی میں نفس کی بے نیازی کے بہت فائدے ہیں چونکہ پروردگار جس کے نفس کو بے نیازی عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے خدا سے رابطہ کا احساس کرتا ہے اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور ہر وقت تائید و عنایت الٰہی اس کے شامل حال ہے لہٰذا وہ تائید و عنایت الٰہی کے باعث سکون و اطمینان کی زندگی بسرکرتا ہے اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی کبھی مجھے میرے نفس کے حوالے کرے گا ۔
اس طرح اس کی زندگی میں مکمل اعتماد و اعتبار، اطمینان ،ثبات قدم اورسکون قلب تو نظر آتا ہے مگر کبھی بھی حرص و ہوس ،حسد ،لالچ اوراضطراب و پریشانی نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام نفسانی بیماریاں نفس کی کمزوری اور فقر سے پیدا ہوتی ہیںجس کی طرف ابھی ہم نے حضرت امام مو سیٰ کاظم کی حدیث کے ذیل میں اشارہ کیا تھا ۔
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :
(أغنیٰ الغنیٰ من لم یکن للحرص أسیراً )( ۱ )
''سب سے بڑا غنی وہ ہے جو حرص و ہوس کا اسیر نہ ہو ''
امیر المو منین حضر ت علی کا ارشاد ہے :
(أشرف الغنیٰ،ترک المنیٰ )( ۲ )
''شریف ترین بے نیازی ، خواہشات کا ترک کرناہے ''
آپ ہی کا ارشاد ہے :
____________________
(۱)اصول کافی ج۲ ص۳۱۶۔
(۲)اصول کافی ج۸ ص ۲۳۔
(الغنیٰ الاکبر:الیأس عمّافی أیدی الناس )( ۱ )
''سب سے بڑی بے نیازی یہ ہے کہ انسان اس کا امید وار نہ ہو جو لوگوں کے پاس ہے ''
اور جب مال نفس کو بے نیاز نہ بنا سکے تو پھر وہ اضطراب و بے چینی کا سبب بن جاتا ہے اور انسان کے حرص و طمع اور مشکلات میں اضافہ کرتا رہتا ہے ۔اس سلسلہ میں خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( انّمایریداللّٰه لیعذبهم بهافی الحیاة الدنیا وتزهق أنفسهم ) ( ۲ )
''پس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انھیں(اموال واولاد) کے ذریعہ ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر میں ہی ان کی جان نکلے ''
( انّما یرید اللّٰه أن یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق أنفسهم ) ......( ۳ )
''اور خداان کے(اموال واولاد) ذریعہ ان پر دنیا میں عذاب کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کفر کی حالت میں ان کا دم نکلے ''
۲۔ضمنت السمٰوات:
''زمین و آسمان اسکے رزق کے ضامن ہیں''
یہ جملہ ان لوگوںکی دوسری جزا ہے جو ﷲکے احکام کو اپنے خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں اور اپنے خواہشات کو حکم وارادئہ الٰہی کا تابع بنا لیتے ہیں۔ایسے لوگوں کو خدا جزا وانعام سے نواز تا ہے ان کی پہلی جزا تو یہ تھی کہ خدا ان کے نفس کو غنی بنادیتا ہے جس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کرچکے ہیں اور ان کی دوسری جزا اور انعام یہ ہے کہ آسمان وزمین ان کے رزق کے ضامن ہوتے ہیں۔
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت ۳۴۲۔
(۲)سورئہ توبہ آیت ۵۵۔
(۳)سورئہ توبہ آیت ۸۵۔
واضح سی بات ہے کہ اس جملہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان رزق حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ﷲاس کی سعی کو کامیاب بنادیتا ہے اور اسے توفیق عطا کرتا ہے۔
توفیق
ﷲنے توفیق کی بنا پر زمین وآسمان کو ضامن بنایا ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانی کوشش رائیگاںچلی جاتی ہے اور اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان برسوں ہاتھ پیر مارتا ہے جد وجہد کرتا ہے لیکن اپنے مقصود تک نہیں پہونچ پاتا اسکے برخلاف کبھی تھوڑی سی جدو جہد ہی نیک اور با برکت ثمرات کا سبب بن جاتی ہے یہ صرف حسن توفیق اور بے توفیقی کی بات ہے۔اور یہ طے ہے کہ خدا ہی توفیق دینے والا ہے۔
مومن اپنے خواہشات پراحکام خدا کو ترجیح دیتا ہے توخداوند عالم بطورجزازمین و آسمان کو اسکے رزق کا ضامن بنادیتا ہے ۔تو یہ بھی توفیق کی بنیاد پر ہے ۔یہاں توفیق کا مطلب یہ ہے کہ خداوندعالم اسکی سعی وکوشش کو مفید وکارآمد جگہ پر لگادیتا ہے جس سے یہ سعی وکوشش نتیجہ خیزبن جاتی ہے بالکل اسی طرح جیسے زرخیززمین پر بارش ہوتی ہے البتہ کبھی بارش ہوتی ہے مگر زمین سے دانہ نہیں اگتاہے اور بارش کا پانی ضائع ہوجاتا ہے لیکن اگر زرخیز زمین پر تھوڑی سی بارش مناسب موقع پر ہوجائے تو خیر کثیر کا باعث بن جاتی ہے اور سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ توفیق ایک الگ چیز ہے اسکا انسان کی کوشش اور جد وجہد سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان جدوجہد کرسکتا ہے مگر توفیق اسکے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ تھوڑے اسباب توفیق انسان کے ہاتھ میں ہیں لیکن جو اسباب توفیق اسکے اختیار میں نہیں ہیں انکی تعداد کئی گنا زیادہ ہے جو سب کے سب خداکے ہاتھ میں ہیں ۔خدا جب کسی بندہ کو توفیق سے نوازتا ہے تو اسکی زندگی اور جدوجہد بابرکت بن جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید نے جناب عیسیٰ کی ز بانی نقل کیا ہے:
( وجعلنی مبارکاً أینماکنت ) ( ۱ )
''اور مجھے مبارک قرار دیا ہے چاہے میں جہاں رہوں ''
جب تک ﷲ کسی بندہ کو توفیق کرامت نہ فرمائے یا اسکے لئے بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو بندہ
اپنی جدوجہد اور عقل کے ذریعہ تھوڑے سے اسباب خیر ہی حاصل کرسکتا ہے۔
( لاینفع اجتهاد بغیرتوفیق ) ( ۲ )
''کوئی بھی کوشش توفیق کے بغیر مفید نہیں ہوتی ''
اورجب پروردگار عالم کسی بندہ کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو توفیق مرحمت کرتا ہے اور اسکی سعی و کوشش کو فلاح و کامیابی کے راستہ پر لگادیتا ہے جس سے اسکی سعی وکوشش نتیجہ بخش ہوجاتی ہے۔
حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے:
(خیرالاجتهاد ما قارنه التوفیق )( ۳ )
''بہترین کوشش وہ ہے جو توفیق کے ساتھ ہو''
دوسری حدیث میں وارد ہو ا ہے:
(التوفیق أشرف الحظّین )( ۴ )
''توفیق دواشر ف واعلی حصو ںمیں سے ایک ہے''
اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ ایسے اسباب خیروسعادت ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی عقل اور جدوجہد کے سہارے حاصل کرتا ہے یا وہ وسائل و ذرائع ہوتے ہیں جوﷲ نے اسے عطا
____________________
(۱)سورئہ مریم آیت ۳۱۔
(۲)غررالحکم ج۲ ص۳۴۵۔
(۳)غررالحکم ج۲ص۳۵۱۔
(۴)غررالحکم ج۱ص۸۲۔
کئے ہیں یہ بھی نتیجہ تک پہونچنے میں شریک ہیں مگر ان کا حصہ اور ان کی منزلت کم ہے۔دوسرا جز اور حصہ خیروبرکت کے وہ غیبی اسباب ہیں جنہیں ﷲ اپنے بندہ کے شامل حال کرتا ہے یا جب بندہ کو اس کی سعی وکوشش سے اسباب خیر میسر نہیں ہوتے تواللہ اسے خیر و سعادت کی راہ پر لگادیتا ہے یہ دوسرا حصہ ہے جو حدیث کے مطابق زیادہ مخفی ہوتا ہے۔
بلا شبہ توفیق جوایک غیبی سبب ہے اور انسان کو خیروبرکت کی راہ دکھاتا ہے ۔انسان کے پاس
موجود دیگر عقلی اور فطری امکانات اور قوتوںسے جدا ایک چیز ہے اگر چہ یہ قوتیں اورصلاحتیں بھی عطائے پروردگار ہیں لیکن تنہا یہ صلاحتیں انسان کو خیروسعادت کی منزل تک پہونچانے کے لائق نہیں ہیں یعنی صرف انھیں کے سہارے انسان شر سے محفوظ نہیںرہ سکتا ہے بلکہ پروردگار جب کسی بندہ کے لئے خیرکا ارادہ کرتا ہے تو اسکی سعی وکوشش اور صلاحیتوں کو خیر کے صحیح راستوں پر بروئے کار لانے میں اسکی مدد کرتا ہے۔مندرجہ ذیل حدیث اس حقیقت کی صاف وضاحت کرتی ہے۔
روایت میں ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے سوال کیا:
(یا بن رسول ﷲ! ألست أنا مستطیعاً لماکُلِّفْتُ؟فقال له عليهالسلام :(ما الاستطاعة عندک؟) قال:القوةعلیٰ العمل،قال له عليهالسلام :(قد اُعطیت القوة،ان اُعطیت(المعونة)،قال له الرجل:فما المعونة ؟ قال عليهالسلام :(التوفیق)،قال(الرجل):فلم اِعطائُ التوفیق؟ قال(الامام) عليهالسلام : هل تستطیع بتلک القوةدفع الضررعن نفسک،وأخذالنفع الیهابغیرالعون من ﷲ تبارک وتعالیٰ؟)قال:لا، قال عليهالسلام :(فَلمَ تنتحل مالا تقدرعلیه؟)ثم قال:(أین أنت من قول العبد الصالح:(وما توفیقی الا بﷲ) ( ۱ )
____________________
(۱)بحار الانوارج۵ ص۴۲۔''وماتوفیقی الابﷲعلیه توکّلت والیه اُنیب'' ''میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسکی طرف میں توجہ کر رہاہوں''سورئہ ہو دآیت۸۸۔
''فرزند رسول ﷲ !جب مجھے مکلف بنایاگیا ہے تو کیا میں مستطیع نہیں ہوں؟امام نے فرمایا:استطاعت سے تمہاری مراد کیاہے؟اس نے جواب دیا کہ عمل بجالانے کی قوت وطاقت''امام نے فرمایا:یہ درست ہے کہ تمہیں قوت دی گئی ہے مگر کیا تمہیں''معونہ''بھی نصیب ہوا ہے؟اس شخص نے سوال کیا:یہ معونہ کیاہے؟امام نے فرمایا:توفیق! اس شخص نے(تعجب سے)پوچھا:توفیق عطا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟امام نے فرمایا کہ:کیا تم اللہ کی مددکے بغیر صرف اپنی قوت کے ذریعہ اپنے کو نقصانات سے محفوظ ر کھ سکتے ہو اور فائدے حاصل کرسکتے ہو؟اس نے جواب دیا ہرگز نہیں:پھر امام نے دریافت فرمایا:پھرتم عبدصالح کے اس جملہ کا کیا مطلب سمجھتے ہوکہ' 'میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے ''
اس روایت کے مطابق انسانی زندگی میں تین طرح کی قوتیں اور عوامل کار فرما ہیں:
۱۔وہ طبیعی اور سماجی قوانین جو انسان کو خیریا شرکی جانب لے جاتے ہیں۔
۲۔وہ قوتیں اور صلاحتیں جو پروردگار عالم نے انسانی وجود میں رکھی ہیں اور جنہیں انسان طبیعت یا سماج میں خیروشر تک رسائی حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔
۳۔توفیق و امداد الٰہی جس کے ذریعہ پروردگار اپنے بندوں کو اسباب خیر تک پہونچاتا ہے اور ان مخفی اسباب کے لئے بندوں کی مدد کرتا ہے جو عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے یا جن تک رسائی ممکن نہ تھی اس آخری سبب کے بغیر خیر تک پہونچنا ممکن نہیں ہے۔
کراجکی نے اپنی کتاب'' کنز ''میں روایت کی ہے کہ امام جعفر صاد ق نے فرمایا:
(ماکلّ من نویٰ شیئاً قدرعلیه،وما کل من قدر علیٰ شیٔ وُفّق له ۔۔۔)( ۱ )
''ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان ہر اس چیز پر قدرت بھی رکھتا ہو جس کی اس نے نیت کی ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ جو مقدور ہو اسکی توفیق بھی حاصل ہواور نہ ہی ایسا ہے کہ جسکی توفیق حاصل ہو وہ شئے خود
____________________
(۱)بحارالانوار ج۵ص۲۰۹۔۲۱۰۔
حاصل بھی ہوجائے۔جب نیت ، قدرت اورتوفیق کے ساتھ وہ چیزبھی حاصل ہوجائے تو سعادت مکمل کہلاتی ہے''
توفیق ،معرفت پروردگار کا بہت وسیع باب ہے اگر چہ ﷲ کی معرفت کے تین راستے ہیں:
۱۔فطرت
۲۔عقل (عقلی دلیلوںکے ذریعہ)
۳۔تعامل مع اللہ(اللہ کے ساتھ تجارت اور معاملہ)
''تعامل مع ﷲ'' معرفت کاایک وسیع در وازہ ہے لیکن اس دروازہ میں صرف صاحبان بصیرت داخل ہوسکتے ہیں اوراسکے ذریعہ انسان کو ایمان، اعتبارواطمینان اور توکل کاوہ درجہ حاصل ہوتا ہے جو فطرت اورعقل کے ذریعہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم کے ساتھ معاملہ اور اس کی عطا کے ساتھ لین دین اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی معیت کی وجہ سے ہی تائید خداوندی اوراس کی تو فیق ہر حال میں انسان کے شامل حال ہو تی ہے ۔
توفیق الٰہی یونہی کسی انسان کے شامل حال نہیں ہوجاتی بلکہ توفیق نازل ہونے کے اپنے اسباب و قوانین اور اصول ہیں۔ جسے پروردگار نے توفیق جیسی نعمت عطا کی ہے یقینا وہ اس لائق تھا کہ ایسی رحمت الٰہی اس کو نصیب ہو اور جو توفیق سے محروم ہے یقینا اس نے اس عظیم نعمت کے نزول و حصول کے مواقع ضرورگنوائے ہیں ورنہ رحمت الٰہی میں بخل و کنجو سی کا دخل نہیں ہے اور نہ ہی اسکا خزانہ ٔ رحمت ختم ہونے والا ہے ۔یہ عظیم نعمت اسی کے حصہ میں آتی ہے جس کے شامل حال خدا کی توفیق ہوتی ہے اور اس نعمت سے محروم صرف وہی ہوتا ہے کہ جسے توفیق نصیب نہ ہو۔ توفیق جیسی نعمت پانے والے افراد بھی برابر نہیں ہوتے بلکہ استحقاق، صلاحیت ،لیاقت اور ظرف کے اعتبار سے ان کی توفیق کے مراتب ودرجات بھی الگ الگ ہوتے ہیں ۔
اسکی بارگاہ سے رحمت،توفیق کی شکل میں بے حساب نازل ہوتی رہتی ہے البتہ اس سے صرف وہی لوگ محروم رہتے ہیں جن کا نفس بد اعمالیوں کے باعث گھاٹے میں ہے اور جنھوںنے اپنے آپ کو اوراپنے باطن اور ظرف کواسکے حصول کے قابل نہیں بنا یاہے جبکہ ان کے برخلاف صاحبان ایمان اپنی استعداد اورظرف کے مطابق اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے رہتے ہیں۔( ۱ )
رزق اگر چہ عالم ظاہر و شہودکا معاملہ ہے لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسئلہ رزق سے غیبی اسباب کا کتنا گہرا تعلق ہے ۔
عالم غیب اور عالم شہود(ظاہر)کے درمیان رابطہ
مسئلہ''غیب''اور''غیب وشہود کا تعلق''جیسے مسائل اسلامی نظریات کے بنیادی مسائل میں شمار ہوتے ہیںاور اس سلسلہ میں لوگوں کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو سرے سے غیب کے منکر ہیں کچھ شہود کے مقابل غیب کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان رابطہ کے منکر ہیں۔
اسلام''غیب''کو صرف تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ''غیب''پر ایمان کی دعوت دیتا ہے اور ''ایمان بالغیب''کو اسلام کی سب سے پہلی شرط قرار دیتا ہے۔
( الم ٭ذٰلک الکتاب لاریب فیه هدیً للمتقین٭الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون ) ( ۲ )
''یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ صاحبان تقویٰ اور پرہیزگارلوگوں کیلئے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ
____________________
(۱)مؤلف کی کتاب ''المذہب التاریخی فی القرآن الکریم ، سے اقتباس ،معمولی تبدیلی کے ساتھ صفحہ ۴۰۔۴۹۔
(۲)سورئہ بقرہ آیت ۱۔۳۔
نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں ''
( الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون ) ( ۱ )
''جو از غیب اپنے پروردگار سے ڈر نے والے ہیں اور قیامت کے خوف سے لرزاں ہیں''
( انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمٰن بالغیب ) ( ۲ )
''آپ صرف ان لوگوں کو ڈر ا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے ازغیب خدا سے ڈر تے رہیں ''
اسلام عالم غیب اور عالم شہود کے درمیان ربط کا بھی قائل ہے اس کا یہ نظریہ ہے کہ ان دونوں وسیع افقوں کوجوڑنے والے بہت سے پل بھی پائے جاتے ہیں ان تمام باتوں سے بڑھکر اسلام کا عقیدہ ہے کہ دونوں عالم ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں یعنی عالم غیب ،عالم ظاہر و محسوس پر اثر انداز ہوتا ہے اور عالم محسوس و ظاہر غیب پر ،اگر انسان متقی وپرہیزگار ہے۔ایمان بالغیب کے باعث دل میں خشیت الٰہی پائی جاتی ہے اور وہ گناہوں سے کنارہ کش رہتا ہے تو یہ چیزیں براہ راست انسان کی مادی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔معاش حیات کی سختیاں آسانیوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں اور رزق کے دروازے اسکے لئے کھل جاتے ہیں۔ارشاد پروردگار ہے:
( ومن یتّق اللّٰه یجعل له مخرجاً٭ویرزقه من حیث لا یحتسب ) ( ۳ )
''اور جو بھی ﷲ سے ڈرتا ہے ﷲ اسکے لئے نجات کی راہ پیدا کردیتا ہے ،اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جسکا وہ گمان بھی نہیں کرتا ہے ''
____________________
(۱)سورئہ انبیاء آیت۴۹ ۔
(۲)سور ئہ یٰس آیت۱۱۔
(۳)سورئہ طلاق آیت ۲۔۳۔
( ومن یتّق اللّٰه یجعل له من أمره یسرا ) ( ۱ )
اور جو ﷲ سے ڈرتا ہے ﷲ اسکے امرمیں آسانی پیدا کردیتا ہے ''
یہ تو تھا عالم ظاہر و محسوس کا عالم غیب سے تعلق۔ اسکے برخلاف عالم غیب کا بھی عالم ظاہر سے
تعلق پایا جاتا ہے۔
پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم سے مروی ہے:
(لولا الخبزماصلّینا )( ۲ )
''اگر روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم نماز نہ پڑھتے''
آپ ہی سے منقول ہے:(وبہ (الخبز)صمتم)( ۳ )
''تم لوگوں کے روزے اسی روٹی کیلئے ہیں''
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:
(فلولاالخبزماصلّیناولاصمنا،ولا أدّینافرائض ربناعزّوجلّ )( ۴ )
''اگر روٹی (کی بات) نہ ہوتی تو نہ ہم نماز پڑھتے اور نہ روزہ رکھتے اور نہ ہی اپنے پروردگار کے احکام بجالاتے''
____________________
(۱)سورئہ طلاق آیت۴۔
(۲)اصول کافی ج۵ص۷۳۔
(۳)اصول کافی ج۶ ص۳۰۳۔
(۴)اصول کافی ج۵ص۷۳۔
حرکت تاریخ کے سلسلہ میں غیبی عامل کا کردار
عالم غیب اور عالم محسوس میں اسی رابطہ کی بنا پر قرآن کریم ''غیب''کو حرکت تاریخ کا اہم سبب شمار کرتا ہے اور تاریخ کے پیچھے مادی سبب کو بھی تسلیم نہیں کرتا چہ جائیکہ مادیت کو تاریخ کا تنہا محرک مانا جائے بلکہ بسا اوقات ایسا بھی دکھائی دیتا ہے کہ تاریخ مادی عوامل کے تقاضوں کے برخلاف حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔
ذرا قرآن کریم کی ان آیات میں غور وخوض کیجئے:
( لقدنصرکم ﷲ فی مواطن کثیرة ویوم حنینٍ اذ أعجبتکم کثرتکم فلم تغنِ عنکم شیئاً وضاقت علیکم الارض بمارحبت ثم ولّیتم مدبرین٭ثم أنزل ﷲ سکینته علیٰ المؤمنین وأنزل جنوداً لم تروها وعذّب الذین کفروا وذٰلک جزاء الکافرین ) ( ۱ )
''بیشک اللہ نے اکثر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا لیکن اس(کثرت) نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہونچایا اور تمہارے لئے زمین اپنی وسعتوں سمیت تنگ ہوگئی اور اسکے بعد تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے ،پھر اسکے بعد اللہ نے اپنے رسول اور صاحبان ایمان پر سکون نازل کیا اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھااور کفر اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کیاکہ یہی کافرین کی جزا اور ان کا انجام ہے''
ان آیات کریمہ سے پہلا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ فتح و کامرانی عطا کرنے والا خدا ہے۔
مادی اسباب و وسائل صرف ذریعہ ہیں کامیابی دینے والا اصل میں خدا ہے۔ تاریخ کی حرکت کو سمجھنے کے لئے بنیادی نقطہ یہی ہے اور یہیں سے اسلامی نظریہ،مادیت کے نظریہ سے جدا ہوجاتا ہے۔
آیات کریمہ میں دوسرا اہم تذکرہ لشکر اسلام کی کثرت کے باوجود حنین کی جنگ کا نقشہ منقلب ہونا ہے حالانکہ مادی نگاہ رکھنے والوں کے نزدیک افرادکی کثرت فتح کا سبب ہوتی ہے۔ ''اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہونچایااور
____________________
(۱)سورئہ توبہ آیت۲۵۔۲۶۔
تمہارے لئے زمین اپنی وسعتوںسمیت تنگ ہوگئی اور اسکے بعدتم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔
آیات کریمہ میں تیسرا تذکرہ ﷲ کی جانب سے اپنے رسول اور مومنین پرعین میدان جنگ میں سکینہ نازل ہونا ہے۔اسی سکینہ کے باعث شدت کے لمحات میں انہیں اطمینان و سکون حاصل ہوا
اور وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہ سکے اور ان کے دلوں سے خوف واضطراب زائل ہوایہ سکینہ فقط خدا کی جانب سے تھا ﷲ نے فرشتوں کا نہ دکھائی دینے والالشکر نازل کیا جو لشکر کفار کو ہزیمت پر مجبور کر رہا تھا ان کی صفوں میں رعب پھیلا رہا تھا اسکے بر خلاف دشمن سے مقابلہ کے لئے مومنین کے دلوں کو تقویت عطا کررہا تھا۔
اب ہم سورئہ آل عمران کی ان آیات کو پڑھیں:
( بلیٰ ان تصبروا وتتّقوا ویأ توکم من فورهم هذا یُمددکم ربّکم بخمسة آلاف من الملا ئکةمسوّمین٭ وما جعله ﷲ الابشریٰ لکم ولتطمئنّ قلوبکم به وما النصرالا من عندﷲ العزیزالحکیم ) ( ۱ )
'' یقینا اگر تم صبر کروگے اور تقویٰ اختیار کروگے اور دشمن فی الفورتم تک آجائیں تو خدا پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مددکریگا جن پر بہادری کے نشان لگے ہوںگے ۔اور اس امداد کو خدانے صرف تمہارے لئے بشارت اور اطمینان قلب کا سامان قرار دیا ہے ورنہ مدد تو صرف خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے ہوتی ہے ''
جنگ کی شدت اور سختیوں کے دوران پانچ ہزار ملائکہ کے ذریعہ غیبی امداد نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کرادیا۔ﷲ نے ملائکہ کے ذریعہ مومنین کے دلو ں کو سکون واطمینان عطا کیا اور اس طرح سخت ترین لمحات میں انہیں اسطرح بشارت وخوش خبری سے نواز ا۔ اسی آیہ شریفہ میں اس
____________________
(۱)سورئہ آل عمران آیت۱۲۵۔۱۲۶۔
بنیادی نقطہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو نقطہ تاریخ کی حرکت کے بارے میں اسلام اور مادیت کے درمیان حدفاصل ہے( وماالنصرالا من عندﷲ العزیزالحکیم ) فتح وکامرانی صرف اور صرف ﷲ کی جانب سے ہے جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ پلٹ جانے کے بعد مومنین کو سکھائے گئے
اسباق سورئہ آل عمران میں موجود ہیں:
( ولا تهنواولا تحزنواوأنتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ) ( ۱ )
''خبر دار سستی نہ کرنا مصائب پر محزون نہ ہونا،اگر تم صاحب ایمان ہوتو سربلندی تمہارے ہی لئے ہے ''
میدان جنگ میں یہ برتری خدا پر ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ایمان کے بعد پھر کہیں ان مادی اسباب و عوامل کی باری آتی ہے جنکی ضرورت میدان جنگ میں پڑتی ہے۔
سورئہ اعراف میں بھی یہی مضمون نظر آتا ہے:
( ولوأنّ أهل القریٰ آمنوا وا تّقوا لفتحنا علیهم برکاتٍ من السماء والارض ولکن کذّبوا فأخذناهم بماکانوا یکسبون ) ( ۲ )
''اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرلیتے تو ہم ان کے لئے زمین وآسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انھوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔''
''پروردگار عالم اپنے بندوں پر زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیتا ہے'' یہ چیز ایمان وتقوے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔اسکے ساتھ ضمنی طورپرمادی و سائل بھی درکار ہوتے ہیں۔
یہ تصویر کا ایک رخ تھا جو کہ مثبت رخ تھا کہ کس طرح میدان جنگ میں ایمان اور تقوی ٰسے
____________________
(۱)سورئہ آل عمران آیت۱۳۹۔
(۲)سورئہ اعراف آیت۹۶۔
فتح و کامرانی ملتی ہے معاشی زندگی میں وسعت رزق ،آسانیاں اور خوشیاں میسر ہوتی ہیں۔ اسکے برخلاف عالم غیب اور عالم محسوس کا یہی تعلق اور رابطہ غلطیوں اورگناہوںمیں مبتلاہونے اور حدود الٰہی سے تجاوز ،تہذیبوں کے خاتمہ اور امتوں کی تباہی و بربادی کا سبب بھی ہوتا ہے۔
سورئہ انعام کی ان آیات کو غور سے پڑھئے:
( ألم یرواکم أهلکنامن قبلهم من قَرنٍ مکنّاهم فی الارض مالم نمکّن لکم وأرسلنا السماء علیهم مدراراً وجعلنا الانهارتجری من تحتهم فأهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرین ) ( ۱ )
''کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کردیا ہے جنہیں تم سے زیادہ زمین میں اقتدار دیا تھا اور ان پر موسلادھار پانی بھی برسایا تھا ان کے قدموں میں نہر یں بھی جاری تھیں پھر ان کے گناہوں کی بناپر انہیں ہلاک کردیا اور ان کے بعد دوسری نسل جاری کردی ''
یہ ہلاکت و بربادی بے عملی، عصیان اور گناہوں کی وجہ سے تھی مادیت کو تاریخ کا محرک سمجھنے والوں کی نگاہ میں ان اسباب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جبکہ قرآن بد اعمالیوں کو بھی بربادی کا سبب مانتا ہے ۔
اسی سورئہ مبارکہ کی یہ آیات کریمہ بھی ملاحظہ فرمائیں جن میں قرآن مجید نے تسلسل کو مکمل طور پر پیش کردیا ہے ۔جیسا کہ ارشاد ہے :
( ولقد ارسلنالیٰ امم منقبلک فاخذناهم بالبأسآء والضرّآء لعلهم یتضرعون٭ فلولااذجاء هم بأسنا تضرّعوا ولکن قست قلوبهم و زیّن لهم الشیطان ماکانوا یعملون٭فلمانسوا ما ذکّروا به فتحناعلیهم أبواب کل شیٔ حتّٰی اذا فرحوابما اُوتوا أخذنٰهم بغتة ً فاذا هم مبلسون٭فقطع )
____________________
(۱)سورئہ انعام آیت۶۔
( دابرالقوم الذین ظلموا والحمد ﷲ ربّ العالمین ) ( ۱ )
''ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں اسکے بعد انہیں سختی اور تکلیف
میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑگڑائیں۔پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی ؟بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہوگئے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لئے آراستہ کردیا ہے ۔پھر جب وہ ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں تو ہم نے امتحان کے طورپر ان کے لئے ہر چیز کے دروازے کھول دئے ،یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہوگئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ،اور وہ مایوس ہوکر رہ گئے، پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کردیاگیا اور ساری تعریف اس ﷲکے لئے ہے جو رب العالمین ہے ''
تمام امتوں کے آغاز سے لیکر ان کے انجام تک تین مرحلے ہیں جن کی طرف ان آیات کریمہ میںاشارہ پایا جاتا ہے اسی طرح ان تینوں مرحلوں میں عالم غیب اور عالم محسوس کے درمیان رابطہ کی وضاحت پائی جاتی ہے۔
پہلا مرحلہ
یہ آزمائش کا مرحلہ ہے اس مرحلہ میں پروردگار امتوں کو نعمتوں اور صلاحتیوں سے نواز تا ہے۔اس مرحلہ میں گناہ و معصیت نزول بلا اور بارگاہ خداوندی میں تضرع وزاری بلائوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔
( فأخذناهم بالبأساء والضرّاء لعلّهم یتضرّعون )
''اسکے بعد ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلاکیا کہ شاید ہم سے گڑگڑائیں''
گناہ سے بلائووں کانازل ہونا اور تضرع وزاری سے بلائووں کا برطرف ہونا یہ در اصل عالم
____________________
(۱)سورئہ انعام آیت۴۲۔۴۵۔
غیب اور عالم محسوس کے رابطہ کو بیان کرتا ہے اوراس نقطہ تک مادی فکرکی رسائی نہیں ہوسکتی ہے یہ بات ہمیںکتاب خدا سے معلوم ہوئی ہے۔
دوسرا مرحلہ
مہلت اور چھوٹ کا مرحلہ ہے ۔اس مرحلہ میں بھی عالم غیب و محسوس کا تعلق نمایاں ہے اس لئے کہ برائیوں اور گناہوں میں غرق ہوجانے اور آزمائش کے مرحلہ میں مصائب و مشکلات کو نظر انداز کرتے رہنے کے باوجود کبھی کبھی امت پر نعمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا لیکن اس مرحلہ میں رزق،نعمت نہیںبلکہ عذاب ہوتا ہے اور ﷲ اس طرح انہیں ان کی سرکشی میں چھوٹ دیکر ان کی رسی درازکردیتا ہے تاکہ پھراچانک ایک دم پوری سختی وقوت کے ساتھ انہیں جکڑلے:
( فلما نسواماذکّروا به فتحنا علیهم أبواب کلّ شیٔ ) ( ۱ )
''پھر جب وہ ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں تو ہم نے امتحان کے طورپر ان کے لئے ہرچیز کے دروازے کھول دئے ''
تیسرا مرحلہ
بربادی اور نابودی کا مرحلہ ہے:
( فقطع دابرالقوم الذین ظلموا والحمد ﷲ ربّ العالمین ) ( ۲ )
''پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کردیا گیا اور ساری تعریف اس ﷲکے لئے ہے جو رب العالمین ہے ''
حمد خدا یہاں عذاب پر ہے نعمت پرنہیں۔ یعنی نعمت حیات کے بجائے ''سرکش افراد کی '' نابودی اورہلاکت پر حمد وثنا ئے الٰہی کی جارہی ہے ۔
____________________
(۱)سورئہ انعام آیت ۴۴۔
(۲)سورئہ انعام آیت۴۵۔
عالم غیب ومحسوس کا رابطہ اس مرحلہ میں بھی گذشتہ مراحل سے جدا نہیں ہے کیونکہ جب افراد قوم اکڑتے ہیں روئے زمین پر سرکشی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان چیزوں میں فرحت محسوس کرتے ہیں تو ان پر ایسا عذاب نازل ہوتا ہے کہ پوری قوم نیست ونابود ہوجاتی ہے۔
لہٰذامعلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں غیبی عامل ،حرکت تاریخ کا اہم عنصر ہے۔
غیبی عامل،مادی عوامل کا منکر نہیں
اگر چہ اسلام کی نگاہ میں حرکت تاریخ کا اہم عنصر غیبی عامل ہے مگراسکا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے
کہ اسلام انسانی زندگی میں مادی عوامل کو تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ در حقیقت حرکت تاریخ کا عامل، کسی ایک چیز کو ماننے کے بجائے اسلام متعدداور مشترکہ عوامل کا قائل ہے یعنی غیبی اور مادی عوامل ایک ساتھ مل کر تاریخ کو آگے بڑھاتے ہیں ۔اور ان میں سے صرف کوئی ایک عامل تاریخ کا محرک نہیں ہے وہ مادی عامل ہو یا معنوی۔ اسلام کی نگاہ میںزندگی بسر کرنے کے لئے ان دونوں عوامل کوبروئے کار لانا ضروری ہے۔
تقویٰ اور رزق کا تعلق
جب عالم غیب اور عالم محسوس کا تعلق اور ربط واضح ہوگیا ''تو آیئے ایک نگاہ ،حدیث قدسی کے اس فقرہ پر ڈالتے ہیں:
(لا یؤثرعبد هوای علی هواه الاضمنت السمٰوات والارض رزقه )
''کوئی بندہ اگر اپنی خواہشات پرمیرے احکام اورمرضی کو ترجیح دے گا تو میں زمین وآسمان کو اسکے رزق کا ضامن بنادوں گا'' عالم غیب و عالم محسوس کے درمیان تعلق کی گذشتہ توضیح کے پیش نظر غیب اور معنویت سے تعلق رکھنے والے ''تقویٰ''اور عالم غیب وعالم محسوس وشہود سے تعلق رکھنے والے ''رزق' ' کے درمیان ربط کی وضاحت کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی ۔
اسلامی تہذیب میں یہ نظریہ بالکل واضح وروشن ہے اس لئے کہ تقویٰ بھی رحمت الٰہی کا وسیع دروازہ ہے تقوے کے ذریعہ انسان ﷲ سے رزق نازل کراسکتا ہے ۔تقوے سے ہی باران رحمت نازل ہوتی ہے اور مشکلات بر طرف ہوتی ہیں تقوے کے سہارے ہی ﷲ کی جانب سے فتح وکامیابی میسر ہوتی ہے۔اسی کے طفیل بند دروازے کھل جاتے ہیں تقوے کی ہی بدولت خداوند عالم زندگی کے مشکلات میں لوگوں کے لئے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔جیسا کہ ارشادالٰہی ہے :
( ومن یتّق ﷲ یجعلْ له مخرجاً٭ویرزقه من حیث لایحتسب ومن یتوکّل علی ﷲ فهوحسبه انّ ﷲ بالغ أمره قد جعل ﷲ لکلّ شی ء قدْرا )
''اور جو بھی ﷲسے ڈرتا ہے ﷲاس کے لئے نجات کی راہ پیدا کردیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے اور جو خدا پر بھروسہ کریگا خدا اسکے لئے کافی ہے بیشک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا ہے اس نے ہر شے کے لئے ایک مقدار معین کردی ہے ۔ ''( ۱ )
جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے :
( ومن یتّق ﷲ یجعل له من أمره یُسراً ) ( ۲ )
''اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اسکے معاملات میں آسانی پیدا کردیتا ہے''
پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ارشاد گرامی ہے:
( لوأن السمٰوات والارض کانتا رتقاً علیٰ عبد ثم اتقیٰ ﷲ لجعل ﷲله منهما فرجاً ومخرجاً ) ( ۳ )
''اگر کسی بندے پر زمین وآسمان کے دروازے بالکل بند ہوجائیں پھر وہ تقوائے الٰہی اختیار کرے تو ﷲ اسکو زمین وآسمان میں کشادگی اور آسانیاں عطا کردے گا ''
____________________
(۱)سورئہ طلاق آیت۲۔۳۔
(۲)سورئہ طلاق آیت ۴۔
(۳)بحارالانوار ج۷۰ص ۲۸۵۔
روایت کے مطابق جب حضرت ابوذر(رح) ربذہ کے لئے جلا وطن کئے گئے توان سے امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا:
(یاأباذر؛انک غضبت ﷲ فارجُ من غضبت له،ولوأن السمٰوات والارض کانتاعلیٰ عبد رتقاً ثم اتقیٰ ﷲلجعل منهمافرجاًومخرجاً )( ۱ )
''اے ابوذر تمہاری ناراضگی اور غضب ﷲ کے لئے تھا لہٰذا اسی کی ذات سے لولگائے رکھنا۔اگر زمین وآسمان کے راستے کسی بندہ پر بند ہوجائیں اور وہ تقوائے الٰہی اختیار کرے تو ﷲ اسکے لئے زمین وآسمان میں آسانیاں فراہم کردے گا ''
مولائے کائنات حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے:
(من أخذ بالتقویٰ عزبت(غابت)عنه الشدائد بعد دنوّها،واحلولت له الاموربعد مرارتها،وانفرجت عنه الامواج بعد تراکمها،وأسهلت له الصعا ب بعد انصابها )( ۲ )
''جوتقویٰ اختیار کرے گا شدائد و مصائب اس سے نزدیک ہونے کے بعد دور ہو جائیں گے تلخیوں کے بعد حلاوت محسوس کرے گا۔ امواج بلا اسکے گرد جمع ہونے کے بعد پراکندہ ہوجائیں گی مشکلات پڑنے کے بعد آسانیوں میں تبدیل ہوجائیں گی ''
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے:
(من اعتصم بﷲ بتقواه عصمه ﷲ،ومن أقبل ﷲ علیه وعصمه لم یبال لوسقطت السماء علیٰ الارض،وان نزلت نازلة علیٰ أهل الارض فتشملهم بلیة،کان فی حرزﷲ بالتقویٰ من کل بلیة،ألیس ﷲ تعالیٰ یقول:ان المتقین فی مقام أمین )
____________________
(۱)نہج البلاغہ خطبہ۱۳۰۔
(۲)نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۸۔
''جو تقوائے الٰہی کی پناہ میں آئے گا ﷲ اسے محفوظ رکھے گا اور جس کی طرف ﷲ کی توجہ ہوجائے اور ﷲ اسے محفوظ رکھے توچاہے آسمان، زمین پر گرجائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اگر تمام اہل زمین پرکوئی بلا نازل ہوتو وہ تقوے کے باعث امان خدا میں رہے گا ۔کیا خدا کایہ قول نہیں ہے:
(ان المتقین فی مقام أمین )( ۱ )
''بیشک متقین امن کے مقام پر ہیں''
امام جعفرصادق سے مروی ہے کہ:
(ان ﷲ قد ضمن لمن اتّقاه أن یحوّله عمایکره الیٰ مایحب ویرزقه من حیث لایحتسب )( ۲ )
''ﷲ نے متقی کی ضمانت لی ہے کہ اسکے ناپسند یدہ امور کو پسندیدہ امور میںتبدیل کردے گا اور اسے ایسے راستہ سے رزق عطا کرے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا''
امام محمد تقی نے سعد الخیرکو تحریر فرمایا:
(ان ﷲ عزّوجل یقی بالتقویٰ عن العبد ماغرب عنه عقله،ویجلّی بالتقویٰ عماه وجهله،وبالتقویٰ نُجّی نوح ومن معه فی السفینة،وصالح ومن معه من الصاعقة،وبالتقویٰ فازالصابرون ونجت تلک العصب من المهالک )( ۳ )
''پروردگار عالم، تقویٰ کے ذریعہ اپنے بندہ سے ان چیزوں کومحفوظ رکھتا ہے جو اسکی عقل سے مخفی تھیں اور تقویٰ کے ذریعہ اسے مکمل بینائی عطا کردیتا ہے اور ان چیزوں کو بھی دکھادیتا ہے جو جہالت کے باعث اس سے پوشیدہ تھیں۔تقویٰ کے باعث ہی نوح اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں
____________________
(۱)بحارالانوارج۷۰ ص۲۸۵۔
(۲)گذشتہ حوالہ۔
(۳)فروع کافی ج۸ص۵۲۔
نے نجات پائی ،صالح اور ان کے ساتھی آسمانی بجلی سے محفوظ رہے۔ تقویٰ کی بناء پر ہی صبر کرنے والے بلند درجات پر فائز ہوئے اور ہلاکت خیز مشکلات سے نجات حاصل کرسکے''
خلاصۂ کلام یہ کہ جو لوگ ﷲ کی مرضی اور احکام کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں اور حکم خدا کے سامنے اپنی ضرورتوں ،خواہشوں اور ترجیحات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو خداوند عالم زمین وآسمان کو ان کے رزق کا ضامن بنادیتا ہے۔ان کے امور کا خود ذمہ دار ہوجاتا ہے اور انھیں ان کے نفسوں کے حوالہ نہیں کرتا اور انکی سعی وکوشش میں توفیق و برکت عطا کرتا ہے۔
یہاں پھرسے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان باتوں کایہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تقوی کے بعدرزق حاصل کرنے کے لئے سعی وجستجو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔حصول رزق کے لئے صرف تقویٰ کوکافی سمجھ لینا اسلامی نظریہ نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ تقویٰ کے ذریعہ بندہ پر رزق نازل ہوتا ہے اوراس طرح آسانی کے ساتھ مختصر زحمت سے ہی رزق حاصل ہوجاتا ہے۔
تقویٰ کی بنا پر نجات پانے والے تین لوگوں کا واقعہ
نافع نے ابن عمر سے نقل کیا کہ پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:تین آدمی چلے جار ہے تھے کہ بارش ہونے لگی تو وہ لوگ پہاڑکے دامن میں ایک غار میں چلے گئے اتنے میں پہاڑ کی بلندی سے ایک بڑا سا پتھر گرااور اسکی وجہ سے غار کا دروازہ بند ہوگیا۔تو ان لوگوں نے آپس میں کہا:اپنے اپنے اعمال صالحہ پر نظر دوڑائو اور انھیں کے واسطہ سے خدا سے دعاکرو شائد خدا کوئی آسانی پیداکردے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے اورمیرے بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں بکریاں چراکر ان کا پیٹ پالتا تھا واپس آکر بکریوں کا دودھ نکالتا تو پہلے والدین کے سامنے پیش کرتا اس کے بعد اپنے بچوں کودیتا۔
اتفاقاً میں ایک دن صبح سویرے گھر سے نکل گیا اور شام تک واپس نہ آیا۔جب میں واپس پلٹا تومیرے والدین سوچکے تھے میں نے روزانہ کی طرح دودھ نکالا اور دودھ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہوگیا مجھے یہ گوارہ نہ ہوا کہ انھیںبیدار کروں اور نہ ہی یہ گوارہ ہوا کہ والدین سے پہلے بچی کو دودھ پیش کروں حالانکہ بچی بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی اور میرے قدموں میں بلبلا رہی تھی مگر میری روش میں تبدیلی نہ آئی یہاں تک کہ صبح ہوگئی پروردگار ا!اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لئے انجام دیا ہے تو اسی عمل کے واسطہ سے اتنی گنجائش پیدا کردے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں ﷲ نے اتنی گنجائش پیدا کردی اور ان لوگوں کو آسمان دکھائی دینے لگا۔
دوسرے نے کہا:میرے چچاکی ایک لڑکی تھی میں اس سے ایسی شدید محبت کرتا تھا جیسے کہ مرد عورتوں سے کرتے ہیں میں نے اس سے مطلب برآری کی خواہش کی اس نے سودینار کی شرط رکھی میں نے کوشش کرکے کسی طرح سودینار جمع کئے انھیں ساتھ لے کر اسکے پاس پہونچ گیا۔اور جب شیطانی مطلب پورا کرنے کی غرض سے اس کے نزدیک ہو ا تو اس نے کہا''اے بندئہ خدا ﷲ سے ڈرو اور ناحق میرا لباس مت اتارو''یہ بات سن کر میں نے اسے چھوڑدیا۔پروردگار اگر میرا یہ عمل تیرے لئے ہے تو تھوڑی گنجائش اور مرحمت کردے۔اللہ نے تھوڑی سی گنجائش اور عطا کردی۔
تیسرے آدمی نے کہا میں نے ایک شخص کوتھوڑے چا ول کی اجرت پراجیرکیا جب کام مکمل ہوگیا تو اس نے اجرت کا مطالبہ کیا میں نے اجرت پیش کردی لیکن دہ چھوڑ کر چلا گیا میں اسی سے کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ اسکی قیمت سے بیل اور اسکا چرواہاخرید لیا۔ایک دن وہ مزدور آیا اور مجھ سے کہا:خدا سے ڈرو اور میرا حق مجھے دے دو۔میں نے کہا جائووہ بیل اور چرواہا لے لو اس نے پھر کہا خدا سے ڈرو اور میرا مذاق مت اڑائو۔میں نے کہا میں ہرگز مذاق نہیں کررہا ہوں یہ بیل اور چرواہا لے لو۔چنانچہ وہ لے کر چلاگیا۔پروردگار میرا یہ عمل اگر تیرے لئے تھاتوہمارے لئے بقیہ راستہ کھول دے ۔ ﷲ نے راستہ کھول دیا۔( ۱ )
____________________
(۱)صحیح بخاری،کتاب الادب،باب اجابةدعاء من بَرّوالدیہ ج۵ ص۴۰ط؛مصر۱۲۸۶ھ ق۔فتح الباری للعسقلانی ج۱۰ص۳۳۸شرح القسطلانی ج۹ص۵۔صحیح مسلم کتاب الرقاق باب قصةاصحاب الغار الثلاثةوالتوسّل بصالح الاعمال ج۸ص۸۹ط؛دارالفکر۔ وشرح النووی ج۱۰ص۳۲۱وذم الہوی لابن الجوزی ص۲۴۶
۳۔کففت علیہ ضیعتہ
اس جملہ کے دو معنی ہوسکتے ہیں کیونکہ''کف'' جمع کرنے اوراکٹھاکرنے کے معنی میں بھی ہے اور یہی لفظ منع کرنے اورروکنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لہٰذاپہلے معنی کے لحاظ سے اس جملہ'' و کففت علیہ ضیعتہ''کے معنی یہ ہوں گے ''میں اس کے درہم برہم امور کو جمع کردوں گا اس کے سامان واسباب کانگہبان ،اسکے امور کا ذمہ دار اور اسکی معیشت کا ضامن ہوں''ابن اثیر اپنی کتاب ''النہایة''میں ''کف''کے معنی کے بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہ لفظ ''جمع کرنے ''کے معنی میں ہو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے:
(المؤمن أخ المؤمن یکفّ علیه ضیعته )( ۱ )
''ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے جو اسکے سرمایہ کو اسکے لئے اکٹھاکرکے رکھتا ہے ''
اسکے دوسرے معنی منع کرنا،روکنا اور دفع کرنا ہیں جیسے :
(کفّه عنه فکفّ، أی دفعه وصرفه ومنعه،فاندفع وانصرف،وامتنع )
اس نے اسکو روکا یعنی اسکا دفاع کیا منع کیا اور واپس پلٹایا تو وہ دفع ہوگیا ،پلٹ گیا اور رک گیا اس معنی کے لحاظ سے مذکورہ حدیث کے معنی یہ ہونگے :
''میں نے اسکی بربادی کو دفع کردیا اور اسکی بربادی اور اسکے درمیان حائل ہوگیا اور اسے ہدایت دیدی اور راستے کے تمام نشانات واضح و روشن کردئے''( ۲ )
علامہ مجلسی(رح)نے اس فقرہ کی تفسیر میں اپنی کتاب بحار الانوار میں تحریر کیا ہے :کہ اس جملہ میں چند احتمالات پائے جاتے ہیں :۱۔وہ معنی جو ابن ثیر نے نہایہ میں ذکر کئے ہیں یعنی اسکے درہم
____________________
(۱)النہایة لا بن ا لاثیرج۴ص۹۰۔
(۲)اقرب المواردج۲ص۱۰۹۳۔
برہم معاملات معیشت کو سمیٹ دو نگااور اسمیں ''علیٰ''کے ذریعہ جو تعدیہ ہے اسکی بنا پر،برکت اور شفقت و غیرہ کے معنی میں ہے یا''علیٰ ''الیٰ کے معنی میں ہے جسکی طرف نہایہ میں اشارہ موجود ہے البتہ اس صورت میں برکت وغیرہ کے معنی مراد نہ ہونگے''
۲۔''کف''منع کرنے اور ''علیٰ ''،''فی'' کے معنی میں ہو اور'' ضیعہ''ضائع اوربربادہونے کے معنی ہو یعنی اس نے اسکی جان،مال ،محنت او ر اسکی تمام متعلقہ چیزوں کو ضائع ہونے سے بچالیا اسکی تائید اس فقرہ ''وکففت عنہ ضیعتہ''سے بھی ہوتی ہے جو شیخ صدوق(رح)کی روایت کے ذیل میں آئندہ ذکر ہوگا۔
ہمیں یہ دوسرے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں جو حدیث کے سیاق کے مطابق اور اس سے مشابہ بھی ہیں خاص طور سے جب ہمیں یہ بھی معلوم ہوگیا کہ شیخ صدوق (رح) نے بعینہ اسی روایت میں ''وکففت عنہ ضیعتہ''نقل کیا ہے جس میں علیٰ کی جگہ عن سے تعدیہ آیا ہے اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کف دفع یا منع کرنے اور پلٹانے کے معنی میں ہے جو کہ رفع کے معنی سے مختلف ہیں کیونکہ دفع کے معنی ،کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اسے روک دینا ہیں اور رفع کے معنی کسی چیز کے وجودمیں آجانے کے بعد اسے زائل کردینا یا ختم کردینا ہیں یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ رفع علاج کی طرح ہوتا ہے اور دفع بیماری آنے سے پہلے اسے روک دینے کی طرح ہے ۔
اور کف ،دفع کے معنی میں ہے نہ کہ رفع کے معنی میں جسکے مطابق اسکے معنی یہ ہونگے خداوند عالم نے اسکو ضائع نہیں ہونے دیا ،یاوہ اسکی بربادی کے لئے راضی نہ ہوا اور یہ بھی ایک قسم کی ہدایت ہے کیونکہ ہدایت کی دو قسمیںہیں :
۱۔گمراہی کے بعد ہدایت
۲۔گمراہی سے پہلے ہدایت
ان دونو ںکو ہی ہدایت کہا جاتا ہے لیکن پہلی والی ہدایت اس وقت ہوتی ہے جب انسان گمراہی اور تباہی میں مبتلا ہوچکا ہو لیکن دوسری قسم کی ہدایت اسکی گمراہی اور بربادی سے پہلے ہی پوری ہوجاتی ہے اور یہ قسم پہلی قسم سے زیادہ بہتر ہے ۔
حدیث میں (کف ضیعتہ)بربادی سے حفاظت کا تذکرہ ہے نہ کہ ہدایت کا اور بربادی سے حفاظت ،
ہدایت کا نتیجہ ہے اس لئے یہ منزل مقصود تک پہونچانے کے معنی میں ہے نہ کہ راستہ دکھانے اور یاد دہانی کے معنی میں ۔
ہدایت کے معنی
لفظ ہدایت دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ۔ہدایت کے ایک معنی منزل مقصود تک پہونچانا ہیں اور دوسرے معنی راستہ بتا نا ،راہنمائی کرناہیں جیسا کہ خداوند عالم کے اس قول :
( انک لاتهدی من أحببت ولکن ﷲ یهدی من یشائ ) ( ۱ )
''پیغمبر بیشک آپ جسے چا ہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیدیتا ہے ''
میں یہ لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے ۔طے شدہ بات ہے کہ یہاں جس ہدایت کی نفی کی جارہی ہے وہ منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں ہے کہ یہ چیز صرف پروردگار عالم سے مخصوص ہے ورنہ راستہ دکھانا رہنمائی کرنا تو پیغمبر اسلام کا فریضہ اورآپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے اس معنی میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے لئے ہدایت کا انکار کرکے اسے صرف پروردگا ر سے مخصوص کردینا ممکن نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے :
( وانک لتهدی الی صراطٍ مستقیم ) ( ۲ )
''اور بیشک آپ لوگوں کو سیدھے راستہ کی ہدایت کررہے ہیں ''
اسی معنی میں قرآن کریم میں مومن آل فرعون کا یہ جملہ ہے :
____________________
(۱)سورئہ قصص آیت ۵۶۔
(۲)سورئہ شوریٰ آیت۵۲۔
( یا قوم اتّبعون أهدکم سبیل الرشاد ) ( ۱ )
''اے قوم والو :میرا اتباع کرو،میں تمھیں ہدایت کا راستہ دکھا دوں گا ''
یہاں پر بھی ہدایت ،راہنمائی اور راستہ دکھانے کے معنی میں ہے نہ کہ منزل مقصود تک پہنچانے کے معنی میں ۔۔۔اس حدیث شریف میں بھی ہدایت کے پہلے معنی (منزل تک پہنچانا) ہی زیادہ مناسب ہیںاس لئے کہ دوسرے معنی کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ انسان ضائع نہ ہو بلکہ ایصا ل الی المطلوب ہی انسان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور انسان کو قطعی طور پر اللہ تک پہنچانے کا ضامن ہے
سیاق وسباق سے بھی یہی معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ گفتگو ان لوگوں پرخصوصی فضل الٰہی کی ہے کہ جو اپنے خواہشات پر ﷲ کی مرضی کو مقدم کرتے ہیں لہٰذا فضل وعنایت کاخصوصی تقاضا یہ ہے کہ انھیں منزل مقصود تک پہنچا یا جائے ورنہ رہنمائی اور راستہ دکھا ناتو خدا کی عام عنایت ورحمت ہے جوصرف مومنین سے یا ان لوگوں سے مخصوص نہیں ہے کہ جوﷲ کی مرضی کو مقدم کرتے ہوں بلکہ یہ عنایت تو ان لوگوں کے شامل حال بھی ہے کہ جو اپنی خواہشات کو ﷲ کی مرضی پر مقدم کرتے ہیں ۔
ﷲ بندہ کو بربادی اورضائع ہونے سے کیسے بچاتا ہے ؟
درحقیقت یہ کام بصیرت کے ذریعہ ہوتا ہے ۔بصیر ت کے اعلیٰ درجات پر فائز انسان قطعی طور پر ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے ۔
لہٰذا جب خداوندعالم کسی بندہ کیلئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اور اسے بربادی سے بچانا چا ہتا ہے تو اسے بصیرت مرحمت کر دیتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ نجات پاجاتا ہے اور خدا تک اس کی رسائی قطعی ہوجاتی ہے یہ بصیرت اس منطقی دلیل وبرہان سے الگ ہے کہ جس کے ذریعہ بھی انسان خدا تک پہنچتا
____________________
(۱)سورئہ غافرآیت ۳۸۔
ہے اور اسلام اس کا بھی منکر نہیں ہے بلکہ اسے اپنا نے اوراختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے وہ اسے ہر شخص کے دل کی گہرائیوں میں اتارنا چاہتا ہے اس لئے کہ انسانوں کی بہت بڑی تعداد عقل و منطق کے سہارے ہی خدا تک پہنچتی ہے ۔
بصیرت کا مطلب حق کا مکمل طریقہ سے واضح دکھائی دینا ہے ۔ایسی رویت منطقی استدلال کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے اور صفائے نفس اور پاکیزگی ٔ قلب کے ذریعہ بھی حاصل ہو سکتی ہے یعنی انسان کسی ایک راستہ سے اس بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے یا عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعہ یا پاکیزگی ٔ نفس کے راستہ ۔
اسلام ان میں سے کسی ایک کو کافی قرار نہیں دیتا بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کے اوپر دونوں کو اختیار کرنا ضروری ہے ۔یعنی عقلی روش کو اپنانا بھی ضروری ہے اور نفس کو پاکیزہ بنانا بھی ۔اس آیۂ شریفہ میں قرآن مجید نے دونوں باتوں کی طرف ایک ساتھ اشارہ کیا ہے:
( هوالذی بعث فی الامیّین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته ویزکّیهم و یعلّمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبلُ لفی ضلالٍ مبینٍ ) ( ۱ )
'' اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا جو انھیں میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے ،ان کے نفوس کو پاک کرے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے''
تزکیہ کا مطلب صفائے قلب اور پاکیزگیٔ نفس ہے جس سے معرفت الہی کے بے شمار دروازے کھلتے ہیں ۔
معرفت کا دوسرا باب (تعلیم )ہے بہر حال بصیر ت چاہے عقل ومنطق کا ثمرہ ہویا تزکیہ وتہذیب نفس کا یہ طے ہے کہ حیات انسانی میں بصیرت کا سر چشمہ پروردگار عالم ہی ہے اسکے علاوہ کسی اور جگہ سے بصیرت کا حصول ممکن نہیں ہے اور اس تک رسائی کا دروازہ عقل وتزکیۂ نفس ہے ۔
____________________
(۱)سورئہ جمعہ آیت۲۔
بصیرت اور عمل
ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کردیں کہ اسلام بصیرت کیلئے ''علم ''اور تزکیہ یا''عقل اور صفائے قلب ''دونوں کو تسلیم کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ان میں سے ایک ،دوسرے سے بے نیاز نہیں کرسکتا لیکن یہ بھی طے ہے کہ حصول بصیرت کیلئے تزکیہ زیادہ اہم اور موثر ہے اسی لئے قرآنِ کریم نے آیہ ٔ بعثت میں تزکیہ کو علم پر مقدم رکھا ہے :
( یزکّیهم ویعلّمهم الکتاب والحکمة ) ( ۱ )
''ان کے نفوس کو پاک کرے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے''
مناسب ہوگا کہ چند لمحے ٹھہرکر ہم خود (تزکیہ )کے بارے میں بھی غور کریں اور دیکھیں کہ تزکیۂ نفس کیسے ہوتا ہے ؟
رہبا نیت کے قائل مذاہب میں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی جائے اور حیات دنیوی سے فرار اختیار کیا جائے اس طرح تزکیہ کا خواہشمند انسان جب اپنی ہویٰ وہوس اور خواہشات نفسانی اور فتنوں سے پرہیز کرے گا تو اسکا نفس پاکیزہ ہوجا ئے گا لیکن اسلامی طریقہ ٔ تربیت میں صور تحال اس کے بالکل برعکس ہے ۔اسلام تزکیہ کے خواہشمندکسی بھی مسلمان کو ہر گزیہ نصیحت نہیں کرتا کہ فتنوں سے فرار کرے خواہشات اور ہویٰ وہوس کو کچل دے بلکہ اسلام فرار کے بجائے فتنوں سے مقابلہ اور خواہشات کو کچل کر ختم کر نے کے بجائے انھیں حدا عتدال میں رکھنے کی دعوت دیتاہے ۔
اسلام کا طریقۂ تربیت ،عمل کو تزکیہ کی بنیاد قرار دیتا ہے نہ کہ گوشہ نشینی ،رہبا نیت اور محرومی کو ۔اور یہی عمل بصیرت میں تبدیل ہوجاتا ہے جس طرح بصیرت عمل میں ظاہر ہوتی ہے لہٰذا
____________________
(۱)سورئہ جمعہ آیت۲
دیکھنا یہ ہوگا کہ عمل کیا ہے ؟بصیرت کسے کہتے ہیں ؟اور ان دونوں میں کیا رابطہ ہے ؟
بصیرت اور عمل کا رابطہ
بصیرت کے بارے میں اجمالی طور پرگفتگو ہوچکی ہے ۔۔یہاں عمل سے مراد ہروہ سعی و کو شش ہے جس کو انسان رضائے الہی کی خاطر انجام دیتا ہے اس کے دورخ ہوتے ہیں ایک مثبت ،یعنی اوا مرخدا کی اطاعت اور دوسرا سلبی یعنی اپنے نفس کو حرام کا موں سے محفوظ رکھنا ۔ اس طرح عمل سے مرادیہ ہے کہ خوشنودی پر وردگار کی خاطر کوئی کام کرے چاہے کسی کام کو بجا لا یا جائے اور چا ہے کسی کام سے پر ہیز کیا جائے ۔بصیرت اور عمل کے درمیان دوطرفہ رابطہ ہے ۔ بصیرت عمل کا سبب ہوتی ہے اور عمل ،بصیرت کا ۔۔۔اور دونوں کے آپسی اور طرفینی رابطے سے خود بخود بصیرت اور عمل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے عمل صالح سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے اور بصیرت میں زیادتی عمل صالح میں اضافہ کا سبب بنتی ہے اس طرح انمیں سے ہر ایک دوسرے کے اضافہ کا موجب ہوتا ہے یہاں تک کہ انسان انھیں کے سہارے بصیرت وعمل کی چوٹی پر پہونچ جاتا ہے ۔
۱۔ عمل صالح کا سرچشمہ بصیرت
بصیرت کا ثمر ہ عمل صالح ہے ۔اگر دل وجان کی گہرائیوں میں بصیرت ہے تو وہ لامحالہ عمل صالح پر آمادہ کر ے گی بصیرت کبھی عمل سے جدا نہیں ہوسکتی ہے روایات اس چیز کو صراحت سے بیان کرتی ہیں کہ انسان کے عمل میں نقص اورکوتاہی دراصل اس کی بصیرت میں نقص اورکوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے ۔اس سلسلہ میں چند روایات ملا حظہ فرما ئیں ۔
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے جبرئیل امین سے نقل فرما یا ہے :
(الموقن یعمل ﷲکأنه یراه،فان لم یکن یریٰ ﷲ فان ﷲ یراه )( ۱ )
''درجۂ یقین پر فائز انسان ﷲ کیلئے اس طرح عمل انجام دیتا ہے جیسے وہ ﷲکو دیکھ رہا ہے اگر وہ ﷲکو نہیں دیکھ رہا ہے تو کم از کم ﷲ تو اس کو دیکھ رہا ہے ''
مولائے کائنات سے منقول ہے :
(یُستدل علیٰ الیقین بقصرالامل،واخلاص العمل،والزهد فی الدنیا )( ۲ )
''آرزووں کی قلت، اخلاص عمل اور زہد، یقین کی دلیلیں ہیں''
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :
(التقویٰ ثمرةالدین،وأمارةالیقین )( ۳ )
''تقویٰ دین کا ثمر ہ اور یقین کا سردار ہے''
نیز آپ سے مروی ہے:
(من یستیقن،یعملْ جاهداً )( ۴ )
''صاحب یقین بھر پور جدوجہد کے ساتھ عمل انجام دیتا ''
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے :
(ان العمل الدائم القلیل علیٰ الیقین،أفضل عندﷲ من العمل الکثیرعلیٰ غیریقین )( ۵ )
____________________
(۱)بحارالانوارج ۷۷ص۲۱ ۔
(۲)غرر الحکم ج ۲ص ۳۷۶۔
(۳)غررالحکم ج۱ص۸۵۔
(۴)غررالحکم ج۲ص۱۶۶۔
(۵)اصول کافی ج۲ص۵۷۔
''یقین کے ساتھ مسلسل تھوڑا عمل کرناﷲکے نزدیک یقین کے بغیربہت زیادہ عمل سے افضل ہے ''
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے:
(لاعمل الابیقین،ولایقین الابخشوع )( ۱ )
''یقین کے بغیر عمل اور خشوع کے بغیر یقین بے فا ئدہ ہے ''
آپ نے ارشاد فرمایا :
(العامل علیٰ غیربصیرةکالسائر علیٰ سراب بقیعة لا یزیده سرعةالسیر الابعدا )( ۲ )
''بصیرت کے بغیر عمل انجام دینے والا ایسا ہے جیسے سراب کے پیچھے دوڑنے والا کہ اسکی تیزی اسے منزل سے دور ہی کرتی جاتی ہے ''
صادق آل محمد کا ہی یہ بھی فرمان ہے :
(انکم لا تکونون صالحین حتیٰ تعرفوا،ولا تعرفون حتیٰ تصدقوا ولاتصدقون حتیٰ تسلموا )( ۳ )
''تم اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتے جب تک معرفت حاصل نہ کرلو اور یقین کے بغیر معرفت اور تسلیم کے بغیر تصدیق حاصل نہ ہو گی ''یعنی تصدیق معرفت اور معرفت، عمل صالح کاذریعہ ہے
امام جعفر صادق سے مروی ہے :
____________________
(۱)تحف العقول ص۲۳۳۔
(۲)وسائل الشیعہ ج ۱۸ ص ۱۲۲ح۳۶۔
(۳)بحارالانوار ج ۶۹ ص۱۰۔
(لایقبل عمل الا بمعرفة،ولامعرفة الا بعمل،فمن عرف دلّته المعرفة علیٰ العمل )( ۱ )
''معرفت کے بغیر کو ئی عمل قابل قبول نہیں ہے اور عمل کے بغیر معرفت بھی نہیں ہو سکتی جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو معرفت خود عمل پر ابھارتی ہے ''
امام محمد باقر کا ارشاد ہے :
(لایقبل عمل الابمعرفة،ولامعرفة الا بعمل،ومن عرف دلّته معرفته علیٰ العمل ،ومن لم یعرف فلا عمل له )( ۲ )
''معرفت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا اور عمل کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہوتی جب معرفت حاصل ہوجاتی ہے تووہ خود انسان کو دعوت عمل دیتی ہے جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پاس عمل بھی نہیں ہے''
۲۔بصیرت کی بنیاد عمل صالح
ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عمل صالح کی بنیاد بصیرت ہے اسی کے با لمقابل بصیرت کا سرچشمہ عمل صالح ہے ۔دوطرفہ متبادل رابطوں کے ایسے نمونے آپ کواسلامی علوم میں اکثر مقامات پر نظر آئیں گے ۔
قرآن کریم عمل صالح اور بصیرت کے اس متبادل اور دوطرفہ رابطہ کا شدت سے قائل ہے اور بیان کرتا ہے کہ بصیرت سے عمل اور عمل صالح سے بصیرت حاصل ہوتی ہے اور عمل صالح کے ذریعہ ہی انسان خداوندعالم کی جانب سے بصیرت کا حقدار قرار پاتا ہے ۔
( والذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سُبُلَنا وان ﷲ لمع المحسنین ) ( ۳ )
____________________
(۱)اصول کافی ج۱ ص۴۴۔
(۲)تحف العقول ص۲۱۵۔
(۳)سورئہ عنکبوت ۶۹۔
''اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے انھیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے اور یقیناﷲحسن عمل والوں کے ساتھ ہے ''
آیت واضح طورپر بیان کر رہی ہے کہ جہاد (جوخود عمل صالح کا بہترین مصداق ہے )کے ذریعہ انسان ہدایت الہی کو قبول کرنے اور حاصل کرنے کے لائق ہوتا ہے ۔
( لنهدینّهم سبلنا ) ( ۱ )
''ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرینگے ''
حدیث قدسی میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے مروی ہے :
(لایزال عبدی یتنفّل لی حتیٰ اُحبّه ، فاذا أحببته کنت سمعه الذی به یسمع، وبصره الذی یبصر به،و یده التی بها یبطش )( ۲ )
''میرا بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر نے لگتا ہو ں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ذریعہ وہ سنتا ہے اسکی
____________________
(۱)خداوند عالم ہمارے شیخ جلیل مجاہد راہ خدا شیخ عباس علی اسلامی پر رحمت نازل کرے میں ان سے اکثر یہ سنا کرتا تھا :کہ انسان کو ہر حرکت کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہو تی ہے جن کا بدل ممکن نہیں ہے ایک تو وہ اس چیز کا محتاج ہوتا ہے جو تحرک میں اس کی مدد کر ے اور حرکت کی تکان کو ہلکا کردے اور اسے ایسی طاقت و قوت عطا کرے جس سے وہ اپنی حرکت کو جاری رکھ سکے اور دوسرے اس چیز کا محتاج ہوتا ہے جو اسے صحیح راستہ کی رہنمائی کرتی رہے تا کہ وہ راستہ سے بھٹکنے نہ پائے یعنی اسے ایسی قوت وطاقت کی ضرورت ہو تی ہے جو ہدایت اور بصیرت کے مطابق اس کی حرکت کا راستہ معین کرے تاکہ وہ صراط مستقیم پر چلتا رہے اور انہیں دونوں چیزوں کا وعدہ ہم سے پروردگار عالم نے سورئہ عنکبوت کی آخری آیت میں فر مایا ہے :(والذین جاھدوافینالنھدینھم سبلناوانّ اللّٰہ لمع المحسنین )پس جو لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں پروردگار عالم ان کو پہلے تو پشت پناہی اور قوت و طاقت عطا کرتا ہے اور یہی خدا کی معیت ہے '' انّ اللّٰہ لمع المحسنین) اور دوسرے ان کوبصیرت و ہدایت عطا کرتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے (لنهدینهم سبلنا )۔
(۲)اصول کافی ج۲ص۳۵۲۔
آنکھیں بن جاتا ہوں جنکے ذریعہ وہ دیکھتا ہے اسی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعہ وہ چیزوں کو چھوتا ہے ''
یہ بہت ہی مشہور ومعروف حدیث ہے تمام محدثوں ،معتبرراویوں اور مشایخ حدیث نے اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے نقل مختلف ہے مگر الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں اور روایت صحیح ہے اوروضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ عبادت ،معرفت ویقین کا دروازہ ہے اور بندہ قرب الٰہی کی منزلیں طے کرتارہتا ہے یہاں تک کہ ﷲ اسے بصیرت عطا کردیتا ہے پھر وہ ﷲ کے ذریعہ سنتا ہے دیکھتا ہے اور ادراک حاصل کرتا ہے ۔۔۔اور ظاہر ہے کہ جو ﷲ کے ذریعہ یہ کام انجام دے گا تو اسکی سماعت بصارت اور معرفت میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے ۔
دوسرا رخ
عمل اور بصیرت کے درمیان دوطرفہ رابطہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح بصیرت سے عمل اور عمل سے بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس رابطہ کا دوسرا رخ بھی ہے جس کے مطابق برے اعمال اورکردارکی خرابی بصیرت میں کمی ،اندھے اور بہرے پن کا سبب ہوتے ہیں اس کے برعکس یہ چیزیں بے عملی اور گناہ وفساد کا باعث ہوتی ہیں ۔
گذشتہ صفحات میں ہم نے روایات کی روشنی میں عمل اور بصیرت کے درمیان مثبت رابطہ کی وضاحت کی تھی اسی طرح اس رابطہ کے دوسرے رخ کو بھی احادیث کی روشنی میں ہی پیش کررہے ہیں ۔
بے عملی سے خاتمۂ بصیرت
اسلامی روایات سے یہ صاف واضح ہوجاتا ہے کہ برے اعمال سے بصیرت ختم ہوتی رہتی ہے قرآن کریم نے بھی متعدد مقامات پراس حقیقت کا اظہار واعلان کیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :
( أفرأیت من اتّخذ الٰهه،هواه وأضلّه ﷲ علیٰ علمٍ وختم علیٰ سمعه وقلبه وجعل علیٰ بصره غشاوةً فمن یهدیه من بعد ﷲ ) ( ۱ )
''کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنالیا اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کراسے گمراہی میں چھوڑ دیا اور اسکے کان اوردل پرمہرلگا دی ہے اور اسکی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے ''
جن لوگوں نے خدا کو چھوڑکر کسی دوسرے معبود کی عبادت کرکے شرک اختیار کیا ﷲ ان سے بصیرت سلب کرلیتا ہے اور ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگادیتا ہے آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے اور طے ہے کہ جب ﷲ کسی بندہ سے بصیرت سلب کرلے تو پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اسی کو قرآن مجیدان الفاظ میں بیان کرتا ہے :
( کذلک یُضلّ ﷲ الکافرین ) ( ۲ )
''ﷲاسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑدیتا ہے ''یہ جملہ دراصل گذشتہ تفصیل کا اجمالی بیان ہے
( کذلک یُضل ﷲ من هومسرف مرتاب ) ( ۳ )
'' اسی طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شکی مزاج انسانوں کو انکی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے''
اس لئے کہ اسراف گمراہی کی طرف لے جاتا ہے
اسی طرح ارشاد ہوتا ہے :
( وما یُضلّ به الا الفاسقین ) ( ۴ )
''اور گمراہی صرف انکا حصہ ہے جو فاسق ہیں ''
____________________
(۱) سورئہ جاثیہ آیت۲۳۔
(۲)سورئہ غافرآیت۷۴۔
(۳)سورئہ غافرآیت ۳۴۔
(۴)سورئہ بقرہ آیت۲۶ ۔
یا :( ویُضلّ ﷲ الظالمین ) ( ۱ )
''ﷲ ظالمین کو گمراہی میں چھوڑدیتا ہے ''
اس کا مطلب یہ ہے کہ فسق اورظلم ،گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں ۔
خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( کَلا بل ران علیٰ قلوبهم ماکانوا یکسبون ) ( ۲ )
''نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے ''
انسان جب گنا ہوں اور معصیتوںکا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے یہی اعمال ایک ٹیلہ کی شکل میں جمع ہو کر اس کے قلب کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور پھر خدا اور حق اسے نظر نہیں آتے ۔ خدا وند عالم کا ارشاد ہے :
( انَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِ ی القَوْم َ الظَّالِمِیْنَ ) ( ۳ )
''ﷲ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ''
( ان ﷲ لا یهدی القوم الکافرین ) ( ۴ )
''ﷲکافروں کی ہدایت نہیں کرتا ''
( انَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِ ی القَوْمَ الْفاسقین ) ( ۵ )
''یقینا ﷲ بدکار لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ''
____________________
(۱)سورئہ ابراہیم آیت۲۷۔
(۲)سورئہ مطففین آیت۱۴۔
(۳)سورئہ قصص آیت۰ ۵۔
(۴)سورئہ مائدہ آیت ۶۷۔
(۵)سورئہ منافقون آیت۶۔
( انَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِ ی من هوَ مُسْرِف کَذَّا ب ) ( ۱ )
''بیشک ﷲ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا ''
( انَّ اللّٰهَ لَایَهْدِی من هُوکاذب کفار ) ( ۲ )
''ﷲ کسی بھی جھوٹے اور نا شکری کرنے والے کی ہدایت نہیں کرتا ''
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ارشاد ہے :
(لولا تکثیر فی کلامکم ،وتمزیج فی قلوبکم، لرأیتم ما أریٰ و سمعتم ما اسمع )( ۳ )
''اگر تمہارے کلام میں کثرت نہ ہو تی اور قلوب آلودہ نہ ہوتے تو تم بھی وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہی سنتے جومیں سنتاہوں ''
امیر المو منین حضرت علی کا ارشاد ہے :
(کیف یستطیع الهدیٰ من یغلبه الهویٰ )( ۴ )
''جس پرہویٰ وہوس غالب ہو وہ کیسے ہدایت پاسکتا ہے ؟''
آپ کا ہی ارشاد ہے :
(انکم ان أمّرْتُم علیکم الهویٰ أصمّکم وأعماکم وأرداکم )( ۵ )
''اگر تم نے اپنے اوپر ہویٰ وہوس کوغالب کرلیاتو وہ تمہیں بہرا،اندھا اور پست بنادیں گی ''
اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل باطل اور فضول باتیں کرنااور دلوں میں حق و باطل کا گڈمڈہونایہ
____________________
(۱)سورئہ غافرآیت۲۸۔
(۲)سورئہ زمرآیت۳۔
(۳)المیزان ج۵ص۲۹۲۔
(۴)غرر الحکم ج۲ ص ۹۴۔
(۵)غررالحکم ج۱ص۲۶۴۔
آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرابنا دیتا ہے ۔
امام محمد باقر نے فرمایا :
(مامن عبد الا وفی قلبه نکتة بیضائ،فاذا أذنب خرج فیتلک النکتة،نکتة سودائ،فاذا تاب ذهب ذٰلک السواد،وان تمادیٰ فی الذنوب زادذلک السواد حتیٰ یغطّی البیاض،فاذا غطّیٰ البیاض لم یرجع صاحبه الیٰ خیرأبداً،وهو قول ﷲ عزّوجل: ( بل ران علیٰ قلوبهم ماکانوا یکسبون ) ( ۱ )
''ہر انسان کے دل میں ایک سفیدی ہوتی ہے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سفیدی میںایک سیاہ نقطہ نمودار ہوجاتا ہے اگر گناہگار تو بہ کرلیتا ہے تو وہ سیاہی زائل ہوجاتی ہے لیکن اگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہے تو سیاہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ سیاہی دل کی سفیدی کو ڈھانپ لیتی ہے اور جب سفیدی پوشیدہ ہوجاتی ہے تو ایسا انسان کبھی خیر کی جانب نہیں پلٹ سکتا ۔ یہی خدا وند عالم کے قول(بل ران علیٰ قلوبھم ماکانوا یکسبون)'نہیں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے'کے معنی ہیں''
یہی سیاہی جب قلب پر چھاجاتی ہے تو اسکے لئے حجاب بن جاتی ہے جس کے نتیجہ میں انسان سے بصیرت سلب ہوجاتی ہے بہ الفاظ دیگر انسان جب گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو بصیرت ختم ہوجاتی ہے ۔
امام محمد باقر کا ارشاد ہے :
(ماشیء أفسد للقلب من الخطیئة،ان القلب لیواقع الخطیئة فماتزال به حتیٰ تغلب علیه فیصیر أسفله أعلاه،وأعلاه أسفله ،قال رسول ﷲ صلىاللهعليهوآلهوسلم ( ۲ )
____________________
(۱)نوررالثقلین ج۵ص۵۳۱۔
(۲)گذشتہ حوالہ۔
''خطا سے بڑھ کر قلب کو فاسد کرنے والی کوئی شئے نہیں ہے ،بیشک جب دل میں کوئی برائی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اسی میں باقی رہ کر اس پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو اسکا نچلا حصہ اوپر اور اوپری حصہ نیچے ہو جاتا ہے''
رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا :(انّ المؤمن اذا أذنب کانت نکتة سوداء فی قلبه،فاذا تاب ونزع واستغفرصقل قلبه، وان ازداد زادت فذلک الرین الذی ذکره ﷲتعالیٰ فی کتابه ( کلّا بل ران علیٰ قلوبهم ماکانوایکسبون ) ( ۱ )
''مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے اگر تو بہ واستغفارکرلے تو اسکا قلب صیقل ہوجاتا ہے لیکن اگر گناہوں میں زیادتی ہوتی رہے تو یہی (رین) یعنی زنگ بن جاتا ہے جسے خدا نے آیت (کلاّبل ران علیٰ قلوبھم)میں فرمایا ہے ''
امیر المومنین حضرت علی کا ارشاد ہے:
(انْ أطعت هواک اصمک وأعماک )( ۲ )
''اگر تم ہویٰ وہوس کی اطاعت کروگے تو وہ تمہیں بہرا اور اندھا بنادے گی''
فقدان بصیرت برے اعمال کا سبب
جس طرح برائیوں اور گناہوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اسی کے برعکس ضلالت و گمراہی بھی گناہ اور بد عملی کاسبب ہوتی ہے اور اس طرح جہالت و ضلالت اور فقدان بصیرت کے باعث شقاوت و بدبختی ظلم واسراف جیسے برے اعمال وجود میں آتے ہیں ۔
خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( قالوا ربّنا غلبت علیناشِقوتنا وکنّا قوما ضالّین ) ( ۳ )
____________________
(۱)نورالثقلین ج۵ص۵۳۱۔
(۲)غررالحکم۔
(۳)سورئہ مومنون آیت ۱۰۶۔
''وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم پر بدبختی غالب آگئی تھی اور ہم لوگ گمراہ ہوگئے تھے''
امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا :
(لاورع مع غیّ )( ۱ )
''گمراہی کے بعد کوئی پارسائی نہیں رہتی ''
مولائے کائنات نے،معاویہ بن ابی سفیان کواپنے خط میں تحریر فرمایاہے:
(امریء لیس له بصر یهدیه،ولا قائد یرشده،قد دعاه الهویٰ فأجابه،وقاده الضلال فاتّبعه، فهجرلاغطاً،وضلّ خابطاً )( ۲ )
''(مجھے تیرا جوخط ملا ہے )یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے جس کے پاس نہ ہدایت دینے والی بصارت ہے اور نہ راستہ بتانے والی قیادت ۔اسے خواہشات نے پکارا تو اس نے لبیک کہدی اور گمراہی نے کھینچا تو اسکے پیچھے چل پڑا اور اسکے نتیجہ میں اول فول بکنے لگا اور راستہ بھول کر گمراہ ہوگیا''
آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے :
(من زاغ ساء ت عنده الحسنة،وحسنت عنده السیئة،وسکرسکرالضلالة )( ۳ )
''جوکجی میں مبتلا ہوا،اسے نیکی برائی اور برائی نیکی نظر آنے لگتی ہے اور وہ گمراہی کے نشہ میں چور ہوجاتا ہے ''
لہٰذا معلوم ہوا کہ بصیرت اور عمل میں دوطرفہ مستحکم رابطہ ہے یہ رابطہ مثبت انداز میں بھی
____________________
(۱)غررالحکم ج۲ص۳۴۵۔
(۲)نہج البلاغہ مکتوب ۷۔
(۳)نہج البلاغہ حکمت ۳۱۔
ہے اور منفی صورت میں بھی ۔جسے اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے ۔
۱۔بصیرت ،عمل صالح کی طرف لے جاتی ہے ۔
۲۔عمل صالح، بصیرت و ہدایت کا سبب ہوتا ہے ۔
۳۔ضلالت اور فقدانِ بصیرت، ظلم وجور جیسے دیگر برے اعمال اور گناہوںکا سبب ہوتی ہے ۔
۴۔برے اعمال اورظلم وجور سے بصیرت ختم ہوجاتی ہے ۔
خلاصۂ کلام
حدیث شریف کے فقرہ ''کففت علیہ ضیعتہ''کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ا س سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان جب خواہشات نفس کی مخالفت کرکے اپنے خواہشات کو ارادئہ الٰہی کا تابع بنادیتا ہے اور مالک کی مرضی کا خواہاں ہوتا ہے تو خدا اسے نور ہدایت اور بصیرت عنایت فرمادیتا ہے اور تاریک راستوںمیں اسکا ہاتھ تھام لیتا ہے ۔
خداوند عالم کا ارشاد ہے :
( یاأیّها الذین آمنوا اتقوا ﷲ وآمنوا برسوله یُؤتکم کِفلین من رحمته ویجعلْ لکم نوراً تمشون به ) ( ۱ )
''اے ایمان والو! ﷲسے ڈرو اور رسول پر واقعی ایمان لے آئو تا کہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوبڑے حصے عطا کردے اور تمہارے لئے ایسا نور قرار دیدے جس کی روشنی میں چل سکو ''
دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے :
( یاأیّها الذین آمنوا انْ تتّقوا ﷲ یجعلْ لکم فرقاناً ) ( ۲ )
____________________
(۱)سورئہ حدید آیت۲۸۔
(۲)سورئہ انفال آیت۲۹۔
''ایمان والو! اگر تم تقوائے الٰہی اختیار کروگے تو وہ تمہیں حق وباطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کردے گا ''
( واتّقوا ﷲ و یعلمکم ﷲ ) ( ۱ )
'' اوراللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہیں علم عطاکرے''
حضرت علی سے مروی ہے :
(هُدی من أشعر قلبه التقویٰ )( ۲ )
''وہ ہدایت یافتہ ہے جس نے تقویٰ کو اپنے دل کا شعار بنالیا ''
(هُدی من تجلبب جلباب الدّین )( ۳ )
''وہ ہدایت یافتہ ہے جس نے دین کا لباس اوڑھ لیا''
(من غرس أشجارالتُقیٰ،جنیٰ ثمار الهدیٰ)(۴)
''جس نے تقویٰ کے درخت بوئے وہ ہدایت کے پھل کھائے گا''
والحمد للہ رب العالمین
محمد مہدی آصفی
۱۰ ذی القعدہ ۱۴۱۲ قم
____________________
(۱)سورئہ بقرہ آیت ۲۸۲۔
(۲)غررالحکم ج۲ص۳۱۱۔
(۳)گذشتہ حوالہ۔
(۴)غررالحکم ج۲ ص۲۴۵۔
فہرست
حرف اول ۵
مقدمہ ٔ مؤلف ۸
حدیث قدسی ۹
حدیث قدسی ۱۰
پہلی فصل ۱۱
''ہویٰ'' (خواہش)قرآن وحدیث ۱۱
کی روشنی میں ۱۱
بنیادی محرکات ۱۲
۱۔فطرت: ۱۳
۲۔عقل : ۱۳
۳۔ارادہ: ۱۳
۴۔ضمیر: ۱۳
۵۔قلب ،صدر،: ۱۳
۶۔ہویٰ(خواہشیں): ۱۳
''ہویٰ'' کی اصطلاحی تعریف ۱۴
''ہویٰ''کے خصوصیات ۱۴
۱۔چاہت میںشدت ۱۵
۲۔خواہشات میں تحرک کی قوّت ۱۷
۳۔خواہشات اور لالچ کی بیماری ۱۸
خواہشات پر عقل کی حکومت ۲۱
انسان ،عقل اور خواہش کا مجموعہ ۲۲
خواہشات کی شدت اورکمزوری ۲۳
انسانی زندگی میں خواہشات کا مثبت کردار ۲۷
۱۔انسانی زندگی کا سب سے طاقتور محرک ۲۸
۲۔خواہشات ترقی کا زینہ ۲۹
عمل اور رد عمل کا سلسلہ ۳۶
خواہشات کا تخریبی کردار ۴۰
خواہشات اور طاغوت ۴۰
عقل اور دین ۴۲
خواہشات کی تباہ کاریاں ۴۳
تباہ کا ری کے مراحل ۴۵
خواہشات کی تخریبی کارروائیوں کا پہلا مرحلہ ۴۶
۲۔خواہشات گمراہی کا ذریعہ ۴۸
۳۔خواہشات ایک مہلک زہر ۴۹
۴۔خواہشات آفت اور بیماری ۴۹
۵۔خواہشات آزمائشوں کی بنیاد ۵۰
۶۔خواہشات فتنوں کی چر اگاہ ۵۰
۷۔خواہشات ایک پستی ۵۱
۸۔خو اہشات موجب ہلا کت ۵۲
۹۔خو اہشات انسان کی دشمن ۵۲
۱۰۔عقل کی بربادی ۵۲
خو ا ہشات کی تباہ کاری کا دو سرا مر حلہ ۵۳
خواہشات کا قیدی ۵۴
خواہشات کی قیدقرآن و حدیث کی روشنی میں ۵۶
انسان اور خواہشات کی غلامی ۵۸
اللہ نے بھی اسے نظر انداز کردیا ۵۹
خواہشات کی تباہیاں قرآن مجید کی روشنی میں ۶۰
۱۔زمین کی جانب رغبت ۶۳
۲۔آیات خدا سے محرومی ۶۳
۳۔شیطان کا تسلط ۶۵
۴۔ضلا لت و گمراہی ۶۶
۵۔لالچ ۶۶
خواہشات کا علاج ۶۸
ہوس کی تخریبی طاقت ۶۸
خواہشات کی پیروی پر روک اور انکی آزادی کے درمیان ۶۹
خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لئے ''عقل ''کا کردار ۷۲
عقل اور دین ۷۵
امام مو سیٰ کا ظم : ۷۶
عقل کے تین مراحل ۷۷
۱۔معر فت اور حجت آوری ۷۸
۲۔اطاعت خدا ۸۱
۳۔خواہشات کے مقابلہ کے لئے صبروتحمل(خواہشات کا دفاع) ۸۴
عقل اور خواہشات کی کشمکش اور انسان کی آخری منزل کی نشاندہی ۸۷
ضعف عقل اورقوت ہوس ۸۹
عقل کے لشکر ۹۱
لشکر عقل سے متعلق روایات ۹۳
پہلی روایت ۹۳
دوسری روایت ۹۸
روایت کی مختصر وضاحت: ۱۰۲
عقل کامل کے فوائداور اثرات ۱۱۶
۱۔حق کے اوپر استقامت ۱۱۶
۲۔دنیا سے دشمنی رکھناکامل عقل کا ثمر ہے ۱۱۶
۳۔خواہشات پر مکمل تسلط ۱۱۷
۴۔حسن عمل اورسلامتی کردار ۱۱۷
عصمتیں ۱۱۷
عصمتوں کے بارے میں مزید گفتگو ۱۲۱
دوسری آیۂ کریمہ : ۱۲۲
عصمتوں کی قسمیں ۱۲۶
خوف الٰہی ۱۲۷
خوف ایک پناہ گاہ ۱۳۰
چند واقعات ۱۳۳
حیاء ۱۳۶
ﷲ تعالیٰ سے حیائ ۱۳۷
بارگاہ خدا میں قلت حیا کی شکایت ۱۴۱
دوسری فصل ۱۴۳
۱۔اسکے امور کو درہم برہم کردوںگا ۱۴۴
ٹھوس شخصیت ۱۴۵
عماربن یاسر ۱۴۸
کھوکھلااوربے ہنگم انسان(شخصیت ) ۱۵۱
ہوس کے عذاب ۱۵۵
دنیا اپنے خواہشمند کے لئے ایک وبال جان ۱۵۷
خواہشات کی پیروی کے بعد انسان کی دوسری مصیبت ۱۶۱
دنیا انسان کا ایک سایہ ۱۶۲
روایات کی روشنی میں عذاب دنیا کے چند نمونے ۱۶۳
آخرت میں انسان کی سرگردانی وپریشا ں حالی ۱۶۵
۲۔اسکی دنیا کو اسکے لئے مزین کردوںگا ۱۶۷
دنیا کا ظاہر اور باطن ۱۶۷
دنیا اورآخرت کا تقابلی جائزہ ۱۷۱
کلا م امیر المومنین میں دنیاکا تذکرہ ۱۷۲
آپ کے ایک خطبہ کا ایک حصہ ۱۷۵
ب۔دنیا کاظاہری رخ(روپ) ۱۸۶
دنیاوی زندگی کے ظاہر اور باطن کا موازنہ ۱۸۸
دنیا کے بارے میں نگاہوں کے مختلف زاوئے ۱۹۰
طرز نگاہ کا صحیح طریقہ کار ۱۹۶
نفس کے اوپر طرز نگاہ کے اثرات اورنقوش ۱۹۸
محبت یا زہددنیا ۱۹۸
حب دنیا ۱۹۹
حب دنیا ہر برائی کا سر چشمہ ۱۹۹
حب دنیا کا نتیجہ کفر ؟ ۲۰۰
حب دنیا کے نفسیا تی اور عملی آثار ۲۰۲
۱۔طولانی آرزو ۲۰۲
۲۔دنیا پر اعتماد اور اطمینان ۲۰۳
۳۔دنیاوی زندگی کو آخرت پر مقدم کرنا ۲۰۵
آخرت کی نعمتوں کے لئے دنیا ہی میں عجلت پسندی ۲۰۸
زود گذر ۲۰۹
روایات کا تجزیہ ۲۱۷
با طن بیں نگاہ ۲۲۷
زہد ۲۳۰
زاہد ،صابر اور راغب۔ ۲۳۳
زہد،تمام نیکیوں کا سرچشمہ ۲۳۴
زہد کے آثار ۲۳۶
۱۔آرزووں میں کمی ۲۳۶
۲۔دنیاوی تاثرات سے نجات اورآزادی ۲۳۸
۳۔دنیاپرعدم اعتماد ۲۴۰
دنیا ایک پل ۲۴۵
اسباب ونتائج کا رابطہ ۲۴۶
زہد وبصیرت ۲۴۶
زہدو بصیرت کا رابطہ ۲۴۷
مذموم دنیا اور ممدوح دنیا ۲۵۰
دنیا سے بچائو ۲۵۳
ب :ممدوح دنیا ۲۵۳
۱۔دنیا آخرت تک پہو نچانے والی ۲۵۴
۲۔دنیا مومن کی سواری ۲۵۹
ج۔اسکے دل کو اسکا دلدادہ بنا دونگاجرم اور سزا کے درمیان تبادلہ ۲۶۴
دنیاداری کے دورخ یہ بھی! ۲۶۵
دل کے اوپر خدائی راستوں کی بندش کے بعض نمونے ۲۶۷
۱۔غبار اور زنگ ۲۶۷
۲۔الٹ،پلٹ ۲۶۷
۳۔زنگ یامُہر ۲۶۷
۴۔مہُر ۲۶۸
۵۔قفل ۲۶۸
۶۔غلاف ۲۶۸
۷۔پردہ ۲۶۹
۸۔سختی ۲۶۹
۹۔قساوت ۲۷۰
دنیا قید خانہ کیسے بنتی ہے ؟ ۲۷۰
اہل دنیا ۲۷۲
دنیا کابہروپ ۲۷۴
تیسری فصل ۲۷۷
جو شخص خداوند عالم کی مرضی کو ۲۷۷
اپنی خواہشات کے اوپر ترجیح دیتا ہے ۲۷۷
مرضی خدا کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا ۲۷۹
افکار کی تبدیلی میں اسلامی اصطلاحات کا کردار ۲۸۰
فقرواستغنا اور اقدار کے اسلامی اصول ۲۸۱
دور جاہلیت کا نظام قدروقیمت ۲۸۲
قدروقیمت کا اسلامی نظام ۲۸۴
اسلامی روایات میں استغنا کا مفہوم ۲۸۵
اقدار کے نظام میں انقلاب ۲۸۹
نفس کی بے نیازی ۲۹۲
بے نیازی(استغنا)کے ذرائع ۲۹۴
۱۔یقین: ۲۹۴
۲۔تقویٰ: ۲۹۵
۳۔شعور : ۲۹۶
حیات انسانی میں بے نیازی کے آثار ۲۹۸
۲۔ضمنت السمٰوات: ۲۹۹
توفیق ۳۰۰
عالم غیب اور عالم شہود(ظاہر)کے درمیان رابطہ ۳۰۵
حرکت تاریخ کے سلسلہ میں غیبی عامل کا کردار ۳۰۸
پہلا مرحلہ ۳۱۲
دوسرا مرحلہ ۳۱۳
تیسرا مرحلہ ۳۱۳
غیبی عامل،مادی عوامل کا منکر نہیں ۳۱۴
تقویٰ اور رزق کا تعلق ۳۱۴
تقویٰ کی بنا پر نجات پانے والے تین لوگوں کا واقعہ ۳۱۸
۳۔کففت علیہ ضیعتہ ۳۲۰
ہدایت کے معنی ۳۲۲
ﷲ بندہ کو بربادی اورضائع ہونے سے کیسے بچاتا ہے ؟ ۳۲۳
بصیرت اور عمل ۳۲۵
بصیرت اور عمل کا رابطہ ۳۲۶
۱۔ عمل صالح کا سرچشمہ بصیرت ۳۲۶
۲۔بصیرت کی بنیاد عمل صالح ۳۲۹
دوسرا رخ ۳۳۱
بے عملی سے خاتمۂ بصیرت ۳۳۲
فقدان بصیرت برے اعمال کا سبب ۳۳۶
خلاصۂ کلام ۳۳۸