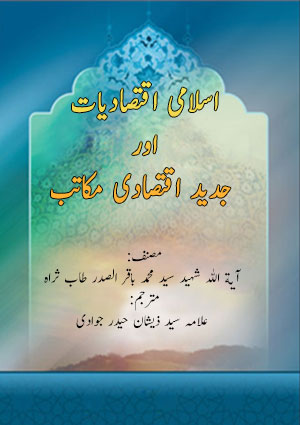شہید اسلام آیت اللہ سید محمد باقر الصدر طاب ثراہ
کی معرکۃ الآراء کتاب
اسلامی اقتصادیات
اور
جدید اقتصادی مکاتب
شناسنامہ کتاب
نام کتاب:اسلامی اقتصادیات اور جدید اقتصادی مکاتب
مصنف: آیة اللہ شہید سید محمد باقر الصدر طاب ثراہ
مترجم: علامہ سید ذیشان حیدر جوادی
کمپوزنگ : زیر نظر شبکہ امامین الحسین علیھما السلام
پیشکش : امام حسین علیہ السلام فاونڈیشن
فہرست
گفتار مترجم (اقتصادی مسئلہ کی اہمیت) 9
اقتصادی کشمکش کے اسباب 13
مساوات یامواسات 18
اقتصادی تاریخ کا ایک خاکہ 28
فنون لطیفہ 37
آثار قدیمہ 38
مخطوطات ومطبوعات 39
سپلائی اور ڈیمانڈ 40
مارکس اور سرمایہ داری 43
مارکس ازم پر ایک نظر 46
سرمایہ داری پر ہماری ایک نظر 50
آزادی؟ 60
اسلامی معاشرہ(معیارِ قیمت) 65
تقسیم 69
انفرادی ملکیت 71
سرمایہ داری کا فساد 73
ذخیرہ اندوزی 75
سود 76
بینک 78
حیات وکائنات 81
انشورنس 85
فیملی پلاننگ 87
کلمۂ مؤلف (برائے طبع دوم) 103
ابتدائیہ 125
مارکسیت کے ساتھ 132
نظریۂ مادیت تاریخ 133
یگانہ محرک تاریخ 135
اقتصادی محرک یا تاریخی مادیت 136
تاریخی مادیت اور واقعیت 140
طریقۂ جدلیت 145
تاریخی جدلیت کی کمزوری 147
دلیل ونتیجہ کا تضاد 149
مادیت تاریخ کی روشنی میں 151
مادیت تاریخ(ایک عام نظریہ کی حیثیت سے) 155
مادیت تاریخ کے دلائل 156
فلسفی دلیل 156
تجربیاتی دلیل 166
کیا مارکسیت پوری تاریخ پر محیط ہے 176
پیداواری قوتوں کا ارتقاء اور مارکسیت 180
فکر اور ماکسیت 183
دین 185
ب:فلسفہ 189
فلسفہ اور طبیعی علوم 195
فلسفہ اور طبقاتی نزاع 196
تجربیاتی علوم 201
مارکسی طبقیت 206
مارکسیت اور طبیعی عوامل 209
مارکسیت اور فنون لطیفہ 213
مارکسی نظریہ کے تفصیلات 217
غلام معاشرہ 224
جاگیردار معاشرہ 226
وقت انقلاب پیداوار میں ترقی نہ ہوئی تھی 229
اقتصادی حالات نے ترقی نہیں کی 230
آخرکار سرمایہ دار معاشرہ پیداہوگیا 232
مارکس کا اعتراف 238
سرمایہ دار نظام کے قوانین 243
قیمت کی بنیاد عمل 244
مارکس نے اقتصادی بنیادکس طرح قائم کی؟ 247
مارکسی بنیاد پرنقدونظر 249
مارکسی مذاہب 272
اشتراکیت واشتمالیت کیاہیں؟ 273
مارکسی مذہب پر عمومی تنقید 275
اشتراکیت 276
اشتمالیت 286
ارکان سرمایہ داری 293
(1)سرمایہ دار تنظیم کا عملی قوانین سے ارتباط 296
(3)سرمایہ داری کے علمی قوانین کا تنظیمی رنگ 298
(4)مذہبی سرمایہ داری کے افکار واقدار پر نقد ونظر 303
حریت مصالح عامہ کا وسیلہ ہے 307
آزادی پیداوار کی زیادتی کا ذریعہ ہے 311
حریت انسان کا فطری حق ہے 313
اسلامی اقتصادیات کے ارکان 321
1۔اسلامی اقتصادیات کا خاکہ 323
(1)مرکب ملکیت 324
(2)محدود آزادی 326
(3)اجتماعی عدالت 330
(2)اسلامی اقتصادایک مجموعہ کا جزء ہے 334
عقیدہ، مفاہیم واقدار ، جذبات واحساسات 336
(1)اقتصادکا ارتباط عقیدہ سے 338
(2)اقتصادیات ومفاہیم 339
(3)اقتصادیات وجذبات 340
(4)اقتصادیات اور مالی سیاست 340
(5)اقتصادیات اور سیاسی نظام 341
(6)سودخوری اور اجتماعی عدالت 341
(7)انفرادی ملکیت اور جہاد 342
(8)اقتصادیات اور تغریرات 345
(3)اسلامی اقتصاد کا عمومی اسلوب 345
طبیعی علوم اس مسئلہ کے حل کرنے سے قاصر ہیں 350
مادیت تاریخ اور مشکل 352
اسلامی اقتصادکوئی علم نہیں ہے 358
(5)تقسیم پیداوار سے الگ شکل میں 362
(6)اقتصادی مشکلات اور ان کا حل 371
طریق تقسیم(تقسیم میں عمل کا حصہ) 373
تقسیم میں ضرورت کا حصہ 377
ضرورت اسلام واشتمالیت کی نظر میں 378
ضرورت اسلام واشتراکیت کی نظر میں 378
ضرورت اسلام وسرمایہ داری کی نظر میں 380
انفرادی ملکیت 381
ملکیت بھی ذریعۂ تقسیم ہے 383
تبادلہ 385
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
گفتار مترجم(اقتصادی مسئلہ کی اہمیت )
ٹھنڈے دل اور گہری نظرسے دیکھاجائے تو اقتصادی مسئلہ انسانی زندگی میں ایک نبیادی حیثیت رکھتاہے۔یہ مسئلہ کل کے انسان کے لئے اتنااہم نہیں تھا جتنا آج کے انسان کے لئے اہم ہوگیاہے۔''ضرورت ایجاد کی ماںہے''کل تک انسان کے ضروریات محدود تھے اور کائنات کی فیاضیوں پر انسان کی جابرانہ دست درازیوں کابھی اثرنہیں ہواتھا۔ اس لئے ہرشخص اپنی ضرورت کے مطابق سامان فراہم کرلیاکرتاتھالیکن آج کا انسان اور آج کے ضروریاتعَیَاذاًبِاللّٰهِ
ہرشخص کی خواہش ہے کہ پوری کائنات پربلاشرکت غیرے قابض ہوجائے اور ہر ایک کی تمنا ہے کہ پورے عالم کو ضروریات زندگی میں شامل کرلے۔ایسے حالات میں دماغی کشمکش اور ذہنی انحطاط کا پیداہونا ناگزیر تھا جیساکہ ہوا !
اقتصادی مسئلہ کی اہمیت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایاجاسکتاہے کہ کسی بھوکے سے
پوچھا گیا:''ایک اور ایک''تواس نے کہا دو روٹیاں۔اس مثل کو ہمارے ملک میں ہمیشہ مثل ہی کادرجہ دیاگیاہے اور اس کی پشت پر کام کرنے والے فلسفہ کو درخورِ اعتناء نہیں سمجھاگیا۔ حالانکہ یہ واقعہ اقتصادی مسئلہ کی اہمیت کابہترین عکاس وترجمان ہے۔اس سے صاف اندازہ ہوتاہے کہ اقتصادی کشمکش انسان کے ذہن کو کس درجۂ انحطاط تک پہنچادیتی ہے اور اس کے افکار ونظریات میں کتنا تغیر پیداہوجاتاہے۔وہ علم ریاضیات کے مسلم مسائل ''ایک اور ایک دو''جیسے حسابات کو بھی صحیح طریقہ سے نہیں جوڑسکتااور ان میں بھی اپنی معاشی حالت کو شامل کر دیتاہے اور زبان حال سے یہ اعلان کرتاہے کہ معاشی اعتبار سے خوشحال انسان کی زبان وفکر اور ہوتی ہے اور معاشی بدحالی کے شکار انسان کی زبان وفکر اور ! وہ ایک اور ایک کو دوسمجھتاہے اور یہ دوروٹیاں۔
اس واقعہ کے خصوصیات پرگہری نظرڈالی جاتی ہے تو دور حاضرکے جملہ نقائص وعیوب بیک وقت نگاہوں کے سامنے آجاتے ہیں۔دورِ حاضر میں علم معاشیات کی اتنی اہمیت اور کمیونزم وسوشلزم کے اتنے چرچے اس لئے نہیں ہیں کہ انسان نے کوئی نئی حقیقت دریافت کرلی ہے اور وہ اپنے انکشاف کا ڈھنڈوراپیٹنا چاہتاہے بلکہ یہ سارا شورقیامت صرف اس لئے ہے کہ معاشی مشکلات نے اس کے دل ودماغ کو معطل کر دیاہے اور وہ روٹی، کپڑے سے ہٹ کر کچھ سوچنے کے لئے تیارنہیں ہے۔اس بوکھلاہٹ میں کبھی مذہب کو براکہتاہے،کبھی اخلاقی اقدار کو قابل مذمت ٹھہراتاہے۔کبھی تہذیب وتمدن کا مذاق اڑاتا ہے ،کبھی دولت وسرمایہ کی مخالفت میں کھوکھلے اور بے جان نعرے بلندکرتاہے اور اس حقیقت سے بالکل غافل ہوجاتاہے کہ یہ ہنگامے مسئلہ کا واقعی حل نہیں ہیں۔مرض کا پروپیگنڈا علاج نہیں ہواکرتا۔حالات کا رونا انقلاب نہیں لاسکتا۔کھوکھلے نعرے جاندارنہیں ہوسکتے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کشمکش کے پیچھے کام کرنے والے عناصر کا پتہ لگائیں اور ان کا قلع قمع کرنے کی کوشش کریں۔ہم نے یہ تواندازہ کرلیاہے کہ معاشی بدحالی کے پیچھے چند
افراد کی ہوس رانی اور ان کے بیجااستحصال کا دخل ہے لیکن یہ بھول گئے کہ استحصال کی جڑیں سرمایہ داری میں نہیں بلکہ نفس کی خباثت میں ہیں نتیجہ یہ ہواکہ سرمایہ داری کے خلاف اتنا بڑاپرزور نعرہ بلند کیاکہ مذہب کی تہذیب نفس کی تبلیغ بھی نقارخانہ میں طوطی کی آواز ہوگئی اور دین کی بے معنی مخالفت نے خباثت نفس کو بڑھنے اور پنپنے کا موقع دے دیا اور ہر نعرہ اپنے ساتھ ایک نئی مصیبت لے کر سامنے آیا۔مرض بڑھتاگیاجوں جوں دواکی۔
اقتصادی کشمکش نے جہاں انسان کے ذہن کو فکر ونظر کے میدان میں ماؤف ومفلوج بنادیاہے وہاں چند مصیبتیں اوربھی پیداکی ہیں جن سے نجات حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہوگیاہے۔
پہلی مصیبت یہ ہے کہ سماج میں ظلم عام ہوگیاہے اور معاشرہ دوطبقوں میں تقسیم ہوگیاہے۔ایک طبقہ کاخ وایوان کی زینت ہے اور دوسرا ڈیروں اور چھولداریوں کی رونق۔ جذبۂ انتقام کی فراوانی کایہ عالم ہے کہ پہلا طبقہ دوسرے طبقہ کے خون کا آخری قطرہ تک چوس لینا چاہتاہے اور دوسرا طبقہ پہلے طبقہ کی شہ رگ حیات تک قطع کر دینا اپنا فرض اولین سمجھتاہے۔عزت ودولت کے واقعی اقدار کے ساتھ انتقام کے تصورمیں بھی فرق آگیاہے اور ہر شخص اپنے علم کو انتقام کا نام دے کر اس میں حسن پیداکررہاہے۔ذہنی بوکھلاہٹ کسی طبقہ کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیتی کہ اس طبقاتیت کی نبیادیں کہاں ہیں اور معاشرہ میں اتناشدید ووسیع ظلم کہاں سے آگیاہے؟
اسی اقتصادی کشمکش نے افراد معاشرہ کو مختلف لاعلاج امراض کا شکار بھی بنارکھا ہے دواؤں کی فراوانی اورایجادات وانکشافات کی کثرت بھی مرض کا علاج نہیں کرسکتی۔ہر دوا ایک دولت کی طلبگار ہے اور ہر علاج ایک بڑے سرمایہ کامتقاضی غریب غربت کی نبیاد پر علاج سے قاصر ہے اور امیرامارت کی نبیاد پر غربت کو قابل توجہ نہیں سمجھتا۔روٹی،کپڑے کے سوال سے آسودہ ڈاکٹراس مریض کی طرف رخ بھی نہیں کرتاجس
سے خاطرخواہ آمدنی کی امید نہ ہو۔نتیجہ یہ ہوتاہے کہ مریض توراہی عدم ہوجاتاہے لیکن پسماندگان میں ایک عظیم ذہنی کشمکش چھوڑجاتاہے۔وہ ڈاکٹر کی لاپرواہی کے پیش نظریہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ لاپرواہی دولت اور سرمایہ کے نتیجہ میں پیداہوئی ہے۔ان کا ذہن اس طرف جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ دولت سرمایہ کے علاوہ غلط تربیت اور نا مناسب نفسیات بھی سیکڑوں برائیوں کی جڑ ہیں او ر اس کا واضح اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کے بجائے صنف اور فرد کے بجائے جماعت سے انتقام لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ذاتی عناد جماعتی اختلاف کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور سماج مزید مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے۔
اقتصادی بدحالی نے دور حاضر کے انسان پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اس سے دو عظیم طاقتیں سلب کر لی ہیں۔ انسان کے پاس دو ایسے جو ہر تھے جن پر وہ اپنی پوری کائنات قربان کر سکتا تھا ایک اس کا مذہب اور اس کی آبرو۔دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں قربانیوں کے قصے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان نے ان دو بے بہا جواہرات پر کتنی بھینٹ چڑھائی ہے اور کس قدر قربانیاں دی ہیں لیکن معاشی بد حالی نے اسے اس منزل پر پہنچا دیا کہ وہ آبرو کو ایک ڈھونگ اور مذہبی رسومات کی بجا آوری کو تضییع اوقات سمجھتا ہے ۔ ایک مسلمان کی نظر میں ایک گھنٹہ مسجد میں بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ایک گھنٹہ بازار میں بیٹھنا ہے۔ حج پر رقم خرچ کرنے سے بہتر قومی فنڈ میں دولت لگا دینا ہے ۔ عزت و آبرو جیسے تصورات سرمایہ داری اور جاگیر داری کے فرسودہ خیالات کا درجہ حاصل کر چکے ہیں ۔ عورتیں دولت کے پیچھے ہوس پرستوں کی جنسی پیاس کا بجھا دینا اپنے لئے باعث فخر سمجھنے لگی ہیں اور اس طرح انسان سے اس کے بیش بہاجواہرات تقریباً سلب ہو چکے ہیں۔
یہ حالات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اقتصادی مسئلہ صرف روٹی کے میدان تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کی وسعتیں اخلاقیات ، نفسیات، مذہبیات، اجتماعیات
اور فلسفی افکار کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشی انتقام سے بھرپور انسان فکری کجروی کی بنیاد پرمرض کے واقعی اسباب کو تلاش کرنے سے عاجز ہو گیا ہے اور ذہنی دیوالیہ پن ہر شے کی پشت پر اسی بد حالی کو کار فرما دکھاتا ہے ۔ اس کے لئے یہ سوچنا تقریباً نا ممکن ہو گیا ہے کہ روٹی کپڑے کے علاوہ کچھ اور عوامل ومحرکات بھی ہیں جن کی اصلاح معاشی اصلاح سے ماورا ہے اور جن کی اصلاح کے بغیر سماج کی اصلاح نا ممکن ہے۔
اقتصادی کشمکش کے اسباب
عالم اقتصادیات میں جب سے اونچ نیچ کی طبقاتی کشمکش پیدا ہوئی ہے اسی وقت سے انسان نے اس کشمکش کو دور کرنے کے ذرائع پر غور کرنا شروع کیا ہے لیکن عجیب اتفاق ہے کہ سیکڑوں اور ہزاروں عقلاء کی عقل صرف ہونے کے باوجود آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا بلکہ یہ کہنا بھی بالکل بیجا نہ ہوگا کہ جیسے جیسے علاج معاش کیا گیا مرض میں اضافہ ہوتا گیا اور ہر دور اپنے ساتھ ایک نیا درد لے کر آئی ۔
دور حاضر کے انسان کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ معاشی کشمکش سے سرمایہ داری پیدا ہوتی ہے اور سرمایہ داری ذاتی ملکیت کا نتیجہ ہے اس لئے ذاتی ملکیت کے سلسلے کو ختم کر دینا ہچائے ۔ اس کے ختم ہوتے ہی جملہ مشکلات حل ہو جائیں گے اور دنیا ایک نئے صالح اقتصادی نظام سے ہمکنار ہو جائے گی ۔ لیکن غور وفکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے پیچھے بھی انتقامی جذبہ کا م کر رہا ہے۔ انسان نے سرمایہ داروں کے مظالم کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ ان کے خاتمہ کے بعد ہر کشمکش ختم ہو سکتی ہے اور یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی
کہ بنیادی طور پر سرمایہ داری کا جذبہ ابھرتا کہاں سے ہے؟ سرمایہ دار ظلم و تشدد کو کیوں پسند کرتا ہے ؟ وہ دولت میں روز افزوں اضافہ کیوں چاہتا ہے اور اس غور نہ کرنے کا سبب صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کے فلسفہ میں دنیا کا آخری محرک و عامل اقتصاد ہے ۔ اخلاقیات ، فلسفہ، افکار کی کوئی بنیادی حیثیت نہیں ہے۔حالانکہ یہ خود ایک بے بنیاد فکر ہے ۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقتصادی حالات انسانی افکار و نظریات کو متاثر کر دیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اقتصادیات سے ہٹ کر ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔اس کی بہترین دلیل آپ کو گذشتہ مثال میں مل سکتی ہے ۔ اقتصادیات نے بھوکے کو دو روٹیاں کہنے پر مجبور کر دیا لیکن شدت گرسنگی کے باوجود وہ ایک اور ایک کے مجموعہ کو تین روٹیاں نہیں کہہ سکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاضیات کی اپنی ایک بنیاد ہے جس سے اقتصادیات کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔ اقتصادیات ان افکار پر اثر انداز ہو کر ان کے فیصلوں کو مخلوط اور مبہم بنا دیتے ہیں لیکن انہیں بدل نہیں سکتے ۔ریاضیات ہی کی طرح فلسفہ کے دیگر الٰہیاتی اور مذہبی مسائل ہیں جن پر اقتصادیات کی اثر اندازی مسلم ہے لیکن اقتصادیات کی بنیادی حیثیت مسلم نہیں ہے ۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اہم بنیادی مسائل پر غور کرتے وقت اقتصادیات کے علاوہ دوسرے اساسی تصورات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے تاکہ ان مسائل کے حل کرنے میں سہولت بھی ہو اور مرض کے ساتھ اس کی جڑوں کا بھی اندازہ ہو جائے ۔
اس سلسلے میں اس مثال کا ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ ایک فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے فقیر سے یہ سوال کیا گیا کہ تم فقر وفاقہ کی زندگی کیوں گذار رہے ہو؟ تمہارا قیام فٹ پاتھ پر کیوں ہے؟تو اس نے بر جستہ جواب دیا کہ ملک کے جملہ مکانات اور سارے محلے پر سرمایہ داروں نے قبضہ کر لیا ہے تو اب ہم غریبوں کا ٹھکانا فٹ پاتھ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے ؟ مطلب یہ ہے کہ اگر سرمایہ داروں نے مکانات پر قبضہ نہ کیا ہوتا تو ہم بھی انہیں مکانات میں ہوتے جن میں یہ لوگ زندگی گذار رہے ہیں۔
انسانی نفسیات کی یہی کمزوری ہے جس کا علاج کسی قانون نے نہیں کیا۔ معاشی اونچ نیچ کو تو محل بحث قرار دیا لیکن اس جذبہ کو یکسر نظر انداز کر دیا جو اس فقیر کے دل میں کروٹیں لے رہا ہے اور جن کی بنا پر یہ بھی محلوں کے خواب دیکھ رہا ہے ۔ ایسا خواب جو کسی وقت بھی شرمندۂ تعبیر ہو سکتا ہے لیکن نتیجہ میں ایک نئی کشمکش ہی لا سکتا ہے ۔ کشمکش کا علاج نہیں لا سکتا یعنی محل کا رہنے والا فٹ پاتھ پر تو آ سکتا ہے لیکن فٹ پاتھ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ۔
اس تجزیہ پر نظر کرنے کے بعد ایک سطحی ذہن بہت جلد اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ معاشی مسئلہ کا پورا حل فٹ پاتھ کے خاتمہ اور معاشی مساوات میں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشی میدان میں مساوات کا تصور انتہائی خوش کن اور مہمل ہے اس کی کسی واقعیت کا خیال بھی دور از عقل بات ہے۔معاشی مساوات کا تصور ایسا ہی ہے جیسے کہ تمام انسانوں کے بیک وقت گورے یاکالے یا لمبے یا کوتاہ قامت ہوجانے کا تصور ہوکہ جس طرح یہ ناممکن اور محال ہے اسی طرح وہ بھی''خیال است ومحال است وجنوں''کا مصداق ہے۔قرآن مجید نے اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا تھاکہ تخلیقی میدان میں اختلاف رنگ ونسل ہماری نشانی ہے اور معاشی میدان میں اختلاف طبقات ہماری مقرر کی ہوئی فطرت کا نتیجہ ۔''من آیاتہ اختلاف السنتکم والوانکم''''نحن قسمنآ بینہم معیشتہم ورفعنآ بعضہم فوق بعض درجآت''
فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے معاشی طبقاتیت کو کسی عزت وذلت کا معیار نہیں بنایا اور تم نے دولت وغربت کو ہی عزت وذلت کا معیار بنالیاہے۔ہمارا کھلا ہوا اعلان ہے کہ انسانیت کو مختلف شعوب وقبائل،مختلف الوان والسنہ میں تقسیم کرنے کاکام ہماراہے۔ تمہاری عظمت وبزرگی کاراز اس تقسیم وتفریق میں نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمہارے ذاتی تقویٰ اور کردار سے ہے۔تخلیق پر فخرکرنادلیل عاجزی اور ذاتی کسب وکار پرمباہات کرنا دلیل ہمت مرداں ہے۔
اس مقام پر یہ نہ سوچاجائے کہ جب طبقاتی تقسیم کاکام خود خالق فطرت نے انجام دیاہے توکسی سرمایہ دار پر ظلم کا الزام رکھنے کے کیا معنی ہیں؟یہ تصور توہر ظالم و جابر کی بد اعمالی کا بہترین بہانہ ہے اور اس کے ذریعہ توہر انسان دائرہ مذہب میں رہ کر غصب وسلب، ظلم وستم،قہرواستبداد سے کام لے سکتاہے اس لئے کہ یہ تقسیم وتفریق قانون کے میدان میں نہیں ہے بلکہ تخلیق کی منزل میں ہے اور تخلیق کی منزل قانون کے میدان سے الگ ہوتی ہے۔تخلیقی اعتبار سے طبقاتیت ناگزیر ہے اور طبقاتیت کے نتیجہ میں معاشی طبقاتیت بھی لازم ہے لیکن قانونی اعتبار سے اس طبقاتیت کو صرف کرنے کا کہاں تک اختیار ہے اس کا کوئی تعلق تخلیقی طبقاتیت سے نہیں ہے۔
فلسفۂ جدید کی روشنی میں یوں کہاجائے کہ ہماری زمین ابتداء میں آفتاب سے متصل اسی کا ایک جزوتھی۔اس میں اتنی ہی حرارت وتمازت پائی جاتی تھی جتنی آفتاب میں پائی جاتی ہے۔وہ اسی سرعت رفتار سے چکر لگایاکرتی تھی جس سرعت سے آفتاب کی گردش ہوتی ہے لیکن مدتوں کے بعد ایک وہ وقت بھی آیاجب کسی دست غیب کی جنبش کے سہارے آفتاب کا یہ ٹکرااسے داغ فراق دے کر رخصت ہوگیا۔فطرت نے اسے کروڑوں میل دور جا پھینکا ۔اب اس میں نہ تو وہ توانائی رہ گئی ہے نہ رعنائی۔نہ وہ چمک رہ گئی ہے نہ دمک نہ وہ تپش رہ گئی ہے نہ سوزش نہ وہ حرارت باقی رہی ہے نہ تمازت۔ایک نئی فضا ہے اور ایک نیاماحول نتیجہ یہ ہواکہ زمین اپنے نئے ماحول کے اثر سے ٹھنڈی ہونے لگی اور ٹھنڈی ہوتے ہوتے ایک دن اس منزل پر آگئی کہ اس میں جاندار سکونت اختیار کرسکیں۔چنانچہ خالق فطرت نے اسے انسانوں اور حیوانوں کا مسکن بنایا۔اب بچوں کا گہوارہ ہے تو یہی زمین اور جوانوں کا میدان ہے تو یہی زمین،بوڑھوں کی قبر ہے تو یہی زمین اور دانۂ گندم کی تربیت گاہ ہے تو یہی زمین آغاز وانجام کا یہ تقاوت بھی قابل صدعبرت ہے:
آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم ہوگئے خاک،انتہا یہ ہے
جاندار کا روئے زمین پر قدم رکھنا تھاکہ ہر حصۂ زمین نے اس کی تخلیق پر اثرکرنا شروع کر دیا۔آفتاب سے قریب تر حصہ کا اثر اور ہوا اور آفتاب سے دورتر حصہ کا اثر اور۔ چاندگہن، سورج گہن نے اور بھی تغیرات وتصرفات پیدا کئے۔سطح وعمق کی طبقاتیت نے اور گل کھلائے اور نتیجہ میں فطرت کا ہفت رنگ مرقع انسان کی صورت میں ہمارے سامنے آگیا۔ زمین کے اندرونی اختلاف پرایک جملہ تغیرآب وہوا، قرب وبعد، خط استوا، عروج وزوال آفتاب، اتصال وانفصال قلب شمالی وجنوبی،جزرومدبحار کا ہوااور نتیجہ میں زمینی مخلوقات مختلف رنگ ولون کا شکار ہوگئی اور یہ بات ناگزیر ہوگئی کہ زمین کے رہنے والے انسان مختلف طبقات اور مختلف خطوں کے اعتبار سے اپنی استعداد وصلاحیت وقابلیت میں بالکل مختلف ہوں اور اگراس پرنسلی اثرات کا اضافہ ہوجائے تو یہ اختلاف اور بھی شدید تر ہوجائے جس کے بعد یہ بات یقینی ہوجاتی ہے کہ اگر معاشیات کے میدان میں انسانی جدوجہد اور ذاتی محنت ومشقت کو بھی معیار بنایاجائے گاتو طبقات کا پیدا ہونا ضروری ہوگا۔ نہ ہر شخص کی طاقت برابر ہوگی نہ ہر شخص کا حوصلہ اور جب طاقت وحوصلہ میں یکسانیت نہ ہوگی تونتیجہ میں بھی یکسانیت ناممکن ہوگی۔
اسلامی احادیث میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیاگیاہے:
لایزال الناس بخیر ماتضا ضلوافان تساو واهلکوا
''جب تک معاشرہ میں باہمی تفاوت باقی رہے گی خیر بھی باقی رہے گا اور جب یہ تفاوت مساوات سے بدل جائے گا معاشرہ ہلاک ہوجائے گا۔''
اس لئے کہ تفاوت میدان عمل میں آگے بڑھنے کی دعوت دیتاہے۔نئی نئی ایجادات کی طرف متوجہ کرتاہے اور مساوات کا تصور غفلت وبے حسی کی بنیاد ہے۔تفاوت ضروری ہے اور مساوات مہمل۔
مساوات یامواسات
اقتصادی دنیا میں مساوات کے نعرے اتنے زیادہ بلند ہوئے ہیں کہ اب کانوں کو ان آوازوں سے نفرت ہونے لگی ہے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگیاہے کہ اگر معاشی برابری انہیں نعروں کا نام ہے توہماری عدم مساوات ہی بھلی ہے۔کم از کم چین سے زندگی گذارنے کا امکان تورہ جاتاہے۔دور حاضر میں اقتصادی میدان میں ایک ہی منظم نظریہ ہے جو ہر ملک میں ترقی بھی کررہاہے اور اسے خوش آمدیدبھی کہاجارہاہے۔یعنی''نظریۂ اشتراکیت''سرمایہ داری اوردوسرے معاشی نظریات اپنی پشت پرکوئی منظم فکر نہیں رکھتے۔ان کی بنیاد''اقتصادی آزادی''پر ہے اور اسی کے تحت وقتی ضروریات کے مطابق قوانین ڈھال لئے جاتے ہیں۔
اشتراکیت کی ابتدائی مقبولیت کا راز اس کا نعرۂ مساوات ہی ہے جس پرتمام غریب ومسکین،فقیرولاوارث،کسان اور مزدور افراد لبیک کہنے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ہر ایک کے ذہن میں حسین مستقبل کا خواب گردش کرنے لگتاہے۔اب ہمارے دروازے موٹرکھڑارہے گا۔ہم بنگلہ میں رہیں گے۔ہماری غذائی صورت حال بہتر ہوجائے گی۔ہماری تعلیم اعلیٰ پیمانہ پرہواکرے گی وغیر ہ ان بیچاروں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ مساوات کے یہ معنی ہرگزنہیںہیں۔یہ مساوات صرف لغت کے حدود تک محدود ہے۔ اقتصادی میدان میں مساوات کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی محنت کا حق نہ ماراجائے۔جو جتنی پیداوار میں حصہ لے اسے اتنی اجرت دی جائے۔مزدوری کا معیار محنت کو قرار دیاجائے۔
کسی ایک طبقہ کو ایسا جاگیرداریاسرمایہ دار نہ بننے دیاجائے کہ دوسرے غریب طبقہ کی قسمت اس کی جوتیوں کے تلے سے ٹانک دی جائے اور اس کی ترقی پستی سب سرمایہ دار کے رنج ومسرت سے وابستہ ہو۔دوسرے الفاظ میں اشتراکی مساوات ایک غیر طبقاتی نظام کا نام ہے جس میں سماج دوحصوں میں تقسیم نہ ہوسکے اور سب اپنی اپنی محنت کی کمائی کھائیں۔جس میں جتنی محنت کی صلاحیت اور سوجھ بوجھ ہووہ اتنا ہی پیداکرسکے اور ویسی ہی زندگی گذار سکے۔ حکومت ذہانت وہوش مندی اور خوشحالی،محنت ومشقت کا نتیجہ ہو۔پیدائشی زمیندار یاوراثتی جاگیردار صفحۂ ہستی سے نیست ونابود ہوجائیں۔
تھوڑے عرصہ کی بات ہے کہ میرے ایک کرم فرماروس کے ایک ثقافتی دورے سے واپس آئے تو انہوں نے ایک ایٹ ہوم کے موقع پرانٹرویو دیتے ہوئے روس کی اشتراکیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا:
وہاں خاندان بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔اس لئے نہیں کہ وہاں ہندوستان جیسی کوئی پلاننگ چل رہی ہے اور دس دس روپیہ پرنسل کشی ہو رہی ہے بلکہ اس نبیاد پر کہ وہاں پانچ سال تک کا بچہ ماں باپ کے ذمے رہتاہے، اس کے بعد اسے حکومت کے حوالے کر دیاجاتاہے۔اٹھارہ برس تک حکومت اس کی تربیت کرتی ہے اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی کام سے لگادیاجاتاہے۔ماں باپ کی ذمہ داریاں بڑی مختصر ہوتی ہیں۔وہ اپنے حالات میں مست ومگن رہتے ہیں۔انہیں صرف اپنے کاموں سے کام ہوتاہے اور باقی ذمہ داریاں حکومت کے سرہوتی ہیں۔
دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں کارکردگی میں عورت اور مرد کاکوئی امتیاز نہیں ہے بلکہ دونوں صنفیں برابر سے کام کرتی ہیں۔ہوٹلوں میں عام طور سے عورتیں ملازم ہوتی ہیں۔ نازک کاموں کے لئے عورتوں کو مقدم کیاجاتاہے اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں مردوعورت کا امتیاز برتاجاتاہو۔
سواریوں کا انتظام مفت ہے۔جو جہاں چاہے سفر کر سکتاہے۔کسی کرائے وغیرہ کا سوال نہیں ہے۔عمارتیں حسین اور خوبصورت ہیں۔لوگ خوشحال نظرآتے ہیں اور ہر وقت ایک غیر طبقاتی زندگی کانقشہ نگاہوں کے سامنے رہتاہے۔
''شروع شروع میں ذاتی ملکیت کا تصور مٹادیاگیاتھا لیکن بعد میں اپنی اپنی محنت کے اعتبار سے ذاتی ملکیت کا خیال قائم کر دیاگیا ہے۔فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے ملک میں ذاتی ملکیت کو فروخت کیا جا سکتا ہے ۔مکانات کو کرایہ پر اٹھایا جا سکتا ہے لیکن وہاں سے سب باتیں غیر ممکن ہیں اور اس سے ان کی زندگی پر کوئی خاص اثر بھی نہیں پڑتا ۔ وہ معاشی حالات کے اعتبار سے مطمئن ہوتے ہیں ۔ انہیں کسی خاص خرچ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اس کے لئے خرید وفروخت یااجارہ داری سے کام لیں۔تعلیم کا انتظام مفت ہے ضروری اسباب زندگی بے قیمت تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی کیا ہے ۔''
ایک اشتراکی ملک کا یہ لفظی نقشہ یقینا خوش رنگ بھی ہے اور خوش آئند بھی ۔لیکن اس مقام پر ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عالم انسانیت کے سکون و اطمیان اور انسانی ارتقاء کے لئے یہی شکل وصورت مناسب ہے تو چین اور امریکہ کو اس سے اختلاف کیوں ہے ؟ کیا چین ایک اشتراکی ملک نہیں ہے ؟ کیا امریکہ اپنے ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی نہیں چاہتا ؟ اوراگر یہ دونوں باتیں ہیں تو یہ با ہمی اختلاف کیوں ہے؟
کہا یہ جاتا ہے کہ چین انتہا پسند ہے اور روس روا دار امریکہ سرمایہ پرست ہے اور روس اشتراکی اس لئے ان کے نظریات میںشدید اختلاف پایا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نظریات ہی کے اختلاف کی کیا ضرورت ہے ؟بلکہ اس سے بالاتر انسانی زندگی کے لئے اصل نظریات وافکار ہی کی کیا ضرورت ہے ؟ جب چین اور امریکہ کی نظر میں فاسد نظریے سے بھی نظام مملکت استوار اور رعیت خوشحال ہو سکتی ہے تو انتہا پسندی یا سرمایہ داری کا کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چین کی نظر میں وہ آخری صورت نہیں
ہے جہاں تک انسان کو پہنچنا چاہئے اور نہ یہ وہ منزل ہے جہاں تک عوام کی ترقی ہونی چاہئے یا ان تمام باتوں کے باوجود نظریات کا اختلاف خود ایک قیمت رکھتا ہے جس کے ذریعے مستقبل میں پیدا ہونے والی غلط صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے ۔ جہاں روس میدان عمل سے پیچھے ہٹ کر صلح پر تیار ہو سکتا ہے اور چین اپنی انتہا پسند ذہنیت کی بنیاد پر یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی حال امریکہ کا بھی ہے وہ بھی ملک میں خوشحالی اور عوام میں رفاہیت چاہتا ہے لیکن اس طرز فکر سے متفق نہیں ہے جو اشتراکی روس کے ذہن میں پایا جاتا ہے۔ اس کے خیال میں انسان کو سرمایہ دارانہ نظام کا حامی ہونا چاہئے اور ملکی خوشحالی کو اسی نظام کے زیر سایہ پروان چڑھنا چاہئے۔ ذاتی ملکیت ہی پورے اقتصادی نظام کی بنیاد ہے اور شخصی آزادی ہی سے ملکی خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے۔
مقصد اور حالات کی یکسانیت کے باوجود نظریات کا اتنا شدید اختلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی ملک نے بھی اپنے طریق کار پر عمل نہیں کیا۔ہر ایک نے دستور میں کچھ اور اصول درج کئے ہیں اور عملی میدان میں کچھ اور طریق کار اپنایا ہے۔ اسلام اس بات کا شدید مخالف ہے۔اس کا نظریہ یہ ہے کہ جس قانون سے مقصد کی تکمیل نہ ہوسکتی ہو اور اس میں حالات کے اعتبار سے ترمیم وتنسیخ ضروری ہو اس قانون کو دستور کے صفحات سے محوکر دینا چاہئے۔
نظریاتی اختلاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نظریات ہی قانون کے رواج کا ذریعہ بنتے ہیں۔روسی اشتراکیت کا خیال ہے کہ عوام کی تھوڑی سی آزادی اور ان پر شدید دباؤ قانون کو رائج کر سکتاہے۔چینی اشتراکیت کا خیال ہے کہ تھوڑی سی آزادی اور معمولی سی ملکیت بھی انسان کے ذہن کو خراب کر سکتی ہے۔سرمایہ داری کا عقیدہ ہے کہ مقابلہ کے میدان میں مکمل آزادی ہی ملکی پیداوار اور عوامی خوشحالی کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ عمل کے میدان میں انسان کو مکمل آزادی ملنی چاہئے۔اسے ہر اس کام کا
اختیار ہونا چاہئے جس میں کوئی عقلی پہلو نکل سکتاہو اور اس کی انسانیت کوکوئی ٹھیس نہ لگتی ہو۔ اس کی نظرمیں قانون کے رواج کا واحد ذریعہ انسان کا فطری عقیدہ ہے۔عقیدہ وہ طاقت ہے جو حاکم ومحکوم دونوں پر دباؤ ڈال سکتی ہے اور احساس بندگی وہ اعجاز ہے جس سے سرکش انسان کو بھی مسخر کیاجاسکتاہے۔
روس کی موجودہ صورت حال یقینا اچھی ہے اور اقتصادی اعتبار سے اس کا انکار کرنا اپنے وجود اور آفتاب وماہتاب کی گردش سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔لیکن دیکھنا یہ ہے کہ روس یا چین کو یہ آسائش گیتی اوررفاہیت حال کیسے نصیب ہوئی ہے؟یہ صرف اس کے حسن انتظام اور دیانت داری کا کرشمہ ہے یااس کے پس منظرمیں کچھ قربانیاں بھی ہیں۔ حالات کا گہرا مطالعہ بتاتاہے کہ روس نے اس رفاہیت کی راہ میں تین قسم کی قربانیان دی ہیں۔آزادی کی قربانی،صنف کی قربانی اور مامتاکی قربانی۔
آزادی کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آغاز کار میں ایک آمرانہ نظام حکومت کے ذریعہ ذاتی ملکیت کایک لخت خاتمہ کر دیاتھا۔بعد میں چھوٹی چھوٹی ملکیتوں کے اعتراف کا سلسلہ شروع ہوااور اب ذاتی ملکیت کا بڑی حد تک اعتراف کرلیاگیاہے۔ ذاتی ملکیت کے محوکر دینے کا نتیجہ یہ ہواکہ ملک کے پاس ساری دولت جمع ہوگئی اور اس نے انتظام شروع کر دیا۔چھوٹے سرمایہ دار بھی اپنے مزدوروں کی زندگی کے خواہاں ہوتے ہیں اور بڑااسٹیٹ ڈکٹیٹر بھی عوام کی بقاچاہتاہے لیکن دونوں کے پیش نظریہ ضروری ہوتاہے کہ اس طرح زیادہ سے زیادہ رقم اپنی ذات پر صرف کرنے کا موقع ملے گا اور اپنے لئے آسائش کے بہتر سے بہتر سامان فراہم ہوسکیں گے۔ اس سلسلے میں کسی حاکم وآمر کی نیت پر شبہہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔صرف دیکھنا یہ ہے کہ اگر ابتدائی دور سے انسان کو اس کے فطری عقائد کی طرف متوجہ کر دیاجاتااور اسے خدائی نظام کا پرستار بنالیاجاتاتو اس آمریت کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔عوام کی آزادی بھی محفوظ رہتی اور حکومت کا کام بھی چلتارہتا۔جبر و
تشدد کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں انسان ازخود کام کرنے پر آمادہ نہ ہو، اور کام سے نفرت اسی وقت ہوتی ہے جب اس پر کوئی باطنی دباؤ نہیں ہوتا۔عقیدہ اس داخلی دباؤ کانام ہے جس کے بعد کسی جبروتشدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔بغاوتوں کے کچلنے کی ضرورت ضرور رہتی ہے لیکن یہ بغاوت کے بعدہوتاہے اور صرف باغی قوم کے ساتھ ہوتاہے اور اشتراکی نظام کے لئے ذاتی آزادی کے سلب کر لینے میں نیک نیت اور بدباطن سب ہی شریک ہیں۔کوئی اس آفت سے نجات نہیں پاسکتا۔
صنف کی قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اشتراکی ممالک میں انسان کی دونوں صنفوں کے کاندھے پر عمل کا بوجھ ڈالاگیاہے۔یہاں عورت کو اسی طرح کام کرناپڑتاہے جس طرح ایک مرد کرتاہے۔پردے کا تصور لغوہے۔ہوٹلوں میں عورتیں کام بھی کرتی ہیں اور تسکین نظرکا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔اختلاط درجۂ کمال پر ہے اور عورت ومرد دوکے بجائے ایک صنف نظر آتے ہیں۔ظاہر ہے کہ یہ بات ان افراد کے لئے توبہت اچھی ہے جن کے یہاں عزت وآبرو،غیرت وحیا،دورجاگیروسرمایہ کی پیداوار ہیں لیکن وہ لوگ جوان تقاضوں کو فطری سمجھتے ہیں،عورت کو عورت دیکھنا چاہتے ہیں اور مرد کو مرد،وہ کبھی ایسی قربانی پرتیارنہیں ہوسکتے۔ مذہب نے بندگی کے پردے میں یہ نکتہ بھی سمجھادیاتھاکہ ایک ایسا دستور حیات بھی ممکن ہے جہاں ہر صنف اپنی منزل پر رہے اور وہی رفاہیت حال پیدا ہوجائے جوان قربانیوں کے بعد پیداہوتی ہے۔عورت گھرکاکام انجام دیتی رہے اور مرد باہر کا۔مرد اپنے آہنی ہاتھوں سے کسب معاش کرے اور عورت اپنے دست نازک سے اسے مرد کے سامنے پیش کرے۔ محبت سے بھرے دل ہوں اور الفت سے لبریز برتاؤ۔مجبوری کی صورت میں دونوں کے معاش کا انتظام اسٹیٹ اپنی املاک سے کرے جو اسے اسٹیٹ کے نام پر دی گئی ہے اور جس تک عام انسان اور ان کی ضرورتوں کی رسائی نہیں ہے۔
مامتاکی قربانی کامطلب یہ ہے کہ اس معاشرہ میں عورت کو ایک مشین کی حیثیت
دے دی گئی ہے اس کاکام پرزوں کوڈھال دیناہے۔اس کے بعد پرزوں کا کیا مصرف ہوگا، کس مشین میں فٹ کئے جائیں گے،کس بازار میں بکیں گے،کس کس طرح ڈھالے اور تراشے جائیں گے اس کا مشین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔بچوں کا ماؤں کی مامتااور باپ کی شفقت سے محروم کر دینا یہ دونوں کے جذبات کی عظیم قربانی ہے جو بعض معاشی اغراض اور سیاسی مقاصد کے تحت لی توجاسکتی ہے لیکن اس کا باقی رکھنا بہت مشکل ہے۔ مامتا کسی وقت بھی جوش میں آسکتی ہے شفقت پدری کاجذبہ کسی وقت بھی بیدار ہوسکتاہے اور اگر بفرض محال ایسانہ بھی ہوااور سماج میں ایسی ہی بے حسی پھیل گئی تو بھی وہ معاشرہ یقینا قابل فخر ہوگا جس میں قربانیوں کے دئے بغیر انسانی نسل کی تربیت ہوجائے۔حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لئے نرسنگ ہوم قائم کئے جاتے ہیں۔ان کے لئے نرسیں رکھی جاتی ہیں اور اس طرح عورتوں یامردوں کی ایک خاص تعداد اس کام پر مقررکردی جاتی ہے لیکن یہی کام ان عورتوں اور مردوں کے حوالے نہیں کیاجاتاجنہیں فطرت نے ان کا مربی اور نگراں بنایا ہے اور جن کے دلوں میں تربیت کے بہترین جذبات پائے جاتے ہیں۔کھلی ہوئی بات ہے کہ تربیت کاکام ماں باپ کے حوالے ہوتاہے تو وہ اپنا سمجھ کرپالتے ہیں اور ملازمین کے حوالے ہوتاہے تو وہ ڈیوٹی سمجھ کر فرض انجام دیتے ہیں۔اپناسمجھنے کی صورت میں مقابلہ کا جذبہ ابھرتاہے اور ہر ایک اپنے بچے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتاہے اور ڈیوٹی کی صورت میں تربیت میں یکسانیت ہوتی ہے۔نرسوں کو کسی خاص بچے سے کوئی خاص انس نہیں ہوتاکہ وہ اسے زیادہ بہتر تربیت دے سکیں اور اس طرح ذاتی صلاحیتیں توابھرتی ہیں لیکن حسن تربیت کے اثرات پوشیدہ ہی رہ جاتے ہیں۔
یہ صحیح ہے کہ اولاد کی تربیت کے لئے ماں باپ ہی ضروری نہیں ہیں۔ انسان کا بچہ بھیڑیئے کے بھٹ میں بھی تربیت پالیتاہے اور انسان ہی رہتاہے لیکن علم الحیات کے ماہرین اتنا ضرورتسلیم کرتے ہیں کہ تربیت اور دودھ کا زندگی پر بے پناہ اثر پڑتاہے۔
بھیڑیے کے بھٹ میں پلنے والا بچہ انسان کا بچہ ضرور ہوتاہے لیکن بھیڑیاصفت درندہ خصلت ہی رہتاہے۔گائے اور بھینس کے دودھ پر پرورش پانے والا بچہ شکل میں انسان ہی رہتاہے لیکن صفات میں حیوانیت سے ضرورمتاثر ہوجاتاہے۔یہ اور بات ہے کہ آج کے معاشرہ میں اس کا احساس نہ ہوسکے اس لئے کہ تقریناً 75 فیصدی افراد اسی صفت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی اسی ایک نہج پر تربیت ہوتی ہے۔
اسلام نے اپنے معاشی نظام میں انہیں نکات کو پیش نظررکھاہے اور معاشی زندگی کے سدھار کے لئے انہیں امور کی رعایت کے ساتھ دستور مرتب کیاہے۔ اس کی نظرمیں معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لئے نہ صنف کی قربانی کی ضرورت ہے اور نہ مامتاکی۔ نہ انفرادی آزادی کے سلب کرنے کی احتیاج ہے اور نہ ذاتی ملکیت کے اس کا دستور یہ ہے کہ عورتیں گھر کے اندر رہ کر بچوں کی تربیت اور شوہر کی خوشحالی کا انتظام کریں۔جتنی اچھی بچوں کی تربیت ہوگی اتنا زیادہ مستقبل روشن ہوگا اور جتنا زیادہ شوہر کو خوش رکھیں گی اتنا ہی زیادہ اپنا فائدہ بھی ہوگااور سماج کی خدمت بھی عفت وپاکدامانی عورت کا عظیم جوہر ہے جس کی قربانی کسی عالم میں بھی روانہیں ہے۔اس دولت کی حفاظت بہرحال ضروری ہے چاہے اس کے لئے کتنی ہی زحمتیں کیوں نہ برداشت کرناپڑیں۔حکومت کاکام یہ ہے کہ وہ ان کے لئے وسائل تربیت مہیاکرے پرورش کے ذرائع زیادہ سے زیادہ فراہم کرے اور اگرعورت بیوہ،لاوارث یا مرد بیکار ومجبور ہوجائے توپورے گھر کی زندگی کا انتظام کرے۔حکومت عامہ انہیں زحمتوں سے بچنے کے لئے سارے ملک کوکام میں لگادینا چاہتی ہے اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر بچہ ماں باپ کے پاس رہے گا تو مامتا کے جوش اور باپ کی شفقت کی بناپر اس پراتنا بوجھ نہ ڈالاجاسکے گا جتنا بوجھ اپنے قبضہ میں رکھنے کے بعد ڈالاجاسکتاہے اور ظاہر ہے کہ جب کام کرنے والے زیادہ ہوں گے تو پیداوار بھی زیادہ ہوگی او رجب پیداوار زیادہ ہوگی تو ملک بھی خوشحال ہوگا۔سامان تعیش بھی بہتر فراہم ہوسکے گا۔ یہ
اور بات ہے کہ ملک کے باشندے فکر ونظر،شعورواحساس،جذبات وعواطف والے انسان نہ ہوں گے بلکہ کل پرزے والے آلات ہوں گے جنہیں زیادہ سے زیادہ تیل پانی دیاجائے گا تاکہ زیادہ دیر تک چل سکیں اور زیادہ سامان پیداکر سکیں۔
حضرت امام جعفر صادق ـنے انہیں مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے سچے اسلام کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچاتھاکہ:
اختبرواشعیتنا بجصلتین محافظتهم علیٰ اوقات الصّلوة ومواساتهم بینهم بالمال
ہمارے شیعوں اور پیروؤں کو دوعادتوں سے آزماؤ۔نماز کے اوقات کی پابندی اور آپس میں مالی ہمدردی۔
نماز کی پابندی بندگی ہے اور مالی ہمدردی زندگی اور اس زندگی وبندگی کے مجموعہ کے کانام ہے اسلام ایمان شیعیت اتباع اور محبت اہل بیت ـ
مذکورہ بالا تفصیلات سے دوباتوں کا اندازہ ہوتاہے ۔پہلی بات یہہے کہ طبقاتیت نظام فطرت کا لازمی نتیجہ ہے۔جب تک انسان مختلف ماحول سے دوچار رہے گا تخلیق انسان میں عالم اسباب کے مختلف اسباب کارفرمارہیں گے۔آب وہوا کا تغیر ایک ناقابل انکار حقیقت بنارہے گا۔انسانوں کی صلاحیت میں بھی اختلاف رہے گا اور صلاحیت کے اختلاف کے ساتھ محنت ومشقت کے عناصر میں بھی تفاوت رہے گا اور اس تفاوت کا لازمی نتیجہ طبقاتیت کی شکل میں برآمد ہوگا۔اسی لئے قرآن کریم نے نہ طبقاتیت سے انکار کیاہے اور نہ طبقاتیت کو کوئی بنیادی حیثیت دی ہے۔عظمت وکرامت کا معیار تقویٰ الٰہی کو قرار دیاہے دولت و ثروت کو نہیں۔دولت وثروت کا اضافہ فطری طاقت وتوانائی کا نتیجہ ہوسکتاہے لیکن تقویٰ وتقدس صرف نفسیاتی طہارت وتزکیہ کا نتیجہ ہے جو انسانی عظمت کا نشان او ربشری بلندی کے لئے سنگ میل ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ معاشی کشمکش کے اسباب طبقاتیت یا ذاتی ملکیت کے اندر نہیں ہیں بلکہ اس کی جڑیں ان کی پشت پرکام کرنے والی نفسیات تک پھیلی ہوئی ہیں۔یہ اور بات ہے کہ مارکس نے انسانی تاریخ کا واحد محرک اقتصاد کو قرار دیتے ہوئے نفسیات کی استقلالی حیثیت سے انکار کر دیا ہے اور اسی لئے اسے ہرمنزل پر ایک نئی مشکل سے دوچار ہونا پڑاہے اورہر مشکل کوحل کرنے کے لئے دورازکار تاویلیں کرناپڑی ہیں۔
استاد محترم فیلسوف الشرق(مصنف کتاب)کا سب سے بڑاکارنامہ یہی ہے کہ انہوں محرک تاریخ کی بنیادی بحث اٹھاکر مارکس کے اس نظریہ کا مکمل تجزیہ کر ڈالاہے اور نتیجہ میں یہ ثابت کر دیاہے کہ تاریخی تغیر وتطور کا سبب صرف اقتصادی انقلاب نہیں ہے بلکہ اس کی پشت پر دین،فلسفہ،نفسیات،اجتماعیات جیسے مختلف عناصر کی کارفرمائی رہی ہے اور یہ سب اقتصادیات سے ہٹ کر ایک استقلالی حیثیت رکھتے ہیں۔
ایسے حالات میں مکمل اقتصادی نظام کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ ان عناصر کی استقلالی حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے انسانی سماج کے ہرعیب کا الگ الگ تجزیہ کرے اور یہ دیکھے کہ کس عیب کی پشت پرکون سا عنصر کام کررہاہے تاکہ نتیجہ میں اس دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھاجائے اور تشخیص مرض کے ساتھ صحیح علاج کیاجائے۔اسلام کا طرۂ امتیاز یہی ہے کہ اس نے دین،فلسفہ،اجتماع،نفسیات سب کی استقلالی حیثیت کا اعتراف کرتے ہوئے اَدوارتاریخ میں ہرایک کو الگ الگ ماناہے اور حالات کا صحیح تجزیہ کرتے ہوئے امراض کا علاج تلاش کیاہے۔اس نے معاشی کشمکش کے تجزیہ میں بھی یہ محسوس کرلیاہے کہ اس کی نبیاد نہ طبقاتیت ہے اور نہ ذاتی ملکیت بلکہ حب ذات کا غیر محدود جذبہ ہے جو انسان کو غلبہ وقہر، استبداد واستحصال پرآمادہ کرتاہے۔اس نے ایک طرف''الناس مسلطون علیٰ اموال ه م'' کہہ کر ذاتی ملکیت کا اعتراف کیااور''نحن قسمنآ بینہم معیشتہم''کہہ کر طبقاتیت کے وجود کو ناگزیر قرار دیاہے اور دوسری طرف استبداد و استحصال کے جملہ
عناصر کو جڑسے اکھاڑکر پھینک دیاہے اور نتیجہ میں یہ ثابت کردیاہے کہ انسانی سماج کی اصلاح مساوات میں نہیں ہے بلکہ مواسات میں ہے۔انسان کی نبیادی ضرورت سامان نہیں ہے بلکہ اطمینان ہے اور یہ باتیں صرف اقتصادی خوشحالی سے حاصل نہیں ہو سکتیں بلکہ اس کی پشت پر صحیح نظریات وعقائدکی بھی ضرورت ہے اور یہ عقائد ونظریات معاشی نظام میں نہیں ملتے۔بلکہ مذہب میں ملتے ہیں اور اسلام اس معنی میں اپنے کو دین ومذہب سے تعبیر کرتاہے کہ اس میں معاشی اصلاح کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اصلاح کے عناصر بھی موجود ہیں وہ تقسیم دولت کے ساتھ تزکیۂ نفس کے اسباب بھی فراہم کرتاہے۔اس کے دامن میں زندگی کے سدھارکے ساتھ بندگی کے سدھار بھی پائے جاتے ہیں۔
مسئلہ گرچہ کافی تفصیل طلب ہے لیکن چونکہ کتاب کاموضوع اقتصادی ہے اس لئے اس سے ہٹ کر عقائد وافکار پرروشنی ڈالنا مناسب نہیں ہے۔اس مقام پر اتنا بھی ظاہر کرناتھاکہ دنیامیں اقتصادہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اقتصادی کشمکش کے اسباب غیر اقتصادی بھی ہیں اور ان کی اصلاح کے ذرائع غیر اقتصادی بھی ہوسکتے ہیں۔اقتصادکے ذریعہ اقتصاد کی اصلاح فلسفی اعتبار سے بھی ناممکن ہے۔
اقتصادی تاریخ کا ایک خاکہ
جہاں تک معاشیات کی نبیادی ضرورتوں کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ کہنا بیجانہ ہوگاکہ اس کی جڑیں انسانی تاریخ کی گہرائیوں تک پہنچی ہوئی ہیں۔انسان نے جب سے صفحۂ ہستی پر قدم رکھاہے اپنے ساتھ نبیادی ضرورتوں کی احتیاج لے کر آیاہے اور ہردور
میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی تدبیر کرتارہاہے۔نبیادی ضرورتوں کا مسئلہ پہلے انسان کے سامنے اسی طرح اہمیت رکھتاتھا جس طرح آج اربوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی دنیامیں اہمیت رکھتاہے۔فرق صرف نبیادی ضرورتوں سے مافوق مسائل میں پیدا ہواہے یا اقتصادیات کی اصطلاح میں یوں کہاجائے کہ ذاتی منفعت کے اعتبار سے ہرشیء ہر دور میں باارزش وبیش قیمت رہی ہے لیکن متبادل قیمت کا وجود اس وقت سے ہواہے جب سے انسانی آبادی کے ساتھ اس کی ضرورتوں میں اضافہ ہواہے اور ایک انسان اپنے جملہ ضروریات کی پیداوار کے اعتبار سے خود کفیل بننے کے لائق نہیں رہا۔ضروریات کو بڑھالینا توبہت حسین تصور تھالیکن اس کا علاج ایک بلائے بے درماں ہوگیا۔
انسان تقسیم کار کے اصولوںپر عمل پیراہونے کے لئے مجبورہوگیا۔قانون یہ بناکہ ہرشخص یاہر جماعت ایک خاص چیزکی پیداوارکاانتظام کرے اورآخرمیں ساری پیداوارکو حسب ضرورت تقسیم کرلیاجائے اور ایک کی پیداوار کو دوسرے کی پیداوار سے تبدیل کرلیاجائے۔تبدیلی کایہ تصور بظاہر بہت سادہ ہے لیکن اپنے پیچھے ایک پورا اقتصادی نظام رکھتاہے۔تبادلہ طرفین کی قیمت کا تعین چاہتاہے اور قیمت کا تعین قیمت کی بنیادوں کی جستجو کا متقاضی ہے جہاں سے علم معاشیات کے مسائل کا آغاز ہوتاہے۔
تاریخ اس دورکا قطعی سراغ لگانے سے قاصر ہے کہ اس دور میں اصول کار کیا تھے؟ اور اصول تقسیم کیاتھے؟لیکن زیادہ ہنگاموں کے نقل نہ ہونے سے اندازہ ہوتاہے کہ نبیادی ضرورتوں کی محدودیت کے پیش نظراس وقت کاانسان زیادہ پاک باطن اور صاف ضمیر رہاہوگا۔لیکن یہ چاندنی کتنے دن ؟آخرکو روشنی طبع کو بلابنناتھا چنانچہ بڑھتی ہوئی ضرورتوں نے مختلف اسباب کی طرف توجہ دلائی اور ہرشخص نے اپنے نجی کام بھی سنبھالے۔ اسے جہاں تبادلہ کے لئے زراعت کرناہے وہاں ذاتی افادیت کے لئے جانوروں کی پرورش بھی کرناہے۔اسباب کے اضافہ سے پیداوار میں اضافہ ہوااور پیداوار کے ضرورت
سے زیادہ ہونے کی بناپرکاہلی نے قدم جمائے اور اب انسانی مزاج یہ بن گیاکہ کام کم کرے او رمنفعت زیادہ حاصل کرے۔اس کا بہترین ذریعہ جسمانی توانائی اور بازوؤں کی طاقت کو جنگ وجدال پر صرف کرناتھا۔چنانچہ ہمسایہ کی زمینوں پر قبضہ کاسلسلہ شروع ہوگیا اور چاروں طرف جنگ وجدل کا بازار گرم ہوگیا۔جنگ وجدل کا مقصد صرف مالیات میں اضافہ نہ تھا اور نہ زمینوں کے رقبہ کا اضافہ ہی تھا بلکہ اس کا ایک نبیادی مقصد یہ تھا کہ مفتوح قوم کو غلام وکنیز بناکر ان سے کام لیاجائے۔غلامی کا سب سے بڑافائدہ یہ ہوتاہے کہ غلام کام زیادہ کرتاہے اور کھاتاکم ہے۔اس کی زندگی پرایک قانون حکومت کرتاہے۔''کام کرو اورکھاؤیامرجاؤ''۔ظاہرہے کہ جس کی زندگی اس کشمکش سے دوچار ہوگی اس کے یہاں کام کے علاوہ اور کیاہوگا؟نتیجہ یہ ہواکہ دھیرے دھیرے انسانی معاشرہ میں غلامی کارواج عام ہوگیا اور پورانظام اقتصاد غلامی کی بنیاد پر چلنے لگا۔
غلامی کس بلا کانام ہے؟اس کے مصائب کیاہیں ؟اس کا اندازہ تاریخ کے بیانات سے نہیں کیاجاسکتاہے۔اس کے لئے صرف اتنا تصور ہی کافی ہے کہ غلامی اس قنوطی زندگی کانام ہے جس میں اپنا کچھ نہیں ہے اور کرنا سب کچھ اپنے ہی کو ہے۔ہمارے ملک میں جس دور کو دور غلامی کہاجاتاہے وہ درحقیقت اجنبی محکومیت کا دور تھا۔ اسے غلامی سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور اسی لئے محکوم قوم کو احتجاج کرنے کا موقع ملا اور اس نے محکومیت کو آمریت وحاکمیت سے بدل ڈالا۔غلامی کے دور میں ایسے کسی امکان کا تصور بھی نہ تھاوہاں آزادی کا تصورجرم اور روٹی،کپڑے کا سوال ناقابل معانی قصور غلام ایک بازار کا سوداتھا اور کنیز ایک جواری کی ہاری ہوئی رقم۔
یہی سلسلہ ایک مدت تک چلتارہااور خود غرض حکام غلاموں کو ظلم کی چکی میں پیس پیس کراپنے''معاش فراواں''کا انتظام کرتے رہے۔انہیں اس کی خبر نہ تھی کہ اس طرح مایوس زندگی گذارنے والے اپنے دست وبازوکی توانائیاں کھوبیٹھتے ہیں جن کی بناپر ملک کی
فوج تیارہوتی ہے اور جس فوج کے سہارے دیگر ممالک کو فتح کرکے غلام سازی کے کام کو فروغ دیا جاتاہے۔نتیجہ یہ ہواکہ غلامانہ زندگی نے ساری توانائیاں ختم کر دیں اور حکام اپنے لشکر جرار سے محروم ہوگئے۔اب حکام کے سامنے دومتقابل سوالات تھے۔یاتواسی بزول، ضعیف وناتواں قوم کے سامنے حکومت کریں جس میں ہرآن دوسرے ملک کے حملہ کا اندیشہ اور ان غلاموں کے سراٹھانے کا خطرہ ہویا ان سب کو آزاد کرکے خود گوشہ نشین ہوجائیں۔جس کا مطلب حکومت سے محکومیت کی طرف قدم بڑھاناہے جو ایک ناممکن ساکام ہے ۔حکام نے مسئلہ پربڑی سنجیدگی سے غور کیااور ایک درمیانی حل یہ نکالا کہ غلاموں کو تھوڑی تھوڑی سی زمین دے کر انہیں کاشتکار کی حیثیت دے دی جائے اس طرح ان کی محکومیت بھی باقی رہے گی اور یہ ہمارے رحم وکرم سے مطمئن بھی ہوجائیں گے۔
یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ عالم میں جاگیر داری کا باب شروع ہوتاہے۔ جاگیرداری کے نبیادی اصول یہی تھے کہ حکومت برقرار رہے اور غلاموں کو کاشتکار کادرجہ دے کر ان سے کام لیاجائے۔کاشتکار اپنے عنوان کی تبدیلی سے خوش ضرور ہوجائے گا لیکن جب تک حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے لئے کوئی فرق نہ ہوگا۔
جاگیرداری سے مراد ہمارے ملک کا وہ دور نہیں ہے جس میں لوگ چند سال پہلے زندگی گذاررہے تھے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک،ظالم،سفاک،بے رحم اور سنگدل دورکانام ہے جہاں انسان خود بھی غلام ہوتاتھا اور اس کی زمین بھی مالک کی ملکیت ہوتی تھی۔بلکہ بسااوقات توعزت وآبرواور ناموس کی بھی کوئی قدروقیمت نہیں ہوتی تھی اور وہ سب جاگیردار کی ملکیت تصور کی جاتی تھیں۔انسانیت اس ''صبحِ حریت''کا انتظار کررہی تھی جب ایسے شدید جان لیوامظالم سے نجات ملے اور مواسات وہمدردی کے جذبات کے ساتھ ساتھ انسانی برادری کا تصور قائم ہوکہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے اسلام کا آفتاب چمکا اور اس کی ضیاباریوں نے ایک عجیب نورانی انقلاب برپاکردیا۔مغرب ان ضیاباریوں
سے بالکل بے خبر اور محروم تھا۔وہاں دردکا احساس کرنے والے بہت تھے لیکن دواکرنے والا کوئی نہ تھا۔بیمار لاکھوں تھے لیکن طبیب ایک نہ تھا۔
سلسلہ آگے بڑھتاگیااور ہوس دولت نے انسان کو اس منزل تک پہنچادیاجہاں زراعت پر صنعت کا اضافہ ہوا۔جاگیرداروں نے کارخانے کھولنا شروع کئے اور کاشتکاروں کو مزدوروں کی حیثیت مل گئی۔انسان کی قطرت کا تقاضایہ ہے کہ وہ جب ایک نظام سے عاجز آجاتاہے تو اسے ترک کرنے پر فوراً آمادہ ہوجاتاہے چاہے اس کا متبادل نظام پہلے سے بدتر ثابت ہو۔چنانچہ کاشتکاروں نے مزدوری کوکاشتکاری سے بہتر خیال کرکے اس کا استقبال کیااور دھیرے دھیرے جاگیرداری کی جگہ سرمایہ داری نے لے لی۔یہ فیصلہ دشوار ہے کہ ان دونوں نظاموں میں کون سا نظام زیادہ مفید اور صالح تھا لیکن اتنا ضرور کہاجاسکتا ہے کہ جاگیرداری کے دور میں کاشتکارکے ذہن میں کسی نہ کسی مقدار میں ملکیت اور آزادی کا تصور تھا اور سرمایہ داری کے دور میں وہ تصور بھی ختم ہوگیا۔زمینیں ہاتھ سے نکل گئیں اور کاشتکارکو مزدور کا ٹائٹل مل گیا۔اب صورت حال یہ ہے کہ مزدور مالک کے رحم وکرم پر کام کرے اور اس کی صوابدید کے مطابق اجرت لے۔
اجرت کا معاملہ بظاہر خود اختیاری ہوتاہے لیکن سرمایہ دارا نہ نظام میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے اور اس کا رازیہ ہے کہ ایک طرف سرمایہ دار کم سے کم خرچ پرزیادہ سے زیادہ پیداوار چاہتاہے اور دوسری طرف مشینوں کی بہتات آدمیوں کی ضرورت کو کم کرتی جارہی ہے۔نتیجہ یہ ہوتاہے کہ مزدور کے لئے زندگی دشوار ہوجاتی ہے اور وہ کم سے کم اجرت پرکام کرنے کے لئے تیار ہوجاتاہے۔
سرمایہ داری کا یہی وہ غیر عادلانہ تشددآمیز رویہ تھاجس میں انسانیت برسہابرس پستی رہی اور ایک وہ دور آیا جب مزدوروں کی قوت احساس کراہ سے بدل گئی اور اس کراہ نے سرمایہ داری کے خرمن میں آگ لگادی۔آگ کی ابتدائی چنگاری آدم اسمتھ اور ریکارڈو
جیسے مفکرین نے مہیا کی تھی لیکن وہ اپنی فکر کو منظم نہ کرسکتے تھے۔ان کی آواز صدابصحراہوکر رہ گئی۔دوبارہ اسی آواز کو کارل مارکس نے بلند کیاتو اس میں ایسی تنظیمی صلاحیت پیداکر دی کہ ایک عالم لبیک کہنے کے لئے آمادہ ہوگیا اور دنیا کے اکثر وبیشتر ممالک نے سرمایہ داری کا جنازہ نکل گیا۔یہ اور بات ہے کہ انسانیت اشتراکیت کے زیر سایہ جس جنت کا خواب دیکھ رہی تھی وہ خواب بھی شرمندۂ تعبیر نہ ہوسکا۔
کارل مارکسکی آواز یقینا عالمگیرہوتی اور اس کی تحریک کے زیرسایہ دنیا ایک جنت ارضی کا خاکہ بن جاتی لیکن مارکس کی فکر میں ایک نبیادی کمزوری یہ تھی کہ وہ سماج کے پست،غریب اور پسے ہوئے طبقے کا انسان تھا اور خود اس کافلسفہ اس بات کا شاہد ہے کہ انسانی افکار اس کے معاشی حالات کے ترجمان ہوتے ہیں۔نتیجہ یہ ہواکہ مارکس کے معاشی نظریات پر بھی اس کے ذاتی حالات نے قبضہ کرلیا اور اس کی فکر کی سنجیدگی ایک جذبۂ انتقام سے بدل گئی۔انتقام ایک ایسی بلاہے جو انسان کو صحیح راستہ سے ہٹادیتی ہے اور اس کی فکر کی سلامتی و سنجیدگی کو سلب کر لیتی ہے۔مارکس غریب طبقہ کا انتقامی ہیروتھا۔اس کی فکر پر انتقام کا جذبہ غالب آگیااور اس نے سرمایہ داری کا قلع قمع کرنے کے لئے ذاتی ملکیت تک سے انکار کر دیا۔مارکس کے ان افکار کا مکمل تجزیہ کتاب میں موجود ہے ۔اس مقام پر صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لئے مارکس افکار میں سے بعض افکار کو بطور نمونہ پیش کرکے یہ ثابت کیاجائے گا کہ اس پر انتقام کی چھاپ کتنی نمایاں ہے اور انتقام نے کس طرح اس کی فکر کو سنجیدہ علمی موازین سے الگ کر دیا۔مارکس نے اپنے فلسفہ کا آغاز ذاتی ملکیت سے کیاہے اور ملکیت کے لئے قیمت کو بنیاد قرار دے کر پہلی بحث قیمت کی اصل ونبیاد سے کی ہے۔ہم بھی اپنی بحث کا آغاز اسی انداز سے کررہے ہیں۔
قیمت:
کسی چیز کی قدروقیمت کی دوقسمیں ہوتی ہیں۔ایک اس کی ذاتی قدروقیمت جو اس کے منافع وفوائد کے اعتبار سے طے کی جاتی ہے۔کاغذ کی قیمت لکھناہے اورزمین کی قیمت کاشتکاری۔کاغذ لکھنے کے لائق ہے توقیمتی ہے چاہے اس کا تبادلہ نہ ہو زمین کاشت کے قابل ہے تو قیمتی ہے چاہے اس کی خرید وفروخت نہ ہو لیکن ایک قیمت تبادلہ کے اعتبار سے طے ہوتی ہے کہ اگرکاغذ یازمین کو دوسری جنس سے تبدیل کرنا چاہیں تو اس کے مقابلہ میں کاغذ کی قیمت کا معیار کیاہوگا۔ذاتی منفعت اور قدروقیمت کسی معیار کی محتاج نہیں ہے۔ اس کامعیار واضح ہے اور اس کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے۔عالم اقتصادیات میں اس سے کوئی بحث نہیں کی جاتی۔اقتصادیات میں بحث صرف متبادل قیمت سے کی جاتی ہے جو اقتصادکی روح اور معاشیات کی نبیادہے۔مارکس نے اس موضوع پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالاہے کہ متبادل قیمت کا معیار انسانی محنت ہے جس چیز پرجتنی محنت صرف ہوگی اس کی اتنی ہی قیمت ہوگی او رچونکہ قیمت کاپیداکرنے والا محنت کش مزدور ہوتاہے اس لئے حقیقی ملکیت کا حق بھی اسی کوہے مالک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
محنت اور قیمت کے رابطہ کو یوں سمجھے کہ ایک کسان نے دوگھنٹہ یومیہ تین ماہ تک محنت کرکے ایک من گیہوں پیداکیاتو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک من گیہوں 0 18 گھنٹہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔اب اگر کسی کاغذبنانے والے نے کپاس کی کاشت سے کاغذکی ساخت تک تین گھنٹہ یومیہ دومہینہ تک محنت کی ہے تو ایک من کاغذ بھی 180 گھنٹہ محنت کا نتیجہ ہے اور اس طرح ایک من گیہوں کو ایک من کاغذ سے بدلاجاسکتاہے اور اس تبادلہ کو کسی ایک کے حق میں ظلم نہیں کہاجاسکتااس لئے کہ دونوں پربرابر کی محنت صرف ہوئی ہے۔محنت کو الگ کرلینے کے بعد اس تبادلہ کاکوئی جوازنہیں ہے اس لئے کہ کاغذ کی جنس اور ہے اور گیہوں کی جنس اور اس کا پیدا کرنے والا اور ہے اور اس کا پیداکرنے والا اور ہے اور اس کی زمین اور۔
اس مقام پریہ بھی یادرکھنے کی ضرورت ہے کہ محنت کی دوقسمیں ہیں۔محنت بسیط محنت مرکب۔محنت بسیط وہ سعی ہے جس میں ایک ہی قسم کا کام ہوتاہے،جیسے لوہار، سناراور کسان وغیرہ کی محنتاور محنت مرکب وہ کوشش ہے جس میں کام کرنے سے پہلے کام کی اہلیت بھی ایک محنت کی طالب ہوتی ہے اور خود کام بھی مختلف قسم کی محنتیں چاہتاہے۔مثال کے طور پرآپ ایک مکان بنواناچاہتے ہیں۔مکان ایک قسم کی محنت سے تیار نہیں ہوسکتا۔اس کے لئے انجینئر کا نقشہ، مزدور کی جانفشانی،معمار کی دقت نظر اور مواد کی متناسب وموزوں شکل کی ضرورت ہے اور ان میں اکثرمحنتیں خود سابق میں محنت کی طلبگار ہیں۔انجینئر کا انجینئرہونا محنت چاہتاہے۔معمار کافن کارہونا محنت چاہتاہے موادکاموزوں ومتناسب شکل میں آنامحنت کا طالب ہے۔اس لئے مکان کی قیمت لگاتے وقت صرف انجینئر،معمار،مزدور اور مواد کی قیمتوںکا اندازہ کرلینا کافی نہ ہوگا بلکہ انجینئر ومعمار مواد پر صرف ہونے والی محنتوں کا لحاظ بھی کرنا پڑھے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ محنتیں کتنے کاموں پر صرف ہوئی ہیں اور ان میںا س مکان کا حصہ کیاہے تاکہ مکان کی صحیح قیمت کا اندازہ کیاجاسکے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام اس شکل میں انتہائی دشوار بلکہ ناممکن ہے اور ایسا معلوم ہوتاہے کہ اس طرح ایک مکان کی قیمت لگانے کے لئے انجینئر ومعمار کی ساری عمر کے کاروبار پر نظرکرنا پڑے گی جو ایک ناممکن عمل ہے۔حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔انجینئر کے انجینئر ہوجانے کے بعد اس کے فن کی قیمت مقررہوجاتی ہے اور یہ معلوم ہوجاتاہے کہ اس کے فن پرکتنی محنت صرف ہوئی ہے۔ اب مکان کی قیمت مقرر کرنے میں دوبارہ اس کی قیمت کے لحاظ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صرف سابق کی مقررشدہ قیمتوں کو جوڑدینا پڑتاہے اور بس۔
ایک نظر:
مارکس کے اس نظریہ پربحث کرنے کے لئے بڑاوقت درکارہے اور اسکے علمی
پہلوؤں پر مکمل بحث کتاب میں موجود ہے۔اس مقام پر صرف یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ نظریہ علمی اعتبار سے کتناوقیع اور باارزش کیوں نہ ہوعملی اعتبار سے انتہائی کمزور اور بے معنی ہے۔معاشیات کے اصول وقوانین دنیوی حالات سے قطع نظرکرکے وضع نہیں کئے جاتے اور نہ انہیں آسمان سے زمین پر نازل کیاجاتاہے وہ درحقیقت سماجی حالات اور معاشرتی حالات ہی کا ایک جائزہ ہوتے ہیں جن کے ذریعہ باہمی لین دین کی گہرائیوں تک جاکر یہ انکشاف کیاجاتاہے کہ یہ معاملہ کس نبیاد پرہورہاہے۔علم اقتصاد کاکام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک من گیہوں کا تبادلہ ایک ریم کاغذ سے جائز یاناجائز قرار دے،اس کاکام صرف یہ ہے کہ بازار میں ایک من گیہوں کو ایک رم کا غذ سے بدلتاہوادیکھ کر یہ انکشاف کرے کہ یہ تبادلہ کس بنیاد پر ہورہاہے ایک من گیہوں ایک ورق کاغذ سے کیوں نہیں بدلاجاتا۔ایک ریم کاغذ ایک چھٹانک گیہوں سے کیوں نہیں تبادلہ ہوااور اس تجزیہ کا فائدہ یہ ہوتاہے کہ اس طرح سماج میں ہونے والے مظالم کا صحیح اندازہ کرلیاجاتاہے اور ہمارے پاس ایک ایسا مستحکم قانون آجاتا ہے جس کی روشنی میں صالح او رفاسد نظام معاش کو الگ الگ کیاجاسکتاہے۔
ظاہر ہے کہ جب سماجی معاملات کا تجزیہ اس نیک مقصد کے لئے ہوتاہے تو اس میں ان تمام معاملات کو پیش نظررکھنا ہوتاہے جو آئے دن پیش آتے رہتے ہیں اور جن کو کوئی سماج ظلم یا ناانصافی نہیں تصور کرتا۔اس سلسلے میں یہ تاویل قطعاً غلط ہوگی کہ اکثر معاملات ہمارے قانون کی لپیٹ میں آجاتے ہیں اور اگردو ایک بچ جاتے ہیں تو انہیں استثنائی حالات کا درجہ دے دیاجائے۔اس لئے کہ اولاً توا ستثنائی حالات کا فیصلہ خود ایک تحکم اور دعوائے بے دلیل ہے اور دوسرے یہ کہ اس طرح کسی بھی نظام کی گرفت ممکن نہ ہوگی اور جب کسی غلطی یاکمزوری کی نشاندہی کی جائے گی اس کے لئے استثناء ہی کا سہارلیاجائے گا۔
مارکس نے اپنے اس قانون میں سماج کے بہت سے معاملات کو قطعی طورپر نظرانداز کردیاہے اور اس کے بظاہر دوہی سبب ہوسکتے ہیں یاتویہ چشم پوشی اس لئے کی گئی
ہے کہ ان تمام معاملات کو سامنے رکھنے کے بعد کوئی قانون نہیں تشکیل پارہاتھا اور عدل وظلم کا فیصلہ کرنے کے لئے قانون کی تشکیل ضروری تھی اس لئے اکثر معاملات کا سہارالے کر ایک قانون وضع کر لیاگیااور باقی معاملات کو استثناء کا درجہ دے دیاگیا۔
یا چشم پوشی کا دوسرا سبب(جومیرے نزدیک زیادہ قرین قیاس ہے)یہ ہے کہ مارکس کے انقلابی تصورات فلسفی نبیاد پر قائم نہیں تھے۔وہ اپنے سماج کے مظالم سے متاثر تھاکہ اس کے لئے صدائے احتجاج کابلند کرنا ایک ناگزیر امر ہوگیا تھا۔اس کے قانون میں فلسفیانہ سنجیدگی سے زیادہ انتقامی بھڑک پائی جاتی تھی اور انتقام کاتقاضا یہ تھاکہ سرمایہ دار طبقہ کو ظالم ثابت کیاجائے اور یہ بات اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک محنت کو دلیل ملکیت بناکر سرمایہ دار کو غاصب،چور،نکما اور سماج کا بے مصرف عنصرفرض نہ کرلیا جاتا۔مارکس کی یہی مجبوری یانفسیاتی کمزوری تھی جس نے اس کو اتنے اہم عناصر سے چشم پوشی پر آمادہ کردیا اور اس کا نظر یہ انتہائی مقبولیت کے باوجود قابل ترمیم وتنسیخ اور علمی میدان میں درجۂ اعتبار سے ساقط ہوگیا۔
فنون لطیفہ
اس میںکوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ کے ہردور میں فنون لطیفہ کو ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔انہیں دنیاکے دوسرے کاموں سے ممتاز رکھاگیاہے۔مذہبی اور علمی پہلو سے یہ بات صحیح ہویاغلط لیکن سماجی اور عملی پہلو سے یہ بات ناقابل انکار ہے کہ سماج نے ہر دور میں ان فنون کو اہمیت دی ہے۔ایک ایک رقص پرہزاروں روپیہ کا خرچ۔ایک ایک گانے پر روپہلے،سنہرے سکوں کی بوچھاراور اداکار کی ایک ایک ادا پر دولت فراواں کی بھینٹ،انسانی سماج کی پرانی تاریخ ہے جو آج تک مستمر ہے اور اگر ان باتوں کو جاگیرداری
یاسرمایہ داری کی لغت تصور کرلیاجائے(جیساکہ ہے)تو اس حقیقت سے بہرحال انکار نہیں ہوسکتاکہ سنگ تراشی ہردور میں ایک فن رہی ہے خوبصورت تصویریں بنانا ہرزمانہ میں ایک کارنامہ رہاہے اور اس کارنامہ کی قدروقیمت عام کاموں سے بالکل جداگانہ رہی ہے۔جس سے صاف واضح ہوتاہے کہ محنت کی مقدار کے علاوہ انسان کے ذوق لطیف کو بھی قیمت کے تعین میں بہت بڑادخل ہے۔
آثار قدیمہ
دنیا میں آثار قدیمہ کوبہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ بزرگوں کی یادگار ہرقوم و ملت میں قابل احترام رہی ہے۔قدیم تعمیرات ہر حکومت کے لئے باعث افتخار سمجھی گئی ہیں۔آثار قدیمہ کے تحفظ پرلاکھوں کروڑوں کا سرمایہ خرچ ہواہے۔اس کے تحفظ کے لئے عالیشان عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں،اسے ذریعۂ عزت قراردیاجاتاہے اور یہ کام اشتراکی اور غیر اشتراکی دونوں ملکوں میں برابر ہوتاہے۔انسانی فطرت کے تقاضے ماحول کے دباؤ سے دب جاتے ہیں مٹتے نہیں ہیں۔جہاں انسان رہتاہے اپنی فطرت اپنے ساتھ رکھتاہے یہ اور بات ہے کہ اشتراکی ممالک کی یہ سیرت خود اس کے نظام زندگی کی عملی کمزوری کی نشاندہی ہو۔ ہزار برس قبل کے مجسمہ پرکتنی ہی محنت کیوں نہ صرف کی گئی ہوآج کی محنت سے سیکڑوں گنازیادہ نہیں ہوسکتی۔حالانکہ ان کی قیمت سیکڑوں گنازیادہ ہوتی ہے۔معلوم ہوتاہے کہ قیمت میں صرف محنت کی مقدار ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ قلبی تعلق،سماجی لگاؤ اور امتدادزمانہ کا بھی ایک حصہ ہے۔
اس مقام پر یہ نہیں کہاجاسکتاکہ آج کے دور میں وسائل کی فراوانی،آلات کی کثرت کی بناپر مجسمہ تراشی میں اتناوقت اور اتنی محنت صرف نہیں ہوتی جتنی کل صرف ہواکرتی تھی۔اس لئے آثارقدیمہ کی زیادتی مارکس کے قانون کی شکست کا اعلان نہیں ہے بلکہ اسی کے قانون کی ایک فرد ہے۔اس لئے کہ اگرمارکس کی طرف سے یہ تاویل کی جاسکتی ہے تو اس کے جواب میں یہ بھی کہاجاسکتاہے کہ آج یہ مجسمہ تراشی ایک قسم کے مرکب عمل کی حیثیت اختیار کرگئی ہے جس کے لئے تعلیم وتربیت اور مشق ومہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل یہ کام زیادہ حصہ فطری صلاحیتوں کی پیداوار ہواکرتاتھا اس میں بہت معمولی تربیت کا دخل ہوتاتھا اور آلات واسباب بھی بہت بسیط تھے ایسی حالت میں آج کے آثار کی قیمت زیادہ ہونی چاہئے اور کل کے آثار کو بے ارزش ہونا چاہئے۔حالانکہ ایساہرگز نہیں ہے یعنی قیمت کا تعلق تمام ترمحنت سے نہیں ہے بلکہ اس میں زمانی عناصر کو بھی دخل حاصل ہے۔
مخطوطات ومطبوعات
آپ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی لائبریری میں چلے جایئے آپ کو وہاں دو قسم کی کتابیں ملیں گی ۔کچھ چھپی ہوئی اور کچھ ہاتھ کی لکھی ہوئی،لائبریری کے ذمہ داروں کی نظر میں مخطوطات قلمی کی قیمت مطبوعات سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔مطبوعات لائبریری کی تعدادبڑھانے کے کام آتے ہیں اور مخطوطات لائبریری کا وقار بڑھانے کے یہ ایک ایسا مذاق ہے جس کا دنیاکے کسی ملک نے انکار نہیںکیا۔مخطوطات میں بھی نوادر ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں کوئی لائبریری اس وقت تک قابل توجہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں نوادر
مخطوطات کی کثرت نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ مکتبات کے ذمہ دار افراد ایک ایک قدیم نسخہ کی تحصیل پر ہزارہاروپیہ صرف کر دیتے ہیں۔جبکہ وہی نسخہ موجودہ شکل میں بازار میں انتہائی ارزاں قیمت پرمل جاتاہے۔میں یہ نہیں کہناچاہتاکہ اس توجہ وامتیاز کا سبب انسان کا نفسیاتی رجحان ہے یا اس کی پشت پر بھی کوئی اقتصادی عنصر کام کر رہاہے۔مجھے تو صرف یہ واضح کرنا ہے کہ اشیاء واجناس کی قیمت کے تعین میں محنت کی مقدار کے علاوہ بھی دیگر عناصر کا دخل ہے۔ ایسا نہ ہوتاتو مطبوعہ کتابوں کی قیمت کہیں زیادہ ہوتی۔مخطوطہ نسخہ بسیط محنت کی پیداوار ہے اور مطبوعہ کتاب مرکب محنت کی۔اس میں پریس،مشین،مہارت، ٹرنینگ،تربیت جیسے بہت سے عناصر کام کررہے ہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ مرکب محنت کی پیداوار کی قدر وقیمت بسیط محنت کی پیداوار سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جیساکہ سابق میں واضح کیاجاچکا ہے۔
سپلائی اور ڈیمانڈ
قیمتوں کے اتارچڑھاؤ میں جہاں معاشرتی،اجتماعی،مذہبی اور نفسیاتی عناصر کارفرماہوتے ہیں وہاں خود پیداوار کی کمی وزیادتی بھی قیمتوں کے اتارچڑھاؤ پر اثر انداز ہوتی ہے۔پیداوار کی زیادتی کی صورت میں اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے اور کمی کی صورت میں زیادہ ۔جبکہ مارکسی اصول اقتصادیات کے تحت ایسا نہیں ہونا چاہئے۔وہاں صرف محنت ومشقت کی مقداردیکھی جاتی ہے،پیداوارکی کمی اور زیادتی نہیں۔
اس کی ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ آج دنیا کا ہر انسان اس حقیقت سے باخبر ہے کہ پانی انسان کی زندگی اور نمک انسان کی غذائیات میں ایک نبیادی حیثیت رکھتاہے۔
ان کے بغیر نہ زندگی کاکوئی لطف ہے اور نہ غذ اکا ۔ہیرے یانیلم کوان میں سے کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔انسان ہیرے کے بغیر زندہ بھی رہ سکتاہے اور لطف زندگی بھی اٹھاسکتاہے لیکن اس نبیادی فرق کے باوجود آج پانی یانمک کی وہ قدروقیمت نہیں ہے جو ہیرے یاسونے وغیرہ کی ہے جس سے صاف ظاہر ہوتاہے کہ اشیاء کی قدروقیمت کے تعین میں ندرت وجود کو بھی دخل حاصل ہے جو شیء جنتی نادر ہوتی ہے اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔دریاکے کنارے پانی بے ارزش ہے اور بے آب وگیاہ صحرامیں سونے سے زیادہ قیمتی۔ممکن ہے اس تفرقہ کی توجیہہ یہ کی جائے کہ اس مسئلہ کو ندرت وعمومیت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا معیار بھی محنت اور اس کی مقدار ہے۔دریا کے کنارے پانی نکالنے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی اور کان سے سونا برآمد کرنے میں زحمت ہوتی ہے۔اس لئے پانی بے ارزش ہوگیا اور سوناقیمتی۔لیکن سچی بات تویہ ہے کہ یہ توجیہہ ایک مغالطہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔دنیا کاکون سا انسان اس حقیقت سے انکار کردے گا کہ کھلی ہوئی کان سے برآمد کیا ہوا سونا بھی اتنی ہی قیمت رکھتاہے جتنا زمین کے اندر سے کھوداہواسونا۔جبکہ کھلی کان سے برآمد شدہ سونا اور دریا سے بھراہواپانی محنت کے اعتبار سے بالکل مساوی حیثیت رکھتاہے پھر اگر زحمت ہی کا حساب کرلیاجائے تو یوں فرض کیاجائے کہ دو مزدور بیک وقت محنت شروع کرتے ہیں۔ایک مزدورصبح سے شام تک کان کی کھدائی کرتاہے اور دوسرا کھیت کی کاشت۔ نتیجہ کے طورپر تین مہینے کے بعد اسے ایک من سونا ملتاہے اور اسے دس من گندم۔تو کیا دنیا کا کوئی انسان ان دونوں کے باہمی تبادلہ پر تیارہوسکتاہے اور کیاکسی انصاف کے بازار میں یہ کہا جاسکتاہے کہ چونکہ دونوں پر صرف کی جانے والی محنت یکساں ہے اس لئے دونوں کی قیمت بھی برابر ہونی چاہئے۔ہرگز نہیں اس کا کھلاہوا مطلب یہ ہے کہ مواد کی ندرت وعمومیت بھی قیمت کے تعین کا ایک اہم عنصر ہے صرف محنت ہی ساری چیزنہیں ہے یہ اور بات ہے کہ محنت نہ ہوتی تو سونا بازار میں نہ ہوتالیکن اس کا یہ مطلب ہرگز
نہیں ہے کہ سونا کچھ نہیں ہے جوکچھ ہے وہ محنت ہی ہے۔
واضح لفظوں میں یوں کہاجائے کہ مارکس نے اپنے اصول اقتصادمیں جہاں سپلائی اور ڈیمانڈ کے عدم توازن کو نظرانداز کردیاہے وہاں خام مواد کی قدر وقیمت کو بھی یکسر فراموش کردیاہے اس کی نظرمیں نہ دوحالات کے علوم میں فرق ہے اور نہ دومواد پر صرف ہونے والی طاقتوں میں۔جبکہ پانی اور سونے کا تفاوت خام مواد کے عظیم فرق کی طرف اشارہ کررہاہے اور بازار میں ذخیرہ اندوزی کے حالات کا عمومی حالات سے اختلاف سپلائی او رمانگ کے عدم توازن کی مکمل نشاندہی کررہاہے اور یہ بتارہاہے کہ خام مواد کے اختلاف سے بھی قیمتوں میں فرق پیداہوتاہے اور سپلائی اور مانگ کے عدم توازن سے بھی۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانی محنت بڑی باوقعت اور قیمتی شیء ہے۔ انسان اس کا ئنات کی روح اور اس کا جوہر ہے۔یہ نہ ہوتا تو پہاڑوں کے سینے میں چھپے ہوے جواہرات کا قدرداں نہ ہوتا۔یہ نہ ہوتاتو دریاؤں کی تہوں میں قلب صدف کی امانت بے وقعت ہوتی۔یہ نہ ہوتاتو نورآفتاب اور خنکی ماہتاب بے ارزش ہوتی یہ نہ ہوتاتو چلتی ہوئی ہواؤں اور پھیلی ہوئی فضاؤں کا قدرشناس نہ ہوتا۔یہ نہ ہوتاتو کوہ گرد فراراور گرد فرار کا امتیاز نہ ہوتا۔یہ نہ ہوتاتو کائنات ہوتی لیکن وجہ کائنات اور جان کائنات نہ ہوتالیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر یہی سب کچھ ہے اورکائنات کچھ نہیں۔اس کا احساس توخود انسان کو بھی ہے کہ یہ کائنات میرے لئے ہے لیکن میراوجود وقیام اسی کا شرمندۂ احسان ہے۔اسی کی سرزمین سے میراقرار اور اسی کے آسمان سے میری زندگی کی چھاؤں ہے۔اسی کے آفتاب سے میرے خون میں گرمی اور اسی کے ماہتاب سے میر ی آنکھوں میں خنکی ہے۔ اسی کی ہواسے نفس کی آمدوشد ہے اور اسی کی فضامیں امکانات سیر وسیاحت ہیں۔مطلب یہ ہے کہ میں اس سے ہوں اور یہ میرے لئے ہے۔لہٰذا اشیاء کی قدروقیمت کے تعین میں جہاں میری محنت ومشقت کو دیکھاجاتاہے وہاں اس کے ذاتی منافع وفوائد،آثار ومصالح کو
بھی نظر اندازنہیں کرناچاہئے۔
مارکس کی بنیادی غلطی یہی تھی کہ اس نے قیمت کو ذاتی اور تبادلی کی طرف تقسیم کرکے دوسراقدم بڑھایا تو ذاتی قیمت کویکسر نظرانداز کر دیا اور تبادلی قیمت کے تعین کے عناصر کو دوسرے مقامات پر تلاش کرنا شروع کردیا۔حالانکہ اسے کم سے کم اتنا ضروردیکھنا چاہئے تھاکہ اگر تبادلی قیمت کا میدان ذاتی قیمت سے بالکل الگ ہے توذاتی قیمت کو قیمت ہی کیوں قرار دیاجاتاہے۔اس کے قیمت ہونے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یہ قیمت دوسری قیمت کے تعین میں مفید اور کارگرثابت ہوسکے اور اسی کی روشنی میں اس کا بھی فیصلہ کیاجاسکے۔
مارکس اور سرمایہ داری
قیمت واجرت کا معیار مقررکرنے کے بعد مارکس نے سرمایہ داری پر تنقید کرنا شروع کی۔اس کی نظرمیں معیار قیمت کی تحقیق وتعین ہی سرمایہ داری پر تنقید کی علمی بنیاد ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ سرمایہ دار کارخانہ میں پچاس ہزار کا خام مواد صرف کرکے سومزدوروں کی محنت سے اسے سال بھرمیں ایک لاکھ بنالیتاہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک لاکھ میں نصف حصہ خام مواد کاہے اور نصف مزدوروں کی محنت کا۔اور جب محنت ہی قیمت کی نبیاد ہے تو اس قیمت کے پیداکرنے والے مزدور ہیں مالک نہیں ہے اور یہ کتنا بڑاظلم ہے کہ پیدا کرنے والے کو اپنی قیمت نہ ملے اور دوسرا اس پر قابض ہوجائے۔سرمایہ دار کو کسی طرح یہ حق نہیں پہنچتاکہ وہ پچاس ہزار میں پچیس ہزار مزدوروں کو دے کر باقی پچیس ہزار پر خود
قابض ہوجائے۔یہ مزدوروں کے حق کی چوری اور ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس ظلم و شقاوت کے مٹانے کا سب سے بڑا نبیادی ذریعہ یہی ہے کہ شخصی ملکیت کا دروازہ بند کر دیاجائے۔نہ سرمایہ دار کے پاس مال ہونہ وہ کارخانہ کھولے اور نہ مزدوروں کا حق ماراجائے۔ ورنہ جب تک سماج میں یہ لعنت رہے گی طبقاتیت ناگزیر ہوگی۔ ایک طبقہ بنگلوں میں بسنے والا ہوگا اور دوسرا محنت کی چکی میں پسنے والا۔یہ کتنا بڑاغضب ہے کہ دن رات کارخانہ میں گھسنے والا مزدور فٹ پاتھ پر پڑارہے اورکارخانہ کے مصائب کا تماشائی سرمایہ دار اپنی دولت میں روز افزوں اضافہ کرے۔
اس کے بعد یہ طبقاتیت صرف اقتصادی اونچ نیچ کے معنیٰ میں رہ جائے تو پھر غنیمت ہے لیکن قیامت تویہ ہے کہ اس طبقاتیت سے بیدردی اور شقاوت کا جذبہ بھی پیدا ہوتاہے۔مزدوروں کا خون چوس کر دولتمند بننے والا انسان مزدوروں کے دکھ درد کا احساس کیوں کر کرسکتاہے؟پھر اس کا دوسرا زینہ اوربھی بھیانک ہوتاہے۔بیدردی اور شقاوت کے ساتھ اخلاقی اقدار پر بھی زوال آجاتاہے۔سرمایہ دار اپنے سے کمتر طبقہ کو حقیر،ذلیل اور اپنے کو صاحب عزت واحترام سمجھتاہے۔اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ یہ ساری دولت وثروت اور یہ سارا وقار واحترام اسی مزدور کی محنت وجانفشانی کا نتیجہ ہے جسے ذلیل نظروں سے دیکھاجارہاہے اور جسے مستحق رحم وکرم بھی نہیں قرار دیاجاتا۔
سرمایہ داری سے سماج پر یہ اثربھی پڑتاہے کہ سرمایہ دار اپنے کثیر سرمایہ کو کسی وقت بھی بیکارنہیں دیکھنا چاہتا۔اس کی ہر آن یہی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی طریقہ سے دوگنا اور چوگنا بنایاجائے۔وہ اس کے لئے مختلف ذرائع اختیار کرتاہے جن میں سے اہم ذرائع سود خواری اور ذخیرہ اندوزی ہیں۔اس لئے کہ ثروت مند انسان کبھی کاہل بن جاتاہے اورکبھی دولت کی ہوس میں چست وچالاک اور چاق وچوبند رہتاہے۔سست وکاہل آدمی کا شعار یہ ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو سرمایہ تقسیم کرکے ان سے ماہ بہ ماہ سودوصول
کرتاہے۔اس طرح سماج میں اس کی قدرومنزلت بھی ہوگی اور لوگ یہ سوچ کر احترام کریں گے کہ یہ شخص آڑے وقت پر غریبوں کے کام آتاہے اور اپنا سرمایہ بھی ترقی کرتارہے گا رند کے رند رہیں گے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے گی۔
چست وچالاک آدمی کا یہ وطیرہ ہوتاہے کہ وہ سرمایہ کے زور پر فصل کے موقع پر ہی کھلیان سے غلہ خرید لیتاہے اور بعد میں جب لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگتے ہیں تو ان سے زیادہ سے زیادہ رقم لے کر وہ غلہ ان کے ہاتھ فروخت کردیتاہے۔
ظاہر ہے یہ طریقۂ کار صرف اخلاقی کمزوریاں ہی نہیں پیداکرتابلکہ اسی کے ساتھ ساتھ سارے سرمایہ کو صرف چند آدمیوں کے پاس جمع کردیتاہے۔جو شیء دنیا کی تباہی کا پیش خیمہ ہی ہوسکتی ہے اور بس۔
اس سلسلہ میں سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ سرمایہ دار نظام کے تحت پرورش پانے والے ذہن ومزاج بھی اس قدرابتری اور پستی کا شکارہوجاتے ہیں کہ ان کی نظرمیں اخلاقی اقدار اور انسانی شرافت کا معیار ہی بدل جاتاہے ایک غربت زدہ انسان سود لیتے وقت سرمایہ دار کی تعریف کرتاہے کہ یہ میرے آڑے وقت پرکام آیا اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتاکہ یہ حرام خور میرا خون جگر چوسنا چاہتاہے۔وہ یہ سوچ بھی نہیں پاتاکہ اسے اپنے نفس کی تسکین کے بعد مزید کسی مطالبہ کا حق نہیں ہے۔آپ نے اس دنیا میں بہت سے ایسے افراد دیکھے ہوں گے،جو سودپرروپیہ دینے والے افراد کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور رقم کی واپسی کے موقع پر دوچارروپیہ سود کے معاف کر دینے کو ایک اہم کارخیر سمجھتے ہیں۔ان کے اذہان کی پستی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص وعدہ کرنے کے بعد سود نہ دے تو وہ اسے سماج کا سب سے بڑا مجرم تصور کرتے ہیں۔ان کی نظرمیں وعدہ خلافی بہت بڑاگناہ ہے اور حرام کی رقم کھاکرغریب کی محنت کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ کار خیر ہے۔
اور یہ سب اس لئے ہوتاہے کہ سادہ لوح انسان جس ماحول میں تربیت پاتاہے اس کے اصول وقوانین کو اپنے لئے آسمانی وحی سے کم نہیں سمجھتا۔اس میں اتنا شعورنہیں ہوتاکہ وہ صحیح وغلط اور فاسد وصالح میں امتیاز پیداکرسکے۔ اشراکی ماحول میں آنکھ کھولنے والے انسان کا بھی یہی حال ہوتاہے۔وہ بھی پیدائشی طور پر اپنے کو حکومت کا غلام اور اپنے دست وبازوکی طاقت کو اسٹیٹ کا صدقہ سمجھنے لگتاہے اسے اس بات پر تعجب نہیں ہوتاکہ میرے دست وبازو کی پیداکی ہوئی قیمت پراسٹیٹ کا قبضہ کیوں ہوگیا؟اور میری کمائی ہوئی دولت پر تصرف کرنے کاا ختیار مجھے کیوں نہیں ملا؟
مارکس ازم پر ایک نظر
کارل مارکس نے سرمایہ دار نظام پر اعتراض کرتے ہوئے جن نکات کا حوالہ دیا ے ان میں سے اکثرباتیں خود ان کے مرتب کئے ہوئے اصولوں میں بھی مشترک طور پر پائی جاتی ہیں۔انہوں نے قیمت کو محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے یہ نتیجہ نکالاہے کہ سرمایہ دار مزدور کی پیداکی ہوئی قیمت کے ایک بڑے حصہ کا غاصب یاچور ہوتاہے اور اسی لئے سرمایہ دار ماحول ہمیشہ مالک ومزدور کی جنگ سے دوچار رہتاہے لیکن اس بات پر توجہ نہیں دی کہ مزدور کو اس کی پیداکی ہوئی تمام قیمت کامالک فرض کرلینا ہر نظام اقتصاد کی نبیادوں کو متزلزل بناسکتاہے چاہے وہ سرمایہ دار نظام ہویاغیر سرمایہ دار۔اس لئے کہ مزدور ہر وقت اپنی محنت کے نتیجہ کا مطالبہ کرے گا اور نتیجہ میں مالک ومزدورکی جنگ حکومت وملازم کی جنگ میں تبدیل ہوجائے گی اور نظام کی ابتری بدستورقائم رہے گی۔
دوسری خرابی یہ بھی پیدا ہوگی کہ کام سے عاجز ہوجانے والے بوڑھے،بیمار، مفلوج، مشلول،بچے وغیرہ ملک میں زندہ رہنے کے حق سے محروم ہوجائیں گے۔کام کرنے والے اپنے تمام نتیجہ عمل کا مطالبہ کریں گے اور کام سے عاجز رہ جانے والے بھوکوں مرجائیں گے۔اس وقت یہ نہیں کہاجاسکتاکہ ایسے حالات میں حکومت اپنی دخل اندازی سے ایسے لوگوں کے رزق کا سامان کرے گی اور انہیں بھوکوں نہ مرنے دے گی۔اس لئے کہ یہ جواب اصول مارکس سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوگا۔مارکس کے اس نظریہ کے تحت حکومت صرف مزدوروں کی ایک وکیل ہوتی ہے۔اس کاکام ان کی پوری محنت کا نتیجہ دلوانا ہوتاہے اس سے زیادہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور ایسی صورت میں اسے مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے ورنہ اشتراکیت بھی سرمایہ داری کی ایک مہذب شکل کانام ہوجائے گی اور مزدور بہرحال اپنی پوری اجرت سے محروم رہے گا۔
اس مقام پر یہ بھی یادرکھنا چاہئے کہ''تقسیم باعتبار ضرورت''کا اصول بھی مارکس کے نبیادی نظریہ سے ہم آہنگ نہیں ہے جب تک کہ اس میں دیگر سیاسی افکار کی آمیزش نہ کرلی جائے اور ظاہر ہے کہ جدید علم اقتصادمیں اس امتزاج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔اس کی نظرمیں سیاست کا میدان اقتصادی ترقیات سے بالکل الگ ہے اور ہونا چاہئے۔
مارکس کے اس اصول کا ایک اثر طبقاتیت کی شکل میں بھی ظہور پزیر ہوگا۔اس لئے کہ سارے مزدور اپنے ظاہری اعضاوجوارح یاباطنی جذبات واحساسات کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوتے۔ان میں چاق وچوبند،ہوشیار ودانشمند بھی ہوتے ہیں اور انہیں میں ضعیف ولاغر،غبی وکندذہن بھی اور کھلی ہوئی بات ہے کہ پہلی قسم کے مزدوروں کی پیدا کی ہوئی قیمت دوسری قسم کے مزدوروں کی پیداوار سے یقینا زیادہ ہوگی۔اب اگر حکومت اپنے حدود کے اندررہ کر مزدوروں کو ان کے صحیح حقوق دلوانے پر اترآئے تو ایک ہی مہینہ کے اندرسماج میں دو طبقے پیداہوجائیں گے اور ایک کی دولت دوسرے سے دوگنی ہوگی۔پھر یہی
بات دوسرے مہینہ میں بھی ممکن ہے جس کے بعد بڑے طبقہ کی دولت اور بھی بڑھ جائے گی اور ماہ بہ ماہ اس کی دولت میں اضافہ ہوتارہے گا اور معاشرہ اسی لعنت کی طرف پلٹنے لگے گا جس سے صدیوں کے بعد نکل سکاہے۔ اس مقام پر یہ امکان ضروررہتاہے کہ حکومت اس سرمایہ کو ختم کر ادے،سلب کرلے یا اس طبقہ کو دولت بڑھانے کا اختیارنہ دے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اصولی طور پر صحیح نہ ہوگی۔خواہ سیاست کے تقاضوں کی بناپر اسے جائز ہی کیوں نہ بنالیاجائے۔
مارکس نے سرمایہ داری کے عیوب ومفاسد کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ تمام باتیں''انفرادی ملکیت''سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے اگرانفرادی ملکیت کو اجتماعی ملکیت سے بدل دیاجائے تو ساری خرابیاں ازخود دور ہوجائیں گی۔چنانچہ انہوں نے اس سلسلہ میں ایک اصول نہ بنایاکہ ملک کاسارا سرمایہ سارے عوام کے لئے ہے اور عوام ملک کے خادم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ بقدر طاقت محنت کرے اور بقدر ضرورت نتیجہ لے لیکن سوال یہ ہے کہ جب مقدار عمل کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہیں تو ایک کے نتائج عمل کو دوسرے کے حوالے کر دینے کا جواز کیاہوگا اور''محنت اصل قیمت ہے''کانظریہ کیوں کر خاک میں ملادیاجائے گا؟
حقیقت یہ ہے کہ مارکس نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں اس میں دین ودنیا دونوں شدید طاغوتیت کا شکار تھے۔دین کے ٹھیکہ دار سرمایہ داروں کے چشم وابروکے اشاروں پر رقصاں تھے اور ان کی افتادطبع کے مطابق احکام گڑھ رہے تھے۔کنیسہ ثروت مندی اور اس کے مظاہر کا اڈہ بناہواتھا۔پوپ بڑے سے بڑے سرمایہ دار سے ٹکڑلیتا تھا۔ سرمایہ کے زور پر جنت کا بیوپار ہورہاتھا دوسری طرف دنیادار دولت وثروت کے بھروسہ پر پوپ کی تائید کررہے تھے۔زندگی اور جنت کا حسین امتزاج منظر عام پر آرہاتھا۔عیاشی، عیاری اور ظلم وستم کا شباب تھا۔مزدوروں کی آواز صدابصحراتھی اور
ظاہر ہے کہ ایسا ماحول کبھی بھی حساس انسان کو خاموش نہیں بٹھا سکتا۔ مارکس کے دل میں یہ ورد ایک طوفان بن کر اٹھااور زندگی کے مختلف شعبوں پرچھاگیا۔دنیاکا دستور ہے کہ جب کوئی نظریہ معمولی اور نارمل حالات میں بنتاہے تواس میں سنجیدگی اورآزادیٔ فکرہوتی ہے اور جب کسی جذبہ سے تاثر کا شکار ہوجاتاہے تو اس کی سنجیدگی جوش انتقام کا شکار ہوجاتی ہے۔مارکس کے ساتھ بھی یہی المیہ پیش آیا۔اس نے اہل کنیسہ اور سرمایہ داروں کے مظالم دیکھے اور ایک مرتبہ چیخ اٹھا۔اس کی آواز احتجاج کسی سینے کے درد میں مبتلا مریض کی چیخ تھی۔ظاہر ہے کہ ایسی چیخ میں نہ کوئی توازن ہوتا ہے اور نہ نالہ وفریاد میں کوئی لئے۔اس لئے اس نے مذہب پرنظر ڈالی تو اسے یکسر معطل کرکے یہ اعلان کردیاکہ مذہب چند فرسودہ خیالات کا مجموعہ ہوتاہے جن میں سرمایہ دار عوام کو خاموش کرنے کا ذریعہ اور ہادیاں مذاہب عوام کی طاقت کو استحصال کا وسیلہ بناکر رکھتے ہیں۔
سرمایہ دار ماحول کو دیکھاتو یہ طے کردیاکہ''انفرادی ملکیت''لغوومہمل ہے اس سے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔سرمایہ دار مزدوروں کے حق کا چور ہے۔اس سے مزدوروں کا انتقام لینا چاہئے اور ان تمام حالات سے عوام کو گذرنا پڑتاہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارکس کے سینے میں دل تھا اور اس دل میں تڑپ تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ اس تڑپ کی زدمیں نظریہ کا توازن بھی آگیا۔ اس نے حالات کے پیش نظر مزدوروں سے ہمدردی کی جس میں وہ حق بجانب بھی تھا اور انسانیت کی بارگاہ میں ماجور بھی۔لیکن ستم یہ ہواکہ اس نے سرمایہ کو بالکل ہی نظرانداز کر دیا اور اس کے ساتھ کسی رعایت کو روانہ رکھا کاش اس نے اتنا اور سوچاہوتاکہ مل کاملک بھی سماج ہی کا ایک انسان ہے اس نے بھی اپنا خون پسینہ ایک کیاہے۔وہ بھی دماغی صلاحیتوں کو صرف کرکے کارخانے کو آگے بڑھاتاہے۔اس پیداوار میں اس کا بھی حق ہونا چاہئے۔ایسا ہوگیاہوتا اور اس نے اپنے نظریہ میں اتنا لوچ پیداکردیاہوتا تو آج زیادہ تراعتراضات سے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی
صورت ضرور ہوتی۔
مارکس کی صورت حال کو دیکھنے کے بعد یہ واضح طو رسے کہاجاسکتاہے کہ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کی بنیاد جذبات پر ہے۔سرمایہ داری کے جذبات اونچے طبقہ کے ساتھ وابستہ ہیں اور اشتراکیت کے جذبات نچلے طبقہ کے ساتھ۔اشتراکیت،سرمایہ داری کے مقابلہ میں قابل تحسین وآفرین ہے لیکن حق وعدالت،انصاف وغیرہ جانب داری کی بارگاہ میں وہ بھی لائق مواخذہ ہے کہ اس نے بھی مسئلہ کو اس سنجیدگی کے ساتھ نہیں اٹھایا ہے جس سنجیدگی سے ایسے اہم مسئلہ کو اٹھنا چاہئے تھا۔
نتیجہ یہ ہواکہ مارکس کے بنائے ہوئے اصول بھی نہ طبقاتی نظام کو مٹاسکتے ہیں اور نہ مزدور کو اس کا صحیح مقام دلاسکتے ہیں۔جب تک ان میں جبر کی آمیزش نہ کرلی جائے اور جبرہی وہ چیز ہے جس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لئے مزدور مارکس نظام کا ساتھ دے رہاہے ورنہ اسے معلوم ہے کہ ہر نظام میں کچھ نہ کچھ کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں جنہیں اس نظام کے برسراقتدار آنے کے بعد بھگتنا پڑتاہے۔
سرمایہ داری پر ہماری ایک نظر
سرمایہ داری کا تاریخی اور علمی تجزیہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اس کے مفاسدو عیوب کا تعلق''انفرادی ملکیت'' سے نہیں ہے۔اس کے عیوب کے پس منظر میں انسان کی نفسیات کار فرماہے۔ نفسیات کو اقتصادیات سے الگ کردینا ایسا ہی جرم ہے جیسے نفسیات کو اقتصادی نظام کا ردعمل تصورکرناالٰہیات کے اصول تسلیم کئے جائیں یانہ کئے جائیں اتنا
بہرحال ماننا پڑے گاکہ انسانوں میں فطری طور پر کچھ جذبات پائے جاتے ہیں جن کے اصل وجود میں سارے بنی نوع انسان شریک اور کیفیات واقدار میں سب کے سب مختلف ہیں۔انسان کا سب سے اہم جذبہ جس سے''مافوق البشر''طاقتوں کے علاوہ کسی ایک کو بھی مستثنیٰ نہیں کیاجاسکتا۔''حب نفس''کاجذبہ ہے۔یہ علماء نفسیات کا ایک مسلمہ بھی ہے اور ہر انسان کا ذاتی مشاہدہ بھی کہ انسان کے جملہ اعمال وافعال کا سرچشمہ اپنے نفس سے محبت کا جذبہ ہوتاہے اور بس۔
فلسفی انداز سے یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی نفس ناطقہ جسے تمام کمالات وفضائل کا مدرک تصور کیاجاتاہے اس کا عالم خارج سے کوئی رابطہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اسے عالم خارج کا ایک آئینہ تصور کرلیاجائے اور آئینہ کاخاصہ یہ ہے کہ آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کی پشت پر کوئی آدمی ہوتو اس آدمی کی کیفیات وحالات سے آپ کارابطہ اسی آئینے کے ذریعہ ہوگا۔آئینہ سامنے سے ہٹ جائے تو آپ اس سے بالکل بے تعلق ہوجائیں گے۔یہی حالت کائنات اور انسان کے درمیان رابطہ کی ہے۔بچہ دودھ کیوں مانگتاہے؟ انسان غذاکیوں استعمال کرتاہے؟تعلیم کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟لباس کا استعمال کیوں ہوتاہے؟ممالک پر حملہ کیوں کیاجاتاہے؟سرمایہ جمع کرنے کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ اقتدار کے پیچھے دوڑکیوں لگائی جاتی ہے؟ جینے کی تمناکیوں ہوتی ہے؟ مرنے کی خواہش کیوں پیدا ہوجاتی ہے؟صحت کی طلب کیوں ہوتی ہے؟مرض سے نفرت کا سبب کیاہے؟زمانہ کے تغیر کے ساتھ انسان کے خیالات کیوں بدل جاتے ہیں؟ان تمام سوالات کا جواب ایک لفظ ہے یعنی''حب نفس''انسان کو اپنے نفس اور اپنی ذات سے محبت ہے۔اس کا نفس جس چیز کی اچھائی کا ادراک کرتاہے۔وہ اس کی طرف خودبخود متوجہ ہوجاتاہے اور جس چیز کی برائی کا فیصلہ کرلیتاہے اس سے متنفر ہوجاتاہے لیکن یادرکھئے کہ یہ نظریہ ہیگل کی مثالیت سے بالکل مختلف ہے۔ہیگل کی نظرمیں کائنات صرف ایک نفسیاتی
تصور اور ذہنی خیال کا نام ہے۔اس کے یہاں ہر شی کا وجود نفس کے ادراک سے وابستہ ہے اور اس فلسفہ میں نفس صرف وجود کو ذات سے مربوط کرنے والی طاقت کانام ہے اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے تمام تصرفات اور اس کے جملہ افعال واعمال کا سرچشمہ نفس کا ادراک ہی ہے تو اس کا کھلاہوا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کائنات سے محبت نہیں ہے۔وہ صرف اپنے نفس سے محبت کرتاہے۔اب جسے اس کا نفس اچھا سمجھتاہے اسے وہ بھی اچھا سمجھنے لگتاہے اور جس سے نفس نفرت کرتاہے اس سے وہ بھی نفرت کرنے لگتاہے۔نفس ہی وہ معشوق ہے جس کے چاہنے والوں اور محبوبوں سے محبت کرنا فطرت انسانی کا فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی معشوق کا یہ انداز محبت نہیں ہے۔حد یہ ہے کہ اکثر اوقات انسان کی اطاعت وعبادت میں بھی نفس ہی کی محبت کارفرمارہتی ہے۔وہ عبادت کیوں کرتاہے؟ برائیوں سے پرہیز کیوں کرتاہے؟واجبات پر عمل پیراکیوں ہوتاہے؟محرمات سے کیوں دوربھاگتاہے؟یہ سب اسی لئے ہوتاہے کہ نفس ایک صورت میں راحت محسوس کرتاہے اور دوسری صورت میں عذاب الٰہی کا دردو الم۔ اور جس میںراحت محسوس کرتاہے اس کی طرف انسانی اعضاء کو کھینچ لیتاہے اور جس میں تکلیف سمجھتاہے ادھر قدم اٹھانے سے روک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ان نظریات وادراکات سے ہم خیال نہیں ہوتا اس کے نفس میں یہ محرکات وعوامل بھی نہیں پیدا ہوتے اور اس کا طرزعمل مسلمانوں کے طرزعمل سے بالکل مختلف ہوتاہے اس مقام پریہ نہیں کہاجاسکتا کہ اس کائنات میں حب نفس کے محرکات سے مافوق عمل کرنے والے نہیں ہیں ہیں اور ضرور ہیں لیکن یہ ضرور کہاجاسکتاہے کہ ان کی تعداد انگلیوں پرگنے جانے والے اعداد سے کسی طرح زیادہ نہیں ہے عمومی طور پر انسان کے افعال واعمال کا واقعی محرک اس کا اپنے نفس سے لگاؤ اور عشق ہی ہوتاہے۔اس میں یہ جذبہ نہ ہوتاتو وہ کسی عمل کی طرف راغب نہ ہوتا۔اس کے علاوہ دوسرانکتہ بھی نظرمیں رکھنے کے قابل ہے نفس انسانی کے کسی بھی فطری جذبہ کو مکمل طور سے پامال نہیں کیاجاسکتا۔ورنہ
ایک دن فطرت پھر عادت پر غالب آجائے گی اور بلی،چوہے کو دیکھ کر شمع پھینک دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نظام حیات کا فریضہ ہلاکت نفس کو نہیں قرار دیاگیابلکہ اس کاکام تطہیر نفس اور تزکیۂ نفس رکھاگیاہے۔
بیشک سرمایہ داری اسی''حب نفس''کی بگڑی ہوئی شکل کانام ہے لیکن اس کی تطہیر کا طریقہ وہ نہیں ہے جسے مارکس نے اپنایاہے کہ انسان کے وجود سے''حب ذات'' کا جذبہ نکال کراسے''حب جماعت''کاجذبہ دے دیاجائے۔وہ پیدا ہوتو جماعت کے لئے۔کام کرے تو جماعت کے لئے۔محنت کرے تو جماعت کے لئے اور مرے توجماعت کے لئے۔ فکری اعتبار سے یہ جذبہ قابل قدر ہے اور یہ نظریہ انتہائی دل پسندو سنجیدہ ہے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس زمین پربسنے والے انسان میں یہ کیفیت پیدابھی ہوسکتی ہے یا نہیں؟اس کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے جذبہ کو اس سے سلب کیاجاسکتاہے یانہیں؟ اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو کھینچ کراسے زندہ بھی رکھاجاسکتاہے یا نہیں؟علم النفس کا تقاضہ اور فطرت کا مشاہدہ تویہی کہتاہے کہ یہ بات عالم خیال میں ممکن ہوتوہولیکن عالم حقیقت میں قطعی طورپر غیر ممکن ہے۔یہاں امکان صرف اس جذبہ کی تطہیر وتقدیس کا ہے جس کے وسائل پر غورکرنانظام زندگی کا سب سے بڑاکارنامہ ہے۔
دوسرااہم سوال یہ بھی ہے کہ''حب ذات''کے جذبہ کی تباہی یا اس کی تطہیر کے وسائل کیاہوں گے؟مارکس ازم کا کہنا ہے کہ یہ بات تعلیم وتربیت یاقہر وغلبہ کے ذریعہ پیداکی جاسکتی ہے۔انسان کو بچپنے ہی سے یہ تعلیم دی جائے کہ تجھے سب کے لئے پیداہونا ہے، سب کے لئے جینا ہے اور سب کے لئے مرجاناہے۔ایسی تعلیم کے مدارس قائم کئے جائیں۔گھروں میں اسی انداز سے تربیت کی جائے اور جوان ہونے سے پہلے پہلے انسان میں اس احساس کو جوان کردیاجائے تاکہ آگے چل کر اس کی نفسانیت ملکی قانون کی راہ میں حائل نہ ہوسکے اور پھر حکومت کی کڑی نگرانی میں اس کی زندگی کو آگے بڑھایاجائے۔تاکہ
اگرکسی مقام پر نفس قانون کی مخالفت پر آمادہ بھی ہوجائے تو حکومت کا دباؤ اسے راہ راست پر کھینچ لائے۔
یہ بات پہلے بھی واضح کی جاچکی ہے کہ خیالی دنیا میں یہ تصور انتہائی دلکش اور جاذب نظر ہے۔لیکن عالم حقیقت وواقعیت میں اس کو عملی جامہ پہنانا تقریباً ناممکن ہے۔ انسان اپنے ہرچھوٹے بڑے جذبہ کو قربان کرسکتاہے لیکن اس کے لئے ایسے بنیادی شعور کی قربانی ناممکن ہے جس پر اس کی ساری زندگی اور زندگی کے سارے اقدامات کا دارومدار ہے۔ طاقت کے دباؤسے ہر بات منوائی جاسکتی ہے لیکن کبھی کبھی طاقت کا استعمال ہی اپنی شکست کی دلیل بن جاتاہے ۔کسی نظام کو برسرکارلانے کے لئے طاقت کا استعمال اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ نظام کی بنیادیں نفس کی گہرائیوں میں نہیں اتری ہیں ورنہ اس زحمت کی ضرورت نہ پڑتی۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ طاقت کا استعمال خود بھی''حب ذات''کے جذبہ کی تکمیل کا ایک وسیلہ ہے تو کیا یہ بھی تسلیم کر لیاجائے کہ ایک شخص کی ذات محبت کے لائق ہے اور باقی افراد کی ہستیوں میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی نفسیات کے تجربے شاہدہیں کہ ایسے جذبات کو پامال کرنا نظام کی کمزوری کا پیش خیمہ ہوسکتاہے اور کچھ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے قانون میںاس جذبہ کا پورا(1)پورا احترام کیاہے۔اس کو اس کا واقعی مقام دیاہے اور اس کی تطہیر کا مکمل انتظام کیاہے ۔اس نے اپنے مخصوص افکارو نظریات کے تحت یہ فیصلہ کیاہے کہ ایسے خطرناک جذبہ کی تطہیر کاکام تربیت اور طاقت کے استعمال سے نہیں ہوسکتا۔فقیراس وقت تک روٹی کا مطالبہ کرتارہے گا جب تک اسے کسی بلند فکر سے قانع نہ بنایاجائے گا۔مظلوم اس وقت تک انتقام کے درپے رہے گا جب تک اسے انتقام کی طرف سے اطمینان نہ ہوجائے گا۔سرمایہ دار اس وقت تک جیب میں ہاتھ نہ ڈالے گاجب تک اسے اپنے پیسے کی حفاظت کے بارے میں اطلاع نہ ہوجائے گی۔کوئی بھوکا یامظلوم یا ثروتمند یہ کہہ دینے سے مطمئن نہیں ہوسکتاکہ تم سماج کے لئے پیداہوئے ہو۔اس
کے دل میں اپنے بارے میں صحیح فیصلہ سننے کا انتظار اور اس کی تڑپ ضرور باقی رہ جائے گی۔
(1)اسلامی عبادات میں قربت کی نیت اسی جذبۂ حب نفس کے احترام کی دلیل ہے۔ عبادات اللہ کے لئے ہونی چاہئے نہ کہ اللہ سے قریب ہونے کے لئے۔قریب ہونا خود ایک انسانی فائدہ ہے لیکن چونکہ انسان کا نفس حب ذات سے بلند نہیں ہوسکتاتھا اس لئے اسلام نے اس فیصلہ کو روارکھا اور اسی کو عام انسانوں کی معراج عبادت قرار دے دیا۔ورنہ حب ذات سے بلند نفوس قدسیہ کا جذبۂ عبادت ہوتاہے۔وہ قربت کے لئے عبادت نہیں کرتے بلکہ معبود کو اہل سمجھ کر سرجھکاتے ہیں۔ان کی نظر اپنے فائدہ پر نہیں ہوتی بلکہ مالک کی اہلیت پرہوتی ہے۔جیساکہ امیرالمومنین علی بن ابی طالب ـکے فقرات سے ظاہر ہوتاہے۔(جوادی)
اسلام نے اپنی تربیت میں اسی نکتہ کو پیش نظررکھا ہے۔اس نے مال کی آزادی دینے کے بعد ثروتمند کو یہ سمجھایاہے کہ یہ مال تمہارا ذاتی مال نہیں ہے۔یہ کسی مالک کی دین ہے جس نے تمہیں نمائش زر کے لئے نہیں بلکہ خدمت خلق کے لئے پیداکیاہے۔ تم تنہا ہی اس کے بندے نہیں ہوبلکہ تمہار اہمسایہ اور تمہارے سامنے بھوک سے ایڑیاں رگڑنے والا بھی تمہارے ہی مالک کا ایک بندہ اور تمہارے ہی خالق کی ایک مخلوق ہے۔خلقت کے رشتے سے تم دونوں برابر اور ایک دوسرے کے مال کے حقدار ہو۔تمہیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ آج تمہیں اتنی دولت دینے والا کل تم سے اس دولت کو سلب بھی کرسکتاہے۔تاریخ گواہ ہے کہ عامرعباسی نے مروان کو قتل کرنے کے بعد اس کے قصرمیں بیٹھ کر اس کا شام کا کھانا منگایا اور اس کی بیٹی کو سامنے بٹھاکر باپ کا سر بیٹی کی گود میں رکھ دیا تو ایک مرتبہ بیٹی نے جھلا کر کہا:اے امیر! یہ بات تیرے لئے جائے عبرت ہے جو دنیا میرے باپ کی جگہ تجھے بٹھاسکتی ہے وہ ایک دن اٹھابھی سکتی ہے۔عامر کے ہاتھ پیر میں رعشہ پڑگیا۔ یہ رعشہ در حقیقت اسلام کی اسی فطری تعلیم کا نتیجہ تھا جو اس نے ہر مسلمان کے لاشعور میں بطور امانت محفوظ کرادی ہے اور جس پر کردار کے پانی سے وقتاً فوقتاً جلاہوتی رہتی ہے۔
اسلام نے فقیروں اور مظلوموں کو یہ تسلی دی ہے کہ تمہارے فقر وفاقہ اور تمہاری مظلومیت کا سلسلہ غیر منقطع نہیں ہے۔ایک دن وہ ضرور آئے گا جب عادل حقیقی اپنی بساط عدالت بچھا کر دنیا کے معاملات کا فیصلہ کرے گا۔اس دن ظلم کرنے والے بیکس ہوں گے اور مظلوم کے دست وبازو مضبوط نظرآئیں گے۔تونے میری اجازت کے بغیر میرے حدود سے تجاوز کیااور اپنے جوش انتقام میں میرے نظام سے آگے بڑھ گیاتو میں نہ دنیا میں تیری کامیابی کا ذمہ دار ہوں اور نہ آخرت میں تیری توانائی کا۔تو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتاہے اور تجھے میرے وعدوں پر اعتبار نہیں ہے۔
''حب ذات'' کے جذبہ کی تطہیر صرف عقیدہ کی طاقت سے ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہ اس جذبہ کی تطہیر کرسکتی ہے اور نہ اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔
سرمایہ داری اسی''حب ذات''کی بگڑی ہوئی صورت کانام ہے جہاں انسان صرف اپنی ذات سے محبت کرتاہے اور دوسروں کوبالکل نظرانداز کر دیتاہے۔عقیدہ کی دنیا سے الگ ہوکر اس کا یہ تصور کسی حد تک صحیح بھی ہے اس نے اپنے نفس سے یہی سیکھاہے۔ اس پر کوئی ایسا ذہنی جبر عائد نہیں کیا گیا جس سے وہ اپنے کو نظرانداز کرکے دوسروں کے مفاد کے بارے میں سوچنے لگتا۔ ایک ثروتمند سے یہ تو کہاجاسکتاہے کہ تیرے ہمسایہ میں ایک بھوکا مر رہاہے،تیرے دروازے پر ایک بھکاری کھڑاہے لیکن(کسی بھی قانون کی رو سے) اس کی کمائی ہوئی روٹی کو اس کے دسترخوان سے اٹھاکر فقیر کو نہیں دیاجاسکتا۔یہ طاقت صرف دین اور اس کے مستحکم عقائد کی ہے۔اس نے اپنے عقیدتمندوں کو یہی سکھایا ہے کہ مال تمہارا ہے اور تم اللہ کے بندے ہو۔تمہارے ابنائے نوع بھی تمہارے ہی اللہ کے بندے ہیں اس لئے اپنے مال کو اس وقت تک اپنانہ سمجھو جب تک تمہارے خداکی مخلوقات میں کوئی بھوکارہ جائے۔کبھی کبھی یہ بھی سوچوکہ جوروٹی تم کھالیتے ہووہ فضلہ بن جاتی ہے۔جو غذا تم استعمال
کرلیتے ہو وہ تمہارے جسم کا جزء ضروربن جاتی ہے لیکن اسے ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنے کی ذمہ دار نہیں ہوتی اور اسی کے برخلاف جو کچھ راہ خدا میں دے دیتے ہووہ محفوظ ہوجاتاہے اور تمہارا خدا اس کے مقابلہ میں تمہیں بہت کچھ دے سکتاہے۔
مارکس ازم میں جبر وقہر کا عملی تصور اسی لئے پیداہواہے کہ اس کے پاس عقیدہ کی طاقت نہیں تھی۔وہ عقیدہ کو محرک سمجھنے کے بجائے ایک افیون تصور کررہاتھا۔اسے مذہبی طاقت کے مشاہدے اور دینی شعور کے تجربات کا موقع نہیں ملاتھا اس نے شروع سے اپنی فکر کا ایک نیاڈھرا بنالیاتھا اور اس کے برخلاف سوچنا ایک جرم سمجھتاتھا۔
مارکس ازم کا یہ خیال کہ سرمایہ دار کی بنیاد''ذاتی ملکیت''پر ہے، یقینا صحیح ہے لیکن سرمایہ داری کے عیوب ومفاسد کی ذمہ داریوں کو بھی''انفرادی ملکیت''کے سرتھوپ دینا یقینا غلط ہے ۔تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں جہاں بڑے بڑے ثروتمندوں اور سرمایہ داروں نے کردار کی اعلیٰ مثالیں پیش کی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ملکیت والے لوگوں نے بدکرداری کے بے مثل مظاہرے کئے ہیں جس کا کھلاہوا مطلب یہ ہے کہ سماج کے عیوب کی ذمہ داری ذاتی ملکیت کے سر نہیں ہے بلکہ اس کا چورانسان کے نفس کے اندرچھپاہواہے جب تک اس کی اصلاح نہ ہوجائے گی سماج کی اصلاح ناممکن ہے۔
عام طور سے یہ خیال کیاجاتاہے کہ مارکس کے معاشی نظام کو اس کے ذاتی عقائد سے الگ کرکے بھی اپنا یاجاسکتاہے لیکن یقینا یہ صرف ایک فریب اور مغالطہ ہے۔نظام زندگی اپنی پشت پر کام کرنے والے عقیدہ سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔مارکس ازم اور اسلام کے قانون کی جدائی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ اسلام''انفرادی ملکیت''کا حامی ہے اور سرمایہ دار کے نفس کی اصلاح عقیدہ کی بنیاد پر کرتاہے اور مارکس ازم ساری خرابیوں کا سرچشمہ''انفرادی ملکیت''کو قرار دیتاہے۔اس کے پاس انفرادی ملکیت سے پیداہونے والے مفاسد کو دبانے کے لئے عقیدہ کی طاقت نہیں ہے اس لئے وہ ایسی ملکیت ہی سے
انکار کر دیتاہے اور اس طرح ایک نیا جھگڑا پیداہوجاتاہے کہ سماجی خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے؟عقائدی نظام سرمایہ دارکو ذمہ دار قرار دیتاہے اور اشتراکی نظام ''سرمایہ داری''یعنی اس کی نبیاد''انفرادی ملکیت''کو۔عقائدی نظام سرمایہ دار کی نفسانیت کا علاج کرتاہے اور اشتراکی نظام''انفرادی ملکیت''کی بنیادوں کا ۔وہ تعلیم عقائد کاسہاراتلاش کرتاہے اور یہ جبر قانون کا۔
اس لئے اس مقام پر سب سے پہلے یہی طے کرنا ہوگاکہ فساد کی ذمہ داری کس کے سر ہے۔سرمایہ داری کے سریاسرمایہ دار کے سر؟اگر اس کی ذمہ داری سرمایہ داری کے سرہے تو حق اشتراکیت کے ساتھ ہے اور اگر اس کا ذمہ دارسرمایہ دار ہے تو حق اسلام کے ساتھ ہے فیصلہ کے لئے دو باتوں پر غور کرنا ضروری ہوگا۔
(1) فطرت کا تقاضا کیاہے؟اور فطرت سے جنگ کس حد تک ممکن ہے؟
(2) انجام بخیر کس کے حصہ میں ہے؟اور ترویج وتبلیغ کس کی ممکن ہے؟
فطری تقاضے کے بارے میں یہ واضح کیاجاچکاہے کہ''حب ذات''کے عمیق جذبہ کے تحت انسان میں عمل کا ذاتی محرک اسی وقت پیداہوتاہے جب اسے کام کے نتیجہ میں اپنے نفس کی تسکین کی کوئی صورت نظر آتی ہے اور وہ اس کام میں اپنا بھی کوئی فائدہ تصور کرتاہے۔انسان جو کسی بھی دینی یادنیوی عمل میں اپنا فائدہ نہیں سمجھتا۔اس سے کام لیاتوجاسکتاہے لیکن وہ خود فطری محرکات کی بناپر کام کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا۔یہ بات نہ کسی دلیل کی محتاج ہے اور نہ کسی برہان کی۔زمانہ کے حالات اور آئے دن کے مشاہدات اس مطلب کو ثابت کرنے کے لئے کافی ووافی ہیں۔
انجام کی صورت حال یہ ہے کہ''انفرادی ملکیت''کے معترف معاشرہ میں عمل کا محرک ذاتی ہوگا اور''اجتماعی ملکیت''کے قائل سماج میں عمل کا محرک حکمراں طبقہ۔اس لئے کہ اس کے یہاں یہ بات انسانی نفسیات کے خلاف ہے اور اس جذبہ کی تطہیر کے لئے کوئی
مافوق عقیدہ نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ''انفرادی ملکیت''کی صورت میں انسان خود مختار ہوگا اور ''اجتماعی ملکیت''کے معاشرہ میں ہرآن کسی نہ کسی جبر کا تصور ذہن میں لئے ہوگا۔
تیسرے بات یہ ہے کہ''انفرادی ملکیت''کے معاشرہ میں نوعیت عمل، زمان عمل، مکان عمل، وقت عمل کے تعین کا اختیار کام کرنے والے کے ہاتھ میں ہوگا اور ''اجتماعی ملکیت''کے سماج میں ان سب کا تعین حکمراں طبقہ کے حوالہ ہوگا۔
چوتھا فرق یہ ہے کہ''انفرادی ملکیت''کے معاشرہ میں انسان اپنی استعمالی چیزوں کو اپنے کدیمین کانتیجہ سمجھے گا اور''اجتماعی ملکیت''کے سماج میں انسان ہر چیز کو حکومت کا صدقہ تصور کرے گا اور ان دونوں تصورات کے نفسیاتی اثرات انسان کے عمل پر اثرانداز ہوں گے۔
ان امتیازات کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیاجاسکتاہے کہ کون سانظام حسن وخوبی، رفاہیت وسکون اور آزادیٔ فکر وعمل کے ساتھ چل سکتاہے اور کس نظام میں جبرواستبداد کی ضرورت ہوگی جس چیز کے بغیر اس نظام کی کامیابی ناممکن ہے؟
''اجتماعی ملکیت''کے سلسلے میں اس تنقید سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ میں سرمایہ داری یا اس کے مفاسد کی حمایت کرنا چاہتاہوں۔یہ طریقہ کارمیری نظرمیں انتہائی مہمل ہے۔ آج کے بعض مسلم مفکرین نے یہ طریقۂ کار ضرور اختیارکر لیا ہے کہ وہ اشتراکیت کی مخالفت میں سرمایہ داری کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ انداز اسلام کی کمزوری ظاہر کرنے میں زیادہ مدددے سکتاہے۔اسلام کے عروج وکمال سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔اسلام خود ایک مستقل نظام حیات رکھتاہے۔اس کا تعلق نہ سرمایہ داری سے ہے اور نہ اشتراکیت سے۔وہ سرمایہ دار نظام کی ''انفرادی ملکیت''سے ہم آہنگ ہے تو اشتراکی نظام کی بعض خوبیوں سے بھی اتفاق رکھتاہے۔لیکن اس نے اپنا نظام زندگی اس وقت پیش کیاتھا
جب نہ صرف سرمایہ داری تھی اور نہ اشتراکیت، اسے ان دونوں کی خوبیوں کا نچوڑ کہنا اس کی کھلی ہوئی توہین ہے۔اس کے بارے میں صرف یہ کہاجاسکتاہے کہ وہ ایک مکمل اور مستقل ضابطۂ حیات ہے۔اگر کوئی نظام اس سے ہم آہنگ ہوگاتو ہم اس سے اتفاق کریں گے اور اگر اس سے مختلف ہوگاتو کسی باطل اور غلط نظام کی موافقت سے معذور رہیں گے۔
اشتراکیت مقصد کے اعتبار سے سرمایہ داری سے کہیں زیادہ بہتر ہے لیکن اس نے اس مقصد کی تحصیل کے لئے قانون فطرت کے موافق کوئی طریقہ نہیں اختیار کیاہے۔ سرمایہ داری بھی اعلان حریت کے اعتبار سے فطرت سے کہیں زیادہ قریب ہے لیکن اس نے بھی حریت کے حدود کو بالکل نظرانداز کر دیاہے۔
آزادی؟
انسان کے فطری جذبات میں ایک جذبہ آزادی کا بھی ہے۔وہ اپنے داخلی محرکات میں کسی ایک محرک کی اہمیت سے کسی وقت بھی انکار نہیں کرسکتا۔لیکن تطہیر نفس کا تقاضہ یہی ہے کہ اس کی بڑھتی ہوئی آزادی پر پابندی لگائی جائے اور اس کے حدود قیودمتعین کئے جائیں۔سرمایہ داری نے اس جذبہ کا احترام ضرور کیاہے لیکن اس کے حدود کو بالکل نظرانداز کر دیاہے۔اس کا خیال ہے کہ انسان فطری طور پر آزاد پیداہواہے لہٰذا اجتماعی طور پر بھی اسے آزادہی رہنا چاہئے۔حکومت کو اس کی آزادی کی راہ میں سدراہ ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔حکومت کاکام عوام کے لئے اسباب ووسائل کا مہیا کرنا ہے نہ کہ ان کے مہیا شدہ اسباب و وسائل پرپابندی لگانا۔
سرمایہ داری کی یہ بات بظاہر بہت معقول ہے لیکن اس نے اس نکتہ کو فراموش کر
دیاہے کہ انسان فطری طورپر آزاد پیدا ہواہے۔اجتماعی طورپر آزاد نہیں پیداہوا۔اس کی زندگی میں دوقسم کے معاملات ہیں۔ایک کا تعلق اس کے انفرادی حالات سے ہے اور دوسرے کا تعلق اجتماعی معاملات سے۔انفرادی حالات کے اعتبار سے وہ بالکل آزاد ہے۔ اس پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جاسکتی لیکن اجتماعی معاملات میں کسی ایک انسان کو بھی آزاد نہیں کیاجاسکتا۔یہاں ہر شخص کو دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہوگا اور ہر شخص پر دوسرے ابنائے نوع کی زندگی کی ذمہ داری ہوگی۔یہاں فطری اور انفرادی آزادی سے اجتماعی آزادی پر استدلال نہیں کیاجاسکتا۔انفرادی اور اجتماعی حالات کی تشریح انتہائی تفصیل طلب ہے ہم اسے''علم اجتماع''کاموضوع سمجھتے ہیں اس لئے قاریٔ محترم کے ذہن پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے استدلال کو روزانہ کے مشاہدات وتجربات اور عقل سلیم کے فیصلے کے حوالے کئے دیتے ہیں۔
سرمایہ داری نے آزادی کی حمایت میں فطری جذبات کے احترام کے علاوہ ایک اقتصادی نکتہ بھی پیش کیاہے کہ آزاد معاشرہ میں ہرشخص حسب خواہش کام کرتاہے،حسب خواہش تجارت کرتاہے،حسب خواہش کارخانے قائم کرتاہے اور ہر شخص کو یہ خیال ہوتاہے کہ اپنے پیدا کئے ہوئے منافع سے ہمیں خود ہی مستفیض ہونا ہے۔وہ اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھاتاہے۔اقتصادیات میں ترقی ہوتی ہے اور ملک تیزی سے خوشحالی کی طرف بڑھ جاتاہے۔
بظاہر یہ بات بھی کچھ کم حسین نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اقتصادی مسئلہ کا مقصود فقروفاقہ اور عوامی تباہ حالی کو دور کرناہے یا ذرائع پیدا وارکا بڑھا دینا خواہ اس کا تعلق کسی ایک طبقہ ہی سے کیوں نہ ہو۔دنیا جانتی ہے کہ معاشیات کا علم عمومی بدحالی کو دور کرنے کے وسائل سے بحث کرتاہے اس کا مقصد کسی ایک طبقہ کے ذرائع آمدنی کو بڑھا دینا یا گھٹادینا نہیں ہے اور سرمایہ داری کی یہ فکر اسی ایک نکتہ کی طرف لے جارہی ہے۔اس فکر میں اقتصادی نشاط،
ذرائع پیداوار کی وسعت کا انتظام ضرور کیاگیاہے لیکن اس سرمایہ کے عوام تک پہنچنے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ۔اقتصادی نقطۂ نظر سے یہ فکر انتہائی مہمل ہے اور معاشیات کا علم کسی طرح بھی اس کی تائید نہیں کرسکتا۔
سرمایہ داری نے اس نکتہ کو بھی فراموش نہیں کیاہے اور ہمت کرکے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ انفرادی آزادی،اجتمالی خوشحالی کا وسیلہ بھی بن جاتی ہے انفرادی آزادی میں تاجروں ادرمل مالکوں کے درمیان باہمی مقابلہ ہوتاہے اور اس مقابلہ میں ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد سرمایہ مہیا کرنا پڑتاہے۔مزدوروں کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور انہیں بھی زیادہ سے زیادہ کام اور زیادہ سے زیادہ اجرت کے مطالبہ کا حق حاصل ہوجاتا ہے۔نتیجہ یہ ہوتاہے کہ ایک طرف ملک کی پیداوار بڑھتی جاتی ہے اور دوسری طرف مزدوروں کے حالات بھی بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں۔دوسرے لفظوں میں انفرادی آزادی، اجتماعی خوشحالی کا سبب بنتی جاتی ہے۔
سرمایہ دار مفکرین کا یہ مغالطہ کسی اور معاشرہ میں توصحیح بھی ہوسکتاتھالیکن آج کے ایٹمی اور بخاری دور میں انتہائی مضحکہ خیز معلوم ہوتاہے۔ان لوگوں نے عوام کو یہ فریب دیا ہے کہ کارخانوں کی ترقی سے مزدوروں کی ضرورت بڑھ جائے گی اور اس نکتہ کو نظرانداز کردیاہے کہ آج کے دور میں کارخانوں کی بڑھتی ہوئی ترقی مزدوروں کے دم قدم سے نہیں ہے بلکہ اس میں مشینری کی طاقت کام کرتی ہے جس کی وجہ سے مزدوروں کی ضرورت گھٹتی جارہی ہے اور ایک وقت وہ بھی آسکتاہے جب کارخانے سے مزدور یکسر نکال دیئے جائیں اور انفرادی ترقی اجتماعی خوشحالی کے لئے سم قاتل بن جائے۔مشینی دور میں ایک مصیبت یہ بھی آتی ہے کہ مشین میں کام کرنے کے لئے جوانوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی بلکہ یہ کام بچے،بوڑھے اور عورتیں تک کرنے لگتی ہیں اور اس طرح جوانوں کی بیکاری بڑھ جاتی ہے اور سرمایہ دار کو ان سے زیادہ سے زیادہ کام لینے کا موقع مل جاتاہے۔ان کی قسمت مکمل طور پر
ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ جتنا چاہتاہے کام لیتاہے اور جس قدرچاہتاہے مزدوری دیتاہے۔
سرمایہ دارانہ نظام سے محاسبہ کرنے میں سب سے بڑی دشواری یہ ہوتی ہے کہ اس نظام کی پشت پر کوئی فلسفہ یابنیادی فکر نہیں ہے۔یہ ایک چلتی پھرتی گاڑی ہے جس کے لئے ہر اسٹیشن سے کوئلہ پانی لیاجاسکتاہے۔اس کا کوئی مستقل فلسفہ ہوتاتو اسے زیر بحث لاکر اس کی اچھائی یابرائی کا فیصلہ کیاجاتالیکن جب کوئی بنیادی اصول ہی نہیں ہے تومذکورہ جوابات ہی پراکتفا کرلینا زیادہ مناسب ہے۔واقعی طور پر بحث صرف مارکس ازم کے ساتھ ہوسکتی ہے۔جس نے اقتصادیات کے اصول بھی متعین کئے ہیں اور انہیں اجتماعیات سے الگ کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور اس طرح دنیا کو ایک مکمل معاشی نظام سے آشنا کیاہے۔
٭٭٭
اسلامی معاشرہ(معیارِ قیمت )
ہماری گذشتہ بحثوں سے یہ بات واضح ہوچکی ہے کہ مارکس نے قیمت کے تعین میں صرف مزدور کی محنت کا حساب کیاہے اور اس کے علاوہ پیداوار کے جملہ عناصر کو نظرانداز کر دیاہے یا کھینچ تان کر کسی سابقہ محنت کا نتیجہ قرار دینے کی کوشش کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہواکہ کبھی ذخیرہ اندوزی کے حالات کو مستثنیٰ کرنا پڑاہے۔کبھی محنت کے معیار پر بحث کرنا پڑی ہے اور کبھی سپلائی اور مانگ کے توازن کو درست کرناپڑاہے۔اور ان سب کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑاہے جو ابتدائے امر سے غیر متوقع تھے۔
اسلام نے قیمت کا معیار متعین کرتے ہوئے زمینوں کی خدادادصلاحیت کو نظر انداز نہیں کیاہے۔اس نے مزدوروں کے جسم ودماغ کے باہمی تفاوت کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔اس کی نظر میں قیمت کے تعین میں یہ سارے عناصر کام کرتے ہیں۔مزدور کی محنت کا وقت بھی دیکھاجاتاہے۔کام کرنے والے کے حالات بھی پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ زمینوں کی صلاحیت پر بھی نگاہ رکھی جاتی ہے اور ان سب کے مجموعہ کو انسانی نفسیات کے معیار پر بھی تولا جاتاہے۔نفسیات کا فیصلہ ہی حرف آخر ہوتاہے اور اسی پر قیمت واجرت کے
تعین کا دارومدار ہوتاہے۔واضح لفظوں میں مارکس ازم میں قیمت کا معیار''محنت کی مقدار'' جس کاتعین عمل کے وقت ہی ہو جاتاہے۔اس لئے قیمت کا تعین بھی اسی وقت ہوسکتاہے لیکن اسلام کی نظرمیں قیمت کا معیار ''عمومی رغبت وتوجہ''اس لئے یہاں قیمت کا تعین اس وقت تک نہیں ہوسکتاجب تک چیز بازار میں نہ آجائے اور لوگ اس کے فائدہ ونقصان کو باقاعدہ سمجھ نہ لیں۔
اسلام نے متاع بازار کو''مال''سے تعبیر کیاہے اور مال کے معنی عربی زبان میں ''مایمیل اللّٰہ النفس''کے ہیں۔یعنی جس کی طرف نفس کا میلان اور اس کی رغبت توجہ ہو۔ظاہر ہے کہ جب مال کی تعبیر ہی توجہ ورغبت کی محتاج ہے تو جیسے جیسے رغبت میلان کے درجات میں فرق آتا جائے گا بازار کی قیمت بھی گھٹتی بڑھتی جائے گی اور وہ تمام اعتراضات بھی درمیان سے ہٹ جائیں گے۔جن سے مارکس کے نظریۂ قیمت کی بنیادیں متزلزل ہورہی تھیں۔
مارکس کے نظریہ پر پہلا اعتراض یہ تھاکہ اس نے فنون لطیفہ کو نظرانداز کردیاہے جن میں محنت زیادہ صرف نہیں ہوتی لیکن ان کی قدروقیمت بازار میں عام سماجی محنت کے نتائج سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔
اسلام کے سامنے یہ زحمت نہیں ہے۔وہ یک چشم نہیں ہے کہ دنیا کی ہر بات کو ایک ہی آنکھ سے دیکھے اور اسے معاشیات کے علاوہ کچھ اور دکھائی ہی نہ دے۔ا س نے کھل کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ فنون لطیفہ کا ذوق انسان کا فطری سرمایہ ہے جسے کسی وقت بھی اس سے سلب نہیں کیاجاسکتا۔''مہترانی ہوکہ رانی مسکرائے گی ضرور۔'' اسے نہ سرمایہ دار کی جاگیر ٹھہرایا جاسکتاہے اور نہ غربت زدہ عوام کی میراث۔اس میں پورا معاشرہ برابر کا شریک ہے۔ اس کی زیادہ قیمت لگانے میں بھی سرمایہ دار ذوق کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ عمومی رغبت کا ہاتھ ہے۔جیسے جیسے یہ رغبت بڑھتی جائے گی قیمت میں برابرا ضافہ ہوتاجائے گااور یہی وجہ
ہے کہ ایک ہی قسم کی حسین تصویر کسی سیاسی لیڈر یا مذہبی رہنما کی ہوتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور وہی تصویر کسی غیر متعلق شخصیت کی ہوتی ہے تو اس کی وہ قیمت نہیں لگائی جاتی۔ پہلی قسم کی جذبات واحساسات کا میلان زیادہ ہوتاہے اور دوسری قسم کی طرف کم۔
مارکس پر دوسرا اعتراض یہ تھاکہ اس نے آثار قدیمہ کی طرف توجہ نہیں دی۔جن پر آج کی بعض صنعتوں کی نسبت زیادہ محنت نہیں صرف کی گئی لیکن اس کے باوجود ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔
مارکس نے اس کا جواب بھی اقتصادی بنیادپر دیاتھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ تمام باتیں سرمایہ دار طبقہ کی انفرادیت پسندی کا نتیجہ ہیں۔ان لوگوں کا خیال یہ ہوتاہے کہ ہمارے یہاں وہ تمام چیزیں محفوظ رہیں جو عام افراد کے یہاں نہ ہوں تاکہ سماج میں ہماری شخصیت مرکز توجہ بنی رہے۔آثار قدیمہ بھی انہیں چیزوں میں سے ہیں جن کے ذریعہ انفرادیت کا مظاہرہ ہوسکتاہے۔اس لئے سرمایہ دار افراد ان کی قیمت بڑھاکر انہیں اپنے خزانہ کی زینت بنالیتے ہیں اور اس طرح اپنے جذبہ نفس کی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔
لیکن مارکس کی اس تاویل کا بھرم بھی اسی وقت کھل جاتاہے جب انسانی نفسیات پر بھی ایک ہلکی سی نظرڈالی جاتی ہے۔دنیا کا وہ کون سا انسان ہے جو اپنے سے متعلق آثار قدیمہ کی قدروقیمت کا انکار کرسکے اور اس پر زیادہ سے زیادہ پیسہ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ ایک تماشائی کو بابل ک کھنڈرات سے کوئی دلچسپی ہویانہ ہولیکن ایک''ماقبل تاریخ دور''کا محقق انہیں کھنڈرات پر اپنی ساری کائنات لٹاسکتاہے اور اپنی تحقیق کے اس سرمایہ کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ایک ملحدوبے دین انسان کو مذہبی آثار سے کوئی تعلق ہویانہ ہو لیکن مذہب سے ربط رکھنے والا مفلس ایک ایک اثر کے تحفظ پر اپنا گھر بار قربان کر سکتاہے۔
آثار قدیمہ کی مالیت اور ان کی قدروقیمت کو سرمایہ دارانہ جذبات کی تسکین کا ذریعہ کہنا ایک تجاہل عارفانہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔مارکس نے معاشیات کے سمندر میں
غوطہ لگاتے وقت انسان کے اخلاقی،سماجی،تحقیقی، مذہبی اور اجتماعی قسم کے تمام جذبات کو بالکل فراموش کر دیا ہے اور اس بات پر مطلق توجہ نہیں دی کہ اگر میری نظر میں روٹی ،کپڑے کے سوال کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو دنیامیں ایسے انسان بھی ہوسکتے ہیں جو اپنے مذہبی جذبات پر روٹی،کپڑابلکہ اپنی ساری کائنات لٹاسکتے ہوں اور اس کانہ سرمایہ داری سے کوئی تعلق ہو اور نہ مزدوری سے۔مذہب میں محمود وایاز ایک ہی صف میںکھڑے ہوتے ہیں وہ بندہ اور بندہ نوار کے فرق کو مٹادیا کرتاہے۔
مطبوعات کے مقابلہ میں مخطوطات کی اہمیت کاراز بھی عمومی رغبت وتوجہ ہی میں مضمر ہے چاہے اس توجہ کا سرچشمہ مذہب ہویا اخلاق،فلسفہ ہویاتمدن، معاشیات سے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔
رسدوطلب کا توازن بگڑجانے سے قیمت کے توازن پر اثرپڑجانے کا سبب بھی یہی نفسیاتی اصول ہے کہ انسان جس چیز کو بھی اپنی زندگی یا زندگی کے کسی جذبے کی تسکین کا ذریعہ سمجھتاہے۔اس کی فراوانی توجہ کو زیادہ مبذول نہیںکراسکتی۔پانی آزادی سے مل جاتا ہے ا س لئے مرکز توجہ نہیں بنتا۔سوناکم نظرآتاہے اس لئے اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک وقت وہ بھی آجاتاہے جب مخصوص حالات کے پیش نظر یہ انداز بدل جاتاہے اور قیمت کے معاملات بھی درہم برہم ہوجاتے ہیں۔صحرامیں پانی سونے سے زیادہ قیمتی ہوتاہے اور زکوٰة کے واجب ہوجانے کے بعد سونا پانی سے زیادہ ارزاں ہوجاتاہے کہ ایک مسلمان پانی دینے میں تکلف کر سکتاہے لیکن سونا دینے میں تامل نہیں کر سکتا۔اس کے علاوہ سیکڑوں مثالیں ہیں۔جہاں رسد اور طلب کا توازن قیمت پر اثر انداز ہوتاہے اور اس کی پشت پر کوئی معاشی نکتہ نہیں ہوتا۔
تقسیم
مارکس کے مذکورہ بالا نظریہ پر ایک اعتراض یہ بھی تھاکہ اگر قیمت کو پیداوار کا باعث صرف محنت کو قرار دیاجائے گا توقاعدہ کی رو سے صر ف انہیں لوگوں کو کھانے کا حق ہوگاجو محنت کر سکتے ہوں ۔کسی وجہ سے محنت سے عاجزہوجانے والے انسانوں کا قانونی طور پر کوئی حصہ نہ ہونا چاہئے۔حالانکہ یہ قطعی غلط ہے۔زندگی کا حق سب کو ملنا چاہئے۔اسلام نے اپنے نظریۂ قیمت سے اس عقدہ کو بھی حل کر دیا۔اس کے نظام میں مزدور کی محنت کے ساتھ خام مواد اور زمین کی صلاحیت کو بھی قیمت کی پیداوار میں بہت بڑادخل ہے۔اس لئے ساری پیداوار کو صرف مزدور کے حوالے نہیں کیاجاسکتا۔بلکہ ایک حصہ زمین کی صلاحیت کے پیدا کرنے والے کا بھی ہوگا۔جو اس نے اپنے غریب وعاجز اور کمزوروناتواں بندوں کے لئے مخصوص کردیاہے اور اس طرح اجتماع میں ایک توازن پیداکرنے کا صالح اقدام کیاہے واضح لفظوں میں یوں کہاجاے کہ افراد مملکت کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری مارکس نے بھی لی ہے اور اسلام نے بھی۔مارکس ایک کی ضرورت کو دوسرے کی پیداوار سے پوراکرنا چاہتاہے۔اور اسلام سب کی ضرورت کو رب العالمین کے دئے ہوئے ایک عطیہ سے۔مارکسیت میں غصب وسلب کا تصور پیدا ہوگیاہے اس لئے کہ اس نے زمین کے خالق کا انکار کرکے اس کے مالکانہ حق کو فراموش کر دیاہے۔اس کی نظرمیں پروردگارکا کوئی حصہ نہیں ہے اور مزدور کا سب کچھ ہے۔اسلام نے اپنے عقیدہ ''رب العالمین''و ''لہ الملک'' سے واضح کر دیاہے۔کہ زمین اللہ کی پیداکی ہوئی ہے اس کے نتائج میں اس کا بھی حصہ ہونا چاہئے اور یہی وہ حصہ ہے جو اس نے اپنے ضعیف وناتواں بندوں کے حوالے کیاہے۔جس کی تعبیر حدیث قدسی میں ان الفاظ سے ہوئی ہے:''فقراء میرے عیال ہیں
اور مالدار میرے وکیل۔''
لفظ وکیل کاا ستعمال بتارہاہے کہ مالدار بھی اپنے پورے مال کا مالک نہیں ہے اس کے مال میں بھی کچھ حصہ پروردگار کا ہوتاہے۔جسے اس نے اپنے غریب بندوں تک پہنچانے کے لئے اس کو اپنا وکیل بنایاہے۔بلکہ لفظ وکیل سے اس نکتہ کی بھی وضاحت ہوجاتی ہے کہ اگر پروردگار عالم کو اپنے غریب بندوں کا رزق مالداروں کی پیداوار سے دلوانا ہوتاتو وہ انہیں وکیل بنانے کی ضرورت محسوس نہ کرتابلکہ کسی اور وسیلے سے غرباء تک پہنچادیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیاجس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شروع ہی سے مالداروں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ آپ پوری پیداوار کے مالک نہیں ہیں۔آپ اپنی مزدوری بھر حصہ لے سکتے ہیں۔باقی زمین کا حصہ ہماراہے جو ہمارے بندوں کو ملنا چاہئے۔
اس مقام پر یہ خیال نہ کیاجائے کہ زیر زمین چھپے ہوئے جواہرات کی اس وقت تک کوئی قیمت نہیں ہوتی جب تک اس پر انسانی محنت صرف نہ ہوجائے اس لئے قیمت کا خالق تومزدور ہی ہے ۔کسی اور کے حصہ دار بننے کا کیاسوال پیداہوتاہے؟اس لئے کہ کسی شیء کا وسیلہ ہونا اور ہے اور خالق صلاحیت ہونا اور۔مزدور کی محنت زمین کے جواہر کے اظہار کا وسیلہ ضرور ہے۔لیکن زمین کی استعداد کی خلاق نہیں ہے زمین کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا حق ان کے حقدار کو بہرحال ملنا چائیے۔
اسی طرز فکر سے سرمایہ داری کے فساد کا بھی قلع قمع ہوجاتاہے جسے مارکس کی ہزار فلسفیانہ موشگافیاں رفع نہ کرسکیں۔اس نے سرمایہ داری کو''انفرادی ملکیت''کا نتیجہ قراردے کر اس کو مٹانے کی فکر شروع کر دی اور بالآخر ہزار تجربات کے بعد بھی کسی نہ کسی مقدار میں اس کا اعتراف کر لینا پڑا۔اسلام نے اس مسئلہ کو روز اول ہی حل کر لیا تھا۔اس کا قانون تھا کہ ہر انسان اپنی ذاتی ملکیت کا مالک ہے اس پرکوئی جبرعائد نہیں کیا جاسکتاہے۔اسے صرف اتنا پیش نظررکھنا چاہئے کہ وہ صرف اپنی پیداوار یعنی اپنی محنت کے نتیجہ کی ملکیت میں
آزاد ہے۔دوسرے کے مال کو غصب کرنے کا مجاز نہیں ہے۔اس کی محنت کا نتیجہ اس کا ہے لیکن زمین کی صلاحیت واستعداد کا نتیجہ اس کا نہیں ہے۔اس لئے اس میں تصرف کرنے کے لئے اسے مطلق العنان نہیں بنایاجاسکتا۔
مارکس ازم کوعقائد سے الگ کرکے دیکھنے والے اشتراکی مسلمان اس نکتہ پر غور کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ کوئی معاشی نظام اس کے مخصوص نظریات وعقائد سے الگ کیا جا سکتاہے یا نہیں؟
انفرادی ملکیت
اسلامی اقدار ومفاہیم سے ناآشنا اربابِ قلم اپنی تحریر کی رومیں یہ بھی لکھ جاتے ہیں کہ اسلام واشتراکیت کا فرق صرف یہ ہے کہ اشتراکیت''انفرادی ملکیت''کی علمبردار ہے اور اسلام اس کے مقابلہ میں''انفرادی ملکیت''کا پرستار۔حالانکہ یہ خیال ایک عمومی شہرت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔اسلامی تصریحات اس سے قطعاًبیگانہ وبے تعلق ہیںاور حقیقت یہ ہے کہ ملکیت کے سلسلہ میں اسلام کا موقف اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں سے الگ ہے۔اشتراکیت نے ملکیت کا قانون مارکس کے مخصوص اقتصادی نظریات کی روشنی میں مرتب کیاہے۔سرمایہ داری نے ملکیت کو فطری آزادی کا نتیجہ قرار دیاہے اور اسلام نے ملکیت کا قانون بناتے وقت دواہم بنیادی نکات کو مرکزنظربنایاہے۔
(1)عقیدۂ توحید
(2)اقسامِ اراضیات
(1)عقیدۂ توحید:
عقیدۂ توحید کے تحت یہ فیصلہ کیاگیاہے کہ زمین اور اس کی تمام نعمتیں آسمان اور اس کی تمام برکتیں ایک ذات واجب کی نظرعنایت کا صدقہ ہیں۔اس نے اس کائنات کو پیداکرکے ایک اشرف المخلوقات نوع کی ترقی کا وسیلہ بنادیاہے اور اسے کائنات سے استفادہ کرنے کی پوری پوری اجازت دے دی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھادیا ہے کہ زندگی کے کسی لمحہ میں اور معیشت کے کسی میدان میں اس ذات کو فراموش نہیں کیاجا سکتاجس نے ان تمام نعمتوں کی بارش کی ہے اور جس کی نگاہِ لطف کے اشارے سے یہ پوری کائنات قائم ودائم ہے۔
(2)اقسامِ اراضیات:
اقسامِ اراضیات کے سلسلہ میں''اسلامی قانون''ملکیت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس زمین کا جائزہ لیتاہے جس کی ملکیت کا قانون وضع کیاجارہاہے اس کے یہاں انفرادی ملکیت ے ساتھ عموعی ملکیت اور حکومتی ملکیت جیسے مختلف تصورات بھی موجود ہیں اور ہر ایک کے لئے الگ الگ موردتلاش کیاگیاہے۔اس نے مطلق طورپر ہر چیز کو نہ اجتماعی ملکیت قرار دیاہے نہ انفرادی ۔زمینوں کی اس تقسیم کا فلسفہ یہ ہے کہ بعض زمینیں عام انسانی دسترس سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں جیسے بلندیٔ کوہ دامنِ کوہ،قعردریاوغیرہ۔
ایسی زمینوں کو خالص اسٹیٹ قرار دیا گیاہے۔بعض زمینیں کسی جہاد کے نتیجہ میں فوج مخالف کے قبضہ سے نکالی جاتی ہیں۔ان میں سے بھی بعض آباد ہوتی ہیں اور بعض بنجر۔ آباد زمینوں کی ملکیت کا قانون الگ ہے۔اور بنجر زمینوں کی ملکیت کا قانون الگ۔ بنجر زمینیں مکمل طورپر محنت کی محتاج ہوتی ہیں اس لئے انہیں ان زمینوں کا ہمسر نہیں قرار
دیاجاسکتاجن پر انسانی محنت صرف ہو چکی ہے اور جنہیں دشمن فوج کی آبادی نے کسی حدتک معمور بنالیاہے۔انفرادی ملکیت کے لئے صرف ان زمینوں کو مخصوص کیاگیاہے۔جو دوست ودشمن اور جنگ وجہاد کے تصورات سے الگ ہوکر انسان کے قبضہ میں آتی ہیں۔
باقی زمینوں کے لئے حالات اور مواقع دیکھ کر قوانین وضع کئے گئے ہیں۔ مارکسیت اور سرمایہ داری نے زمینوں کی اس تقسیم کو بالکل نظرانداز کر دیاہے۔حالانکہ کم ازکم مارکس کو اس تقسیم کو پیش نظررکھنا چاہئے تھا اور ملکیت کا فیصلہ کرتے وقت یہ نکتہ نظرانداز نہیں کرنا چاہئے تھاکہ انفرادی زحمت سے انفرادی ملکیت پیداہوتی ہے اور اجتماعی محنت سے اجتماعی ملکیت۔محنت کی اہمیت کے اعتبار سے اسلام اور اشتراکیت دونوں متحد تھے لیکن آگے چل کر دونوں کا راستہ الگ ہوگیا۔اشتراکیت نے زمینوں کی آباد کاری کے سلسلہ میں اجتماعی اور انفرادی محنت کو یکساں کردیا۔اور اسلام نے دونوں کے تفاوت کو باقاعدہ پیش نظر رکھا۔ اور اسی لئے اس نے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا:
(اَلنَّاسُ مُسَلِّطُوْنَ عَلیٰ اَمْوَالِهِمْ)
لوگ اپنے اپنے مال پر پورا پورا اختیار رکھتے ہیں۔
قرآن مجید کی متعدد آیتوں نے بھی نتیجۂ عمل کو افراد کی طرف منسوب کرکے یہ واضح کردیاہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے نتیجۂ عمل کا مالک ہوتاہے ۔کسی دوسرے شخص کو اس کے عمل اور اس کی محنت میں حصہ دار بننے کا حق نہیں ہے۔
سرمایہ داری کا فساد
مارکسیت اور اسلام کا ایک امتیازی نقطہ یہ بھی ہے کہ دونوں نے سرمایہ داری کے مفاسد کے اسباب کی تعین میں الگ الگ راہیں اختیار کی ہیں اور اس مہلک مرض کا علاج
بھی علیحدہ تجویز کیاہے۔مارکسیت کی نظرمیں سرمایہ داری انفرادی ملکیت سے پیداہوتی ہے۔ اس لئے اس کے ختم کرنے کا واحد ذریعہ ''انفرادی ملکیت'' کے تصور کو باطل یا محدود بناکر اس کے بڑے حصے کو اجتماعی ملکیت میں تبدیل کر دینا ہے اور اسلام کی نظر اس سے بالکل مختلف ہے۔وہ ان تمام خرابیوں کی ذمہ داری انفرادی ملکیت کے سرنہیں ڈالتاہے بلکہ اس کی نظرمیں سرمایہ داری کی پیداوار اس کی مفاسد ''انفرادی ملکیت''کے قانون سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہوتے ہیں ۔انفرادی ملکیت اپنی راہوں پر چلتی رہے تو یہ مفاسد کسی وقت بھی پیدا نہیں ہوسکتے۔
اس مقام پر سب سے زیادہ حیرت انگیز موقف مارکس کا ہے جس نے''محنت'' کو قیمت اور ملکیت کی بنیاد تسلیم کرنے کے بعد بھی سرمایہ داری کے خاتمہ کی کوئی بہتر صورت نہیں نکالی اور محنت کرنے والے کی اس کے نتیجۂ عمل سے محرومی ہی کو وجہ عافیت تصور کیاہے۔ حالانکہ سرمایہ داری کے مقابلہ میں مارکس کا صحیح موقف یہ تھا کہ ہر انسان اپنے نتیجۂ عمل کا مالک ہو۔اسے تجارت،کاروبار اور اس قسم کے جملہ اقدامات کا اختیار دیاجائے تاکہ اس کا سرمایہ دو چند یادہ چند ہوسکے اور ان تمام اضافوں سے روک دیاجائے جس میں اس کی کوئی محنت شریک نہ ہو۔مارکس کے اس بنیادی قانون سے غفلت کا نتیجہ یہ تھاکہ اسے اپنے سیدھے سادھے قانون میں ذہنی اجبار یا خارجی دباؤ کو شامل کرنا پڑا۔اور قانون اپنے راستے سے ہٹ گیا اسلام عمل کی اہمیت کا آخر تک قائل رہا۔اس لئے اسے کسی جبر واکراہ کا سہارا نہیں لینا پڑا۔
ذخیرہ اندوزی
اسلام نے ثروتمند افراد کو ہر کاروبار کی کھلی اجازت دینے کے باوجود ''ذخیرہ اندوزی''کو ایک جرم عظیم قرار دیاہے اس کا راز صرف یہ نہیں ہے کہ اس طرح سماج کا غلہ چند گھروں میں محفوظ ہوجائے گا اور عوام بھوک سے تباہ ہونے لگیں گے یہ تو ایک اخلاقی نکتہ ہے جسے اقتصادیات سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا راز یہ ہے کہ ذخیراندوزی کرنے والا فصل پر غلہ خرید کرایک مقام پر محفوظ کرلیتاہے اور جب چھوٹے چھوٹے تا جروں اور کسانوں کا غلہ ختم ہوجاتاہے تو اسے منظر عام پر لاکر دگنی اور چوگنی رقم وصول کرتاہے۔ظاہر ہے کہ جس نظام نے سرمایہ کی اصل محنت کو قرار دیاہے وہ اس طرز عمل سے اتفاق نہیں کرسکتا کہ مال کی قیمت کسی محنت کے بغیر بڑھے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا اپنے مال کو بغیر کسی محنت ہی کے بڑھانا چاہتاہے۔اس مقام پر یہ نہیں کہاجاسکتاکہ مال کی حفاظت بھی ایک انسانی محنت ہے لہٰذا اس کا بھی حساب ہونا چاہئے۔اس لئے کہ علم اقتصادیات میں محنت سے مراد زحمت نہیں ہے ورنہ کھانا پینا بھی ایک محنت ہے اور بینک میں روپیہ رکھنا اور اس کا نکالنا بھی ایک محنت ہے بلکہ محنت سے مراد وہ جدوجہد ہے جو سرمایہ کی ترقی کے سلسلہ میں صرف کی جائے۔ حفاظت پر صرف ہونے والی محنت کو اقتصادی محنت نہیں کہاجاسکتا۔اس سے پیداوار میںکسی اضافہ کا امکان نہیں ہے۔تجارت کی محنت سرمایہ کی ترقی کا باعث ہوتی ہے اس لئے وہاں قیمت میں اضافہ کیاجاسکتاہے۔اس کے علاوہ خود سرمایہ دار ممالک بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان اپنے معاملات میں اسی حد تک آزاد کیاجاسکتاہے جب تک اس کی آزادی سے معاشرہ کے دوسرے افراد متاثر نہ ہوں۔اور ظاہر ہے کہ یہاں آزادی کو دوسرے افراد کے متاثر بنانے ہی کی راہ میں صرف کیاجارہاہے۔اس لئے ایسی آزادی پرپابندی عائد
کرنا قانون اور حکومت کا اولین فرض ہے۔
سود
سرمایہ کے اضافہ کی دوسری ناجائز صور ت ہے سود۔سود کے ناجائز ہونے میں بھی وہی دونوں اقتصادی اور اخلاقی عناصر کارفرماہیں۔اقتصادی اعتبار سے دولت کا اضافہ محنت کے زور پرہونا چاہئے اور اخلاقی اعتبار سے محنت کو اجتماع کی صلاح پر صرف ہونا چاہئے۔معاشرہ کی بربادی کو اس کا ہدف ومقصد نہیں بننا چاہئے اور سود میں یہ تمام باتیں قہری طور پر پائی جاتی ہیں۔
سود خواری کا ایک اہم عیب یہ بھی ہے کہ سود خوارتاجرزیادہ ہوتاہے اور آدمی کم۔ اس میں انسانی اخلاق وکردار کا فقدان ہوجاتاہے اور اس کے سامنے پیسے کے علاوہ کوئی دوسرا مطمح نظر نہیں رہ جاتا۔اسلام اس نظریہ سے دو جہتوں سے اختلاف رکھتاہے۔وہ ایک طرف انسان کو انسان دیکھنا چاہتاہے اور اس کا مقصد ہے کہ ہر دل میں قوم کا دردر ہے اور ہر انسان دوسرے کے رنج وغم اور دکھ درد کا پاس ولحاظ رکھے۔جبکہ سودخوار اپنی مقررہ مدت کے پورے ہوجانے کے بعد رحم وکرم کے تمام مفاہیم کو فراموش کر دیتاہے۔وہ ہر امکانی طریقہ سے اپنا سود چاہتاہے اب گھر بکتاہے تو بک جائے،بچے فاقہ سے مررہے ہیں تو مرجائیں لیکن سودمل جائے اور اگر کسی سور خوار میں اتنی شقاوت نہیں بھی ہے تو وہ یہ بہرحال نہیں کرسکتا کہ انسان کی مجبوری کے پیش نظر اس مہینہ یا اس سال کا سودمعاف کردے۔وہ اپنے حساب کو بڑھاتاہی رہے گاچاہے رقم کسی منزل پر کیوں نہ پہنچ جائے۔
دوسری طرف اسلام نے اس پہلو کو بھی نظرانداز نہیں کیاکہ انسان اپنے سماجی حالات کا اسیر ہوتاہے۔معاشرہ میں کوئی شہزور ہوتاہے اور کوئی کمزور،کوئی غنی ہوتاہے اور کوئی فقیر، کوئی ذہنی نشاط رکھتاہے اور کوئی غبی وکندذہن ہوتاہے۔اس لئے ہر ایک کے ساتھ اسی کے حالات کے مطابق برتاؤ ہوناچاہئے۔کسی پر کوئی دباؤ ڈالنا انسانی شرافت وغیرت کے خلاف ہے۔سرمایہ دار کو اللہ نے پیسہ دیاہے تو کھائے عیش کرے،لطف اٹھائے،جو چاہے کرے لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی عزت کا مذاق اڑائے، اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے، اسے اپنی دولت کے شکنجہ میں جکڑلے اور اس پر ایسے حالا ت کا بوجھ ڈال دے کہ وہ سراٹھانے کے لائق نہ رہ جائے۔
اسلام اور سودخواری کے نظام میں اتنا فاصلہ ہے کہ اسلام اصل قرض کے بارے میں بھی یہ تعلیم دیتاہے کہ اگر قرض دار کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس سے مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
(وَإنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة ِلَی مَیْسَرَةٍ)
اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو اس کی کشائش حال کا انتظار کرنا چاہئے۔ (بقرہ/280)
اور نظام سودخواری کا یہ تقاضہ ہے کہ اصل مال کجاسود بھی معاف نہ ہوناچاہئے۔ ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ان اعلیٰ اقدار ومفاہیم سے کسی طرح ہم آہنگ نہیں ہوسکتاجن پر اسلام نے اپنے احکام وتعلیمات کی بنیاد رکھی ہے۔
بینک
سود کے سلسلہ کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر سود کا کاروبار ختم کر دیاجائے گا تو بینک کا سارا نظام درہم برہم ہوجائے گا اور ملک کی آبادی،عوام کی خوشحالی کا کوئی امکان نہ رہ جائے گا۔پھر سود میں جو بھی اقتصادی یا اخلاقی خرابی فرض کی گئی ہے وہ سود لینے سے متعلق ہے کہ سرمایہ دار کا سود لینا مناسب نہیں ہے لیکن اس سے یہ کہیں ظاہر نہیں ہوتاکہ سرمایہ دار کے لئے سود دینا بھی جائز نہیں ہے یا اس میں بھی کوئی اقتصادی یا اخلاقی کمزوری ہے۔اور بینک کا سارا نظام سرمایہ دارکے سوددینے پر ہی چلتاہے سودلینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
بینک کے نظام کی صحت کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ بینک کا مالک عوام سے روپیہ جمع کرکے اس سے بڑی بڑی تجارتیں کرتاہے اور یہ تجارتیں اکثر حالات میں منفعت بخش اور مفید ثابت ہوتی ہیں اس لئے مالک اس بات کو گوارانہیں کرتاکہ عوام کے پیسے سے ملنے والے فائدہ کو تن تنہا ہڑپ کرجائے بلکہ ان تمام حصہ داروں کو شریک کرنا چاہتاہے جن کے پیسے سے یہ فائدہ حاصل ہواہے۔
ایسے اخلاقی اور سود مند اقدام کی ممانعت کسی طرح مناسب نہیں ہوسکتی ۔اس نظام کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس طرح غریب عوام کو اپنا سرمایہ بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے۔وہ بھی اپنی قلیل رقم سے اس بڑی تجارت میں حصہ لے سکتے ہیںجوبینک کے بغیر ممکن نہ تھی۔ان کی تھوڑی رقم بھی تھورے عرصہ میں دگنی ہو سکتی ہے۔جو بینک کا سہارا لئے بغیر کبھی نہیں ہوسکتی تھی۔بینک کا کاروبار جہاں سرمایہ دار کی دولت میں اضافہ کا سبب ہوتاہے وہاں غریب عوام کے لئے بھی فائدہ بخش ہوتاہے۔یہاں محنت اور قیمت کے توازن کا سوال بھی نہیں اٹھ سکتااس لئے کہ ایک جماعت کا پیسہ ہوتاہے اور ایک جماعت کی محنت۔اب اگر
عوام کو اپنے مال کا فائدہ لینے کا حق ہے تو سرمایہ دار کو اپنی محنت کا پھل بھی ملنا چاہئے۔
اس پوری توجیہہ وتشریح کے باوجود بینک کے سلسلہ میں دوباتیں تشریح طلب ہیں۔
(1) بینک کا مالک اگراپنی شخصیت کو صرف ایک محنت کش مزدور اور ایک ایجنٹ کی شکل میں پیش کرتاہے تو اسے یہ حق کسی طرح نہیں دیاجاسکتاکہ وہ مالک کے تمام حقوق وفرائض کو اپنے ذمہ لے لے۔ایجنٹ کاکام تجارت کرکے اپنی محنت کی اجرت لینا ہوتاہے۔اس کا یہ حق نہیں ہوتاکہ وہ تجارت سے حاصل ہونے والے فائدہ میںمالک کا حق معین کرے۔اور بینک کے کاروبار میں بعینہ یہی شکل ہوتی ہے۔یہاں مالک بینک ہی یہ طے کرتاہے کہ روپیہ جمع کرنے والوں کو کتنی مقدار میں سودیعنی فائدہ دیاجائے گا۔
سوال یہ ہے کہ کسی کے مال میں فائدہ کے معین کرنے کا حق اس کے مزدور کو کیسے مل سکتاہے؟اور پھر وہ بھی قبل ازوقت آج آپ نے اپنا سرمایہ بینک کے حوالے کیااور مالک نے آج ہی یہ فیصلہ کردیاکہ آپ کو اتنے فیصد فائدہ دیاجائے گا۔
مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ فائدہ میرے ہی مال کا ہے تو ابھی میرا مال بینک سے باہر بھی نہیں نکلا۔اس کے سال بھرکے بعدکا فیصلہ اسی وقت سے کیونکر ہوگیا اور اگر یہ فیصلہ سرمایہ دار نے اپنے ذاتی پیسے یادوسروں کے پیسے کی بنیادپر کر دیا ہے تو وہ ہمارے پیسے سے تجارت کرنے کا ایجنٹ نہیںہے۔بلکہ اپنے پیسے سے ہمارے پیسے کو خریدرہاہے یا ہمارے پیسے کو ایک سال کے لئے8۔10فیصدی کرایہ پر لے رہاہے جو درحقیقت اس تقریر سے بالکل مختلف ہے جو بینک کے جوازمیں کی گئی ہے۔پھر یہ بھی بحث طلب مسئلہ ہے کہ پیسے کو زیادہ پیسے پر بیچنا یاپیسے کو کرایہ پر اٹھانا صحیح بھی ہے یا نہیں۔جس پر حسب موقع آئندہ روشنی ڈالی جاسکتی ہے۔
(2) بینک کا مالک اگر عوام کے پیسے سے تجارت کرنے میں ان کا ایجنٹ ہے اور واقعاً عوام ہی اس کے مالک ہیں تو فائدہ ونقصان کی ذمہ داری بھی عوام ہی کے سرہونی چاہئے۔یہ غیر ممکن ہے کہ سوروپیہ جمع کرنے والا سال بھر کے بعد ایک سو پانچ لے کر الگ ہوجائے چاہے تجارت میں فائدہ ہو یا نقصان،اس لئے کہ اس سلسلہ میں اگر کوئی فائدہ ہواہے تو وہ بھی اسی کے مال سے اور اگر کوئی نقصان ہواہے تو وہ بھی اسی کے سرمایہ میں ہے۔ایسی حالت میں ایجنٹ کے نقصان برداشت کرنے کاکیا جواز ہے۔بینک کے نظام کی ان ہی خرابیوں کے پیش نظر اسلام نے ایک نیااصول یہ پیش کیاہے کہ بینک کا ذمہ دار پیسے جمع کرکے تجارت کرے اور فائدہ ونقصان کا کوئی فیصلہ نہ ہو۔تجارت کا سال ختم ہونے کے بعد فائدہ کا حساب کیاجائے۔اور جتنی مقدار میں اضافہ ہواہواسے حسب حصہ تقسیم کرلیاجائے۔تجارت میں نقصان کی کوئی ذمہ داری ایجنٹ پر نہ ہو۔اس لئے کہ وہ صرف دیانت داری سے کام کرنے کا ذمہ دار ہوتاہے۔اسے نہ مال ومتاع سے کوئی تعلق ہوتاہے اور نہ اس کے فائدہ ونقصان سے اور ظاہر ہے کہ یہ توجیہ وتعلیل آج کے نظام بینک سے بالکل مختلف ہے۔
بینک کے سلسلہ میں یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے کہ یہ ساری گفتگوان لوگوں کے پیسے کے بارے میں ہے جوبینک کے قائم ہوجانے کے بعد اس میں تحفظ اور اضافہ کی غرض سے رقم جمع کرتے ہیں۔رہ گئے وہ لوگ جن کی رقم سے بینک قائم ہوتاہے۔مثلاً اصلی سرمایہ دار یا وہ لوگ جو بینک کے SHAREHOLDER یا حصہ دار ہوتے ہیں۔جن کا کام سود تقسیم کرنا اپنے پیسے کے ساکھ پر معاملات کرنا،چیزوںکو رہن رکھنا،عالمی بینک میں پیسہ جمع کرنا اور تجارت وغیرہ ہوتاہے۔ان کے بارے میں لمحۂ فکر یہ یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان منافع کی تقسیم کس معیار اور کس انداز پر ہوگی۔ان کے کاروبار پر اس لحاظ سے نظرہوگی کہ انہوں نے دوسروں کی رقم کے ساتھ وہ قانونی سلوک کیوں نہیں کیاجو علم اقتصادیات کی رو سے
ہوناچاہئے تھایاکہ ان کا سرمایہ کس انداز سے جمع ہواہے اور اس کے جواز وغیرجوازکے ذرائع کیاتھے؟اس پورے سرمایہ میں ان غربت زدہ عوام کا کیا حصہ ہے جو اس دولت کے جمع ہوجانے سے بھوکے مررہے ہیں۔جن کی زندگی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ انہیں بینک میں جمع کرکے ان کے رحم وکرم کے مستحق بن سکیں۔
حیات وکائنات
حیات وکائنات پر الگ الگ بحثیں توبہت ہوئی ہیں ان موضوعات پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ان مسائل کے لئے فلسفہ، نفسیات،فزیالوجی جیسے علوم مرتب کئے گئے ہیںلیکن ان دونوں کے باہمی رشتے کو اس انداز سے کم قابل توجہ سمجھاگیاہے جس سے اقتصادی مسائل حل ہوسکتے۔حیات وکائنات کے فلسفی تعلقات سے قطع نظران کے اقتصادی ربط کو اس انداز سے سمجھاجاسکتاہے کہ فطرت یا قدرت نے یہ کائنات اسی انسان کی خاطر پیداکی ہے جو کچھ اس کائنات میں ہے سب اسی خاص مخلوق کے لئے ہے۔ہر فرد بشر کو اس کائنات سے استفادہ کرنے کا پوراپورا حق ہے چاہے وہ عالم ہویاجاہل،ضعیف ہو یا طاقتور، ذہین ہو یا غبی، گوراہویاکالا،لمباہویاپستہ قد،کچھ بھی اور کیسا بھی ہواگر اس کائنات سے تعلق رکھتاہے تو اس کا ایک حصہ ہونا چاہئے۔فطرت کا یہ کتنا بڑاظلم ہوگاکہ باشندے زیادہ پیداکردے اور زمین کم،پیاسے زیادہ ہوں اور پانی کم،بھوکے زیادہ ہوں اور غذاکم ایسا نہیں ہوسکتا۔
فطرت نے کائنات میں وہ سب کچھ بھردیاہے جو بنی نوع انسان کے لئے
ضروری اور لازمی تھا۔اس نے اپنے فیوض میں کوئی کوتاہی اور اپنی عطامیں کوئی بخل نہیں کیا۔ اب ان فیوض وبرکات سے فائدہ اٹھانا انسان کا اپنا کام ہے وہ چاہے تو ساری کائنات کی تسخیر کرے اور چاہے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے اور ایک وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہ کر سکے۔
حیات وکائنات کا یہ رشتہ اس بات کا کھلاہوااعلان ہے کہ دنیامیں فقروفاقہ غربت وافلاس کا سبب فطرت کی کوتاہی یا اس کا قصور نہیں ہے۔اس میں تمام ترانسان کی غفلت، اس کی کاہلی اور اس کے ظلم وتعدی کا دخل ہے۔اس نے اس نکتۂ تخلیق کو فراموش نہ کیاہوتا اور اپنے علاوہ دوسروں کو بھی جینے کا حقدار سمجھاہوتاتو آج دنیا کی وہ حالت نہ ہوتی جس سے یہ دنیا گذررہی ہے۔آج تویہ بات ببانگ دہل کہی جاسکتی ہے کہ فقر وفاقہ اور غربت وافلاس میں جہاں سرمایہ داروں کے مظالم کا حصہ ہے وہاں انسانوں کے ہوس اقتدار کا بھی کچھ کم دخل نہیں ہے۔قدرت نے انسانوں کو پوری زمین پر بکھرایاتھا تو ان کے لئے نعمتیں بھی سارے کرۂ ارض پر بکھیردی تھیں۔خدا براکرے اس ہوس اقتدار کا کہ اس نے کائنات کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کر دیا۔سات سات اقلیم ہراقلیم میں متعدد ملک،ہر ملک میں متعدد صوبے،ہر صوبے میں متعدد شہر، ہر شہر میں متعدد قصبے، ہر قصبے میں متعدد گاؤں اور ہر گاؤں میں الگ الگ نظام۔کوئی نہ اپنے یہاں کا مال منتقل کرنا چاہتاہے۔اور نہ آگے کچھ سوچنے کی ضرورت محسوس کرتاہے۔گھر گھر کے چھوٹے چھوٹے اقتدار نے اپنی گرفت کو مضبوط رکھنے کیلئے دوسروں سے اس کے رشتے کو جوڑنے کی بجائے توڑنے ہی پرزوردیا ہے۔
ایسے حالات میں اگر کائنات کی نعمتیں کسی ایک مرکز پر جمع ہوجائیں اور دوسرے افراد کو بھوکا اور ننگارہنا پڑے تو تعجب کیاہے؟یہ ضرور ہوگاکہ اپنے دامن کے دھبہ کو چھپانے کے لئے انسان کبھی فطرت کی دین پر اعتراض کرے گا اور کبھی دوسرے ملکوں کے مظالم پر۔وہ کسی وقت یہ نہیں سوچنا چاہتاکہ اگر ایک اعتبار سے دوسرے نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے
تو دوسرے اعتبار سے ہم نے بھی اس کے اوپر کچھ کم ظلم نہیں کیاہے۔
کہایہ جاتاہے کہ آج اور کل کے اقتصادی مسائل میں بڑافرق ہے۔کل زمین کا رقبہ اتنا ہی تھا لیکن آبادی کم تھی اور ضروریات زندگی محدود تھے۔اور آج آبادی ہزاروں گنازیادہ ہوچکی ہے۔اب اگراسی اعتبار سے زمین کا رقبہ اور اس کی قوت بھی بڑھ جاتی تو کوئی اقتصادی مسئلہ نہ پیداہوتا۔لیکن مشکل تویہ ہے کہ ہر شیء میں اضافہ ہوتارہااور اضافہ نہیں ہواتو صرف زمین کے رقبہ اور اس کی قوت میں۔اس لئے دور حاضر کی کشمکش کو انسانی ہویٰ وہوس کا نتیجہ نہیں قرار دیاجاسکتااس میں فطرت کی کوتاہی کا بھی بہت بڑادخل ہے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین کے رقبہ میں پیمائش کے اعتبار سے کوئی اضافہ نہ ہونے کے باوجود اس زمین نے ایسے جواہرات اور خزانے اگل دیئے ہیں جن کا اگلی قوموں کو کوئی تصور بھی نہ تھا۔پٹرول کی برآمد کا کام حال ہی میں شروع ہواہے اور اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک کا دارومدار اسی پٹرول پر ہے۔نئی نئی گیسیں حال ہی میں ایجاد ہوئی ہیں۔زمین میں چھپی ہوئی طاقتوں سے استفادہ کرنے کے نئے نئے وسائل کا انکشاف بھی کچھ زیادہ عرصہ قبل نہیں ہوا۔اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دولت کا خزانہ اور ثروت کا مرکز یعنی امریکہ جیسے عظیم ملک کا انکشاف بھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ظاہر ہے کہ امریکہ کے سینے میں جتنی دولت کے خزانے جمع ہیں وہاں کی آبادی کی ضروریات سے یقینا زیادہ اور بہت زیادہ ہیں۔تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے ہوس اقتدار نے ممالک کو تقسیم نہ کیاہوتااور ذرائع پیداوار سے ہرایک کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیاجاتاتو آج کسی بھی ملک یا قوم کی وہ حالت نہ ہوتی جس کی وجہ سے علماء اقتصادیات حیران وسرگردان نظر آرہے ہیں۔
اے روشنی طبع توبرمن بلاشدی
ہوس پرستی کے انہیں مفاسد کے پیش نظر اسلام نے انسان کو اقتدار اعلیٰ سے بالکل الگ کرکے کل کائنات کا حاکم ومالک صرف ذات احدیت کو تسلیم کیاہے اور اس کے بعد
حکومت کرنے کا حق صرف ان لوگوں کے لئے رکھاہے جو نفسانیت سے مافوق اور ہوس اقتدار سے بلند وبالا ہوں۔جن کا کام صحیح حکمرانی ہوا ور حکومت کے پردے میں خدمتکے نام پر ہوس رانی نہ ہو۔
دوسری طرف اس نے سیاسی تقسیم کو بھی کالعدم بنادیاہے اور اپنے کسی قانون میں بھی قوم عرب یاملک حجاز کے باشندوں کو خطاب نہیں کیابلکہ ہمیشہ قوانین کے اعلان میں''یَاَیُّ ه َا النَّاسُ'' اے گروہِ انسان کا لفظ استعمال کیاہے۔ہم نے اپنے اصولوں کو ان تمام لوگوں کے لئے وضع کیاہے جن پر یہ مقدس ومحترم لفظ صادق آتی ہو۔ہمارے معاشی نظام سے صحیح فائدہ اسی وقت اٹھایا جاسکتاہے جب اسے ملک وملت کے حدود سے بلند تر ہوکر دیکھاجائے اور اس کے دفعات کو تمام انسانوں پر منطبق کیاجائے۔عرب وعجم کے تصورات مہمل ہوں اور قوم وقبیلہ کے امتیازات لغو۔اسلام میں یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب عالم انسانیت کے وسیع تر تصور سے دنیا قطعاً ناآشنا تھی اور قبائل وبلاد سے بالاتر ہوکر سوچنے کی صلاحیت بھی پیدانہ ہوسکی تھی۔
سرمایہ داری اور اقتدار پرستی کے اسی ظلم کی طرف امیرالمومنین حضرت علی ـنے ان لفظوں میں اشارہ کیاتھا:
ماجاع فقیراه ما متع به غنی
مارایت نعمة موفورة الا والیٰ جانبهاحق مضیع
کوئی فقیر اس وقت تک بھوکا نہیں ہوتا جب تک کوئی غنی اس کے حصۂ دولت سے بہرہ ورنہ ہوجائے۔میں نے کہیں بھی نعمت کی فراوانی نہیں دیکھی مگر اس کے پہلو میں ایک حق کو برباد ہوتے بھی دیکھاہے۔
پہلافقرہ سرمایہ داری کے ظلم کا اعلان ہے اور دوسرا فقرہ ہوس اقتدار کی تعدی کا اظہار ۔برباد ہونے والے حق کی تعبیر بھی اپنی بلاغت میں بڑی وسعت رکھتی ہے۔اس میں
ثروت مندوں کے ظلم کے ساتھ اقتدار والوں کے واقعی احکام پر ظلم کے اشارے بھی پائے جاتے ہیں۔
انشورنس
سرمایہ میں اضافہ کی ایک نئی ترکیب انشورنس بھی ہے۔انشورنس کے مختلف طریقہ ہوتے ہیں۔بعض کی شرح منفعت کا حساب ہوتاہے اور بعض کا غیر معلوم ظاہر ہے کہ اس علم ولاعلمی کے اعتبار سے دونوں کی نوعیت بھی مختلف ہوگی۔جہاں شرح منفعت معلوم ہوگی وہاں جواز کی دلیل کچھ اور ہوگی اورجہاں شرح مجہول ہوگی وہاں بحث کا انداز کچھ اور ہوگا۔
انشورنس کی ایک صور ت یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ رقم کمپنی سے طے کر لیں اور کمپنی آپ سے اس رقم کو قسط وار وصول کرتی رہے۔اس کے بعد اگر آپ کی زندگی نے رقم پوری ہوجانے کے بعدبھی وفاکی تو آپ کو رقم مع سود کے دے دی جائے گی لیکن آپ کو آئندہ بھی قسط وار رقم دیتے رہنا پڑے گی۔جسے آج کی اصطلاح میں زندگی کا بیمہ کہتے ہیں۔اس کی خطرناک شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی نے طبیعی قانون یاکسی حادثہ کی بناپر آپ کاساتھ چھوڑبھی دیاتو آپ کے ورثہ کو یہ ساری رقم مع اضافہ کے دے دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ قانونی طور پر اس معاملہ کے صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔قانونی معاملہ وہی ہوتاہے جس میں معاملہ کے دونوں طرف معلوم ہوتے ہیں۔اور یہاں ایسا نہیں ہے۔آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں تو اس چیز کی مقدار بھی معلوم کرتے ہیں اور اس کے عوض میں دی جانے والی رقم کی مقدار بھی معلوم کرتے ہیں۔ایسا نہیں ہوتاکہ نہ اس چیز کی مقدار معلوم ہو
اورنہ اس کی قیمت کی مقدار معلوم ہواور معاملہ تمام ہوجائے۔یہی حال کرایہ کا بھی ہے کہ جب کسی چیز کو کرایہ پر دیتے ہیں یا کوئی رقم بطور قرض دیتے ہیں تومال وقیمت دونوں کو معلوم کرلیتے ہیں۔
بیمہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔یہاں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ملنے والے دس ہزار کے مقابلہ میں ہمیں ایک آنہ دینا پڑے گا یابیس ہزار،ممکن ہے زندگی باقی رہ جائے اور بیس ہزار دیناپڑ جائے۔اور ممکن ہے کل ہی ساتھ چھوڑ دے اور ایک دو قسط بھی نہ دینا پڑے۔ظاہر ہے کہ ایسے نامعلوم معاملہ کو کسی طرح جائز نہیں کہاجاسکتا۔یہ اور بات ہے کہ طرفین کے راضی ہو جانے کی بناپر مصالحت کی کوئی شکل نکال لی جائے یا بیمہ کمپنی زیادہ رقم کے مقابلہ میں اپنے کچھ مخصوص خدمات پیش کردے یااسے مال کی حفاظت کی اجرت قرار دے لیکن یہ قانون نہیںہے۔
بیمہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنی کسی ضرورت کی بناپر بیمہ کمپنی سے یہ معاہدہ کرے کہ ہمیں دس سال کے بعد کسی خاص ضرورت کے لئے پانچ ہزار روپیہ کی ضرورت ہے اور کمپنی اس سے یہ کہے کہ آپ دس سال میں قسط وار ساڑھے چار ہزار روپیہ دے دیجئے ہم آپ کو اس موقع پر پانچ ہزار روپیہ کامل دے دیں گے بلکہ اگر ممکن ہوگااور ہمارے تجارت ترقی کر جائے گی تو پانچ ہزار سے زیادہ بھی دے دیں گے۔یعنی پانچ ہزار تو بہر حال دیں گے۔زیادہ کا امکان حالات کے اوپر موقوف ہے۔زیر نظرمعاملہ میں قانونی طورپر خوددو خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ایک یہ کہ ہماری رقم کے مقابلہ میں ملنے والی رقم کی کوئی مقدار معین نہیں ہے اور بغیر تعین کے اسے دورقموںکا معاوضہ تو بہرحال نہیں قرار دیا جاسکتا۔
رہ گیا بینک والوں کی طرح ایجنٹ بن کر تجارت کرنا تو اس کے بارے میں پہلے ہی واضح کیاجاچکاہے کہ ایسا معاملہ صرف اس وقت صحیح ہوسکتاہے جب مال کے فائدہ یانقصان کی ذمہ داری مالک پر ہو،ایجنٹ پر نہ ہو اور یہاں پانچ ہزار کا قطعی ہونا
اس بات کا ثبوت ہے کہ تجارت کے نقصان سے بیمہ کرانے والے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔اس کا حساب صرف فائدہ کے اعتبار سے مختلف ہوسکتاہے۔ورنہ ایک معینہ رقم دے کر تو اسے بہرحال رخصت کر دیا جائے گا۔
اس مقام پر یہ بات نظرانداز نہ کرنا چاہئے کہ سودیا بیمہ کے معلق جو کچھ درج کیاجارہاہے وہ ایک قانونی بحث کے تحت ہے اور اس میں صرف یہ واضح کرنا ہے کہ اسلامی معاشیات میں سرمایہ داری کو توڑنے اور ثروت کو ایک مقام پر جامد نہ رکھنے کے لئے مذکورہ بالا وسائل اختیار کئے گئے ہیں اب اگر فقہی مسئلہ کے اعتبا رسے شرعی حیلوں کی بنا پر اس کی نوعیت بدل جائے تو اس کی ذمہ داری قانون پر نہ ہوگی۔اس لئے کہ شرعی حیلے یا قانون کی استثنائی صورتیں ضرورت کے مواقع کے لئے ہواکرتی ہیں ان سے اصل قانون کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
فیملی پلاننگ
اقتدار کی گرفت کو مضبوط کرنے والے اور سرمایہ کو بیش از بیش بڑھانے والے افراد نے حیات وکائنات کے رشتے کو توڑکر عوامی بدحالی کے لئے نئے نئے اسباب تلاش کئے ہیں۔انہوں نے سماج کو یہ سوچنے کا موقع نہیںدیاکہ اس معاشی بدحالی اور اقتصادی کشمکش میں ان کی جغرافیائی تقسیم یا ان کی سرمایہ داری کا بھی کوئی ہاتھ ہے بلکہ ہمیشہ یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زمین کی ناقابل اضافہ پیمائش آبادی کی بڑھتی ہوئی رفتار کو برداشت نہیں کرسکتی۔اس پر پابندی لگانے کی شدید ضرورت ہے اور حسن اتفاق سے ایسا بھی
ہواکہ حکومت کے پرستار،دولت کے ایجنٹ اہل فکر ونظر نے بھی اپنی قوت استنباط کو خیر باد کہہ کے نظام زر کی تائید کے لئے نت نئے افکار تراشنا شروع کر دیئے اور سب کا سارا زور اس بات پر صرف ہوگیا کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو روکاجائے۔اس سلسلہ میں بہت سے فلاسفہ بھی میدان میں آئے لیکن سب سے زیادہ نام مالتھسنے پیداکیا۔اس نے اس بگڑے ہوئے توازن کو سائنٹیفک انداز سے دیکھااور باقاعدہ ریاضی قواعد سے یہ ثابت کردیاکہ اگر بڑھتی ہوئی آبادی کی روک تھام نہ کی گئی تو آئندہ چند برس کے اندر دنیا کا نقشہ کچھ اور ہی ہوجائے گا۔
مالتھسکا کہنا ہے کہ زمین کی پیمائش میں اضافہ ناممکن ہے۔اس کی طاقت روز بروز کم ہوتی جارہی ہے۔غلہ کی پیداوار یازمین سے استفادہ صرف جدید ترین وسائل پیداوار کے ذریعہ ممکن ہے اور وسائل پیداوار اور پیداوار میں اضافہ کے تناسب کی کیفیت یہ ہے کہ پیداوار ہر پچیس سال کے اندر صرف اتنی ہی بڑھتی ہے جتنی پچیس سال پہلے تھی جب کہ آبادی کی مقدار ہر پچیس سال کے بعد دگنی چوگنی ہوجاتی ہے۔نتیجہ یہ ہوتاہے کہ پہلے پچیس سال تک تو دونوں کا توازن برقرار رہتاہے اور اقتصادیات میں کوئی کشمکش نہیں پیدا ہوتی۔لیکن دوسرے پچیس سال سے یہ کشمکش شروع ہوجاتی ہے۔غلہ صرف تگنا ہوتاہے اور آبادی چوگنی ہوجاتی ہے۔اور پھر یہ غیر متوازن سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتاچلاجاتاہے۔
دونوں کے توازن کو برقرار رکھنے کے لئے آبادی کو کم کرنے کی شدید ضرورت ہے اور اس کمی کے دوہی وسیلے ہوسکتے ہیں۔ایک قبل ازوقت اختیار کیاجائے گا اور دوسرا بعد ازوقت، قبل ازوقت اقدام یہ ہونا چاہئے کہ شادیاں کم ہوں،دیر سے ہوں،لوگ اپنے نفس پر کنٹرول کریں۔عورتوں سے جنسی ارتباط کم کیاجائے اور بچے اسی اعتبار سے پیداکئے جائیں جس اعتبار سے پیداوار کاتناسب بڑھ رہاہو۔مثال کے طور پر پچاس سال کے بعد جب غلہ تگنا اور آبادی چوگنی ہونے والی ہوتواس وقت کے لئے پچیس سال بعد ہی سے یہ انتظام
شروع کر دیاجائے کہ آئندہ پچیس سال میں جتنا غلہ پیداہونے والا ہو اسی اعتبار سے بچے بھی پیداکئے جائیں۔
اگرآج غلہ ایک من پیداہورہاہے اور انسانی آبادی دس افراد پر مشتمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ پچیس سال کے بعد غلہ دومن ہوجائے گا۔اور آدمی بیس افراداور توازن برقرار رہے گا لیکن اس کے بعد پچیس سال میں غلہ تین ہی من رہے گا اورآدمی چالیس ہوجائیں گے۔ظاہر ہے کہ اگر یہ تعداد تیس ہی رہتی توکوئی اقتصادی مسئلہ نہ پیداہوتا اور سب اسی طرح مطمئن رہتے جیسے پہلے پچیس برس میں رہ چکے تھے۔لیکن ایسا نہ ہو سکا اس لئے اب صحیح علاج یہی ہے کہ پچیس سال سے پچاس سال کے درمیان بیس کے بجائے دس ہی بچے پیداکئے جائیں۔
طریقۂ کاریہ ہوکہ جن کے یہاں آبادی بڑھ چکی ہے وہ آئندہ پچیس سال کے لئے دوسروں کو موقع دیں اور اپنے نفس پر کنٹرول کریںپھر آئندہ وقفہ میں اگر کوئی آسمانی آفت نازل نہ ہوئی توانہیںبھی کوئی موقع دیاجائے گا ورنہ نہیں۔
بعد از وقت اقدام کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ پہلی تدبیر کے بعدبھی کسی آسمانی آفت کی بناپر آبادی اور پیداوار کاتناسب بگڑجائے گا تو اسے پھر اپنی منزل پر لانے کے لئے ملک میں جنگ وغیرہ چھڑجائے،یا فطرت سے مددمانگی جائے اور کوئی سیلاب، زلزلہ وغیرہ آجائے تاکہ دونوں کاتناسب اپنی اصلی شکل پر پلٹ آئے۔
مالتھسکے اس نظریہ پر علمائے اقتصادیات نے سخت تنقید کی ہے اور اس کے تاروپودبکھیرکر رکھ دیئے ہیں لیکن ہماری تنقید صرف یہ ہے کہ مالتھس کا یہ پورا بیان صرف تخمینی ہے اس کی کوئی علمی یا قانونی بنیاد نہیں ہے اور ایسے بیان پر بھروسہ کرکے آئندہ نسلوں کے لئے راستہ نہیں روکا جاسکتا۔ممکن ہے کہ مالتھس نے اپنے دور میں اپنے ملک کی یہی کیفیت دیکھی ہو اور اس سے متاثر ہوکر یہ فلسفہ تیار کر دیا ہولیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے ناقص
تجربات کو ایسے عظیم مسائل کی بنیاد نہیں قرار دیاجاسکتا۔
مالتھس کا کہناہے کہ انسانوں کی پیداوار پچیس سال کے اندر دوگنی اور چونگی ہوجاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تخمینہ صرف اپنے ملک کیلئے ہے یا تمام دنیا کے لئے۔ اگر اپنے ملک کے لئے ہے تو کسی ملک کے حالات کو اقتصادیات کا قانون نہیں بنایا جاسکتا۔ بلکہ یہ خود ہی میرے دعویٰ کا ایک ثبوت ہوگاکہ انسان نے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لئے دنیا کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیاہے اور اس طرح اکثر ممالک فقر وفاقہ کا شکار ہوگئے ہیں۔
اور اگر یہ مشاہدہ تمام دنیا کے لئے ہے تو اسے تمام دنیا کی پیداوار پر بھی غور کرنا ہوگا جو ایک انسان کیا ایک دنیا کے لئے بھی ممکن نہیں ہے آج کی حکومت کسی ایک چھوٹے سے دیہات کی پیداوار کا بھی صحیح اندازہ نہیں کرسکتی اور قانون پیداوار سے پہلے ہی زمین کے رقبے کے حساب سے وضع کردئے جاتے ہیں۔
قانون بنانے والے یہ نہیں سوچتے کہ یہ قانون کس پر نافذ کیاجارہاہے۔اس کے یہاں اتنا غلہ پیدا بھی ہواہے یا نہیں۔سرکاری انسپکٹر کا بیان صحیح بھی ہے یا نہیں۔زمین پر کوئی داخلی آفت تونازل نہیں ہوئی ہے۔
ظاہر ہے کہ جب ایک دیہات کی پیداوا ر کا صحیح اندازہ نہیں لگایاجاسکتاتوساری دنیا کا اندازہ کیالگایاجاسکتاہے۔پھر زمین کی پیداوار سے مراد فقط غلہ کی پیداوار ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ترکاریاں،فروٹ،پھل،گھاس،درختوں کے پتے وغیرہ بھی شامل ہیں جن کی صحیح مقدار کا اندازہ لگاناناممکن ہے۔ان چیزوں کے علاوہ حیوانات کی تعداد کا شمار کرنا بھی ضروری ہے۔اس لئے کہ ملک کے بہت سے باشندوں کی گذراوقات صرف گوشت پرہوتی ہے۔اس کے بعددریائی پیداوار کا بھی حساب کیاجائے گا۔اس لئے کہ مچھلی کے علاوہ بھی دریاؤں میں اکثر ایسے حیوانات پائے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی ملک کے باشندوں کی غذابنا کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ دنیاکی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوجو کسی نہ کسی ملک کی غذانہ بنتی ہو۔ ایسے حیوانات جن کا آپ تصور بھی نہیں کرسکتے بعض ممالک میں بڑے شوق سے استعمال کئے جاتے ہیں۔دنیا کی غذائی صورتِ حال کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے سوراخوں میں چھپے ہوئے ان جانوروں کا بھی حساب کرنا پڑے گا جو اکثر اوقات بعض پست اقوام کی غذا بن جایا کرتے ہیں۔اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اتنا طویل وعریض حساب سوائے کسی غیب داں ہستی سے کوئی دوسرا نہیں کرسکتا۔
مالتھسکے سلسلہ میں ایک انتہائی تعجب خیزبات یہ بھی ہے کہ اس نے نسل بندی کے قانون کی بنیادیں طے کرتے ہوئے زمین کی طاقت اور اس کی پیمائش کے علاوہ دنیاکی ہرغذا کو نظرانداز کردیاہے اور اپنے قانون کو ایک بازیچۂ اطفال سے زیادہ کوئی مرتبہ نہیں دیا۔
زیر نظر بحث کا تمام تر تعلق اقتصادیات سے ہے اس لئے فیملی پلاننگ کے دیگر سماجی اخلاقی اور نفسیاتی عیوب کی طرف اشارہ نہیں کیاجاسکتاورنہ پوری تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیاجاسکتاتھاکہ فیملی پلاننگ عیاشتی کی ترویج، نفسیات کی موت اور اخلاق کی تباہی کے سواکچھ نہیں ہے۔تاہم بحث کو خاتمہ دیتے ہوئے تین اہم نکات کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے:
(1) غذائی صورت حال کو درست کرنے کے لئے نسل بندی کا جو ذریعہ اختیار کیاگیاہے۔ اس سے کسی بھی ملک کی معاشی حالت نہیں درست ہوسکتی۔اس لئے کہ پیدا ہونے والا بچہ ابتدائی ایک دوسال تک ملک سے کسی قسم کی غذاکا مطالبہ نہیں کرتا۔اس کے بعد تھوڑی تھوڑی غذاکاتقاضہ شروع کرتاہے اور عمر کی ایک منزل پر پہنچ کر سماج سے پوری غذا کا مطالبہ کرتاہے۔جب کہ اس کی پیدائش کو روکنے کے لئے روز اول ہی سے اتنا سرمایہ صرف کر دیاجاتاہے جو اگر ملک کی پیداوار یاتجارت کو فروغ دینے پر
صرف کردیاجاتاتو شاید صورتِ حال پیدانہ ہوتی اور وہ وہمی خطرہ سامنے نہ آسکتا۔
خالص اقتصادی نقطۂ نظر سے تویہ بھی کہاجاسکتاہے کہ ملک کا جتنا سرمایہ آئندہ نسلوں کی روک تھام پر صر ف کیاجارہاہے یہی سرمایہ اگر قدیم نسل کے بچے ہوئے بیکار، ضعیف وناتواں افراد کے خاتمہ پر صرف کردیاجاتاتو شاید مسئلہ جلدی آسان ہوجاتا۔ اس لئے کہ یہ طبقہ موجودہ صورتِ حال میں بھی پورا غذاکا مطالبہ کرتاہے۔ اور سماج کو کچھ دینے سے بالکل قاصر ومجبور ہے لیکن افسوس کہ آج کی حکومتیں ذہنی اعتبار سے اتنی پست ہوگئی ہیں کہ جو سامنے آجاتاہے اس سے خوفزدہ ہوجاتی ہیں اور جو عدم کے اندھیرے میں خاموش بیٹھا رہتاہے اسے اس دنیا میں قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں دیتیں۔
(2) مالتھسنے اپنے بیان میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیاہے کہ اگر ملک میں وقتاً فوقتاً جنگ چھڑجایاکرے یا کوئی زلزلہ آجایاکرے یاکچھ سیلاب وغیرہ کا شکار ہوجایاکریں تو پیداوار آبادی کاتناسب برقراررہ سکتاہے لیکن میرے خیال میں یہ بات بھی انتہائی عجیب اور مضحکہ خیز ہے۔اس کے حادثات کے آئینہ میں آدمیوں کی تباہی پرتو نظرکی لیکن یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی آج کی جنگ میں آدمی سے کہیں زیادہ سامان ضائع ہوجاتاہے۔زمین دار برباد ہوجاتے ہیں،حیوانات مرجاتے ہیں،پیداوارتباہ ہوجاتی ہے،فصلیں برباد ہوجاتی ہیں اور توازن راہِ راست پر آنے کے بجائے مزید خراب ہوجاتاہے۔یہی حال زلزلہ اور سیلاب وغیرہ کاہوتاہے۔ ایسی چیزوں کو توپیداوار کی قلت کے اسباب میں شمار کرنا زیادہ بہتر تھا۔آبادی کی کمی میں ان کا حساب کرنا ان کی واقعی کیفیت سے چشم پوشی کے سوااور کچھ نہیں ہے۔
(3) کسی بھی ملک کی غذائی صورت حال کے بگڑجانے کی بہت بڑی ذمہ داری وہاں کے باشندوں کی عشرت پرستی اور عیش پرستی پر بھی ہوتی ہے۔دور حاضر کے انسان
نے اپنے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے لوازم اتنے زیادہ بڑھالئے ہیں کہ کسی بھی آدمی کی آمدنی اس کے خرچ کے لئے کافی ہوتی نظرنہیں آتی۔بہتر سے بہتر غذ ااور عمدہ سے عمدہ لباس کے پاک صاف، بلند بالااسبابِ راحت سے معمور مکانات بھی ضروری ہیں۔پھر سنیما، عیاشی،فنونِ لطیفہ کے ذوق کی تسکین، تفریح گاہوں کی سیر اور اس قسم کے دیگر غیر ضروری یا غیر جائز کام بھی ابتدائی ضروریات میں شامل ہوگئے ہیں۔
نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی آمدنی سے نالاں اور اپنے خرچ سے پریشان ہے کوئی شخص بھی اپنے طبقہ کی سطحِ زندگی پر آنے کے لائق نہیں رہ گیاہے اور یہ انسان کی خودغرضی کی آخری منزل ہے کہ وہ اپنے موجودہ حالات کو دیکھ کر آئندہ آنے والی نسلوں پر پابندی لگانا چاہتاہے۔اسے خطرہ یہ ہے کہ اگر انسانوں کا اضافہ ہوگیاتو ان کے خرچ کے لئے سامان کہاں سے مہیاکیاجائے گا۔یعنی اپنے عیش وطرب اور اپنی سطحِ زندگی کو محفوظ رکھنے کے لئے دوسروں کو اس زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں دی جاسکتی۔ اس کے آنے کے بعد اپنے وسائل راحت باقی نہ رہ سکیں گے۔اور گوناگوں مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا،زیادہ محنت کرنی پڑے گی،زیادہ غلہ پیداکرنا پڑے گا،زیادہ سامان مہیا کرنا پڑے گا،وسائل راحت میں کمی ہوجائے گی اور مزید بے حساب پریشانیاں لاحق ہوجائیں گی۔اس منزل پرآنے کے بعد ہر انسان ایک دوراہے پر کھڑاہوجاتاہے ۔ایک طرف اپنا سکون واطمینان،اپنی سطحِ زندگی،اپنی معاشرت کے اصول اور اپنی موجودہ صورتِ حال ہوتی ہے اور دوسری طرف آنے والی نسل کے وجود کا سوال؟
کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ انسان دوسروں کے وجود کو مٹادیتاہے لیکن اپنی راحت کو قربان نہیں کرسکتا۔ اپنے ہاتھوں اپنی نسل کا خون بہادیتاہے لیکن اپنی سطحِ زندگی کو نہیں
گراسکتا۔کیا ایسے انسان سے یہ توقع نہیں ہے کہ یہ آگے چل کر ایک پورے سماج کا قاتل بن جائے گا اس لئے جس نے آج اپنی نسل کے تباہ کرنے میں کوئی درد محسوس نہیں کیاوہ کل دوسروں کی گود کے پالے ہوئے بچوں کو تہ تیغ کرنے میں کیا تکلیف محسوس کرسکتاہے؟انسان کی ایک نفسیاتی کمزوری یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے عیوب سے چشم پوشی کرکے دوسروں کے اندر عیب تلاش کرتاہے اور حتیٰ الامکان اس بات کی کوشش کرتاہے کہ دوسروں کے عیب کو جلد ہی عالم آشکار کردے تاکہ لوگ میرے عیوب کی طرف متوجہ نہ ہوسکیں۔
فیملی پلاننگ پر زوردینے والے افراد کا طرز عمل یہی ہے کہ وہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ملک کی غذائی صورت حال کو بگاڑدیں گی اور ان کے ہوتے ہوئے آبادی اور پیداوار کاتناسب برقرار نہ رہ سکے گا۔لیکن اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اس عدم توازن میں اپنا بھی''بقدر حصۂ رسدی''ہاتھ ہے۔اور مالتھس کے فلسفہ کی روشنی میں یوں کہاجائے کہ بالفرض آج کی آبادی دس سے بیس ہوچکی ہے۔پیداوار ایک من سے دومن ہوگئی ہے اور حساب برابر چل رہاہے۔لیکن اب آئندہ خطرہ یہ ہے کہ غلہ ایک ہی من بڑھے گا اور آبادی 20 آدمیوں کی بڑھے گی۔ اوراس طرح دس آدمیوں کی خوراک کا مسئلہ ایک مصیبت بن جائے گا۔اس لئے دس آدمیوں کوآنے سے روک دیاجائے۔لیکن سوال یہ ہے کہ آئندہ کی آبادی کے بڑھنے میں صرف آئندہ آنے والی نسل ہی کاہاتھ تو نہیں ہے۔اس میں موجودہ نسل کا بھی حصہ ہے۔
اگر یہ لوگ دس سے بیس نہ ہوئے ہوتے اور پندرہ ہی رہ جاتے تو آئندہ کے لوگ بھی چالیس نہ ہوتے اور مصیبت پیدانہ ہوتی۔اس لئے مسئلہ کو حل کرنے کی دو صورتیںہیں۔آنے والی نسل کو چالیس کے بجائے تیس بنادیاجائے یاموجودہ نسل کو
بیس سے کم کر دیاجائے۔یہ انسان کی خودغرضی ہے کہ وہ خود دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتااور دوسروں کو آنے سے روک دیتاہے اور وہ بھی صرف اس لئے کہ قدرت نے آنے والی نسل کا سلسلہ وجود اسی کے حوالے کر دیاہے۔اس اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتاہے۔کاش ان فیملی پلاننگ پر زوردینے والے افراد نے یہ بھی سوچاہوتا کہ اگر یہی ترقی پسندی اور عیش پرستی ایک پشت پہلے پیداہوگئی ہوتی تو آج ان کا وجود کتمِ عدم کے گوشے میں ہوتااور ان کی پلاننگ کا پرچم کس دنیا میں لہراتا؟
خود غرض دنیا اپنے وجود کی یہ تاویل کرسکتی ہے کہ ہم موجودہ صورتِ حال کو سدھارنے کے لئے ایک سماجی ضرورت بن چکے ہیں اس لئے ہمیں دنیا سے نہیں ہٹایاجا سکتا۔آئندہ آنے والے تو ااج کی نسل کی گردن پر ایک زبردستی کو بوجھ بن کر آرہے ہیں۔ان سے ایک مدت تک کوئی کام نہیں لیاجاسکتا۔اس لئے ان کا روکنا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نسل نے بھی دنیا میں قدم رکھتے ہی سماج کے مشکلات کو حل کرنے میں حصہ نہیں لیا۔بلکہ اپنے پہلے کی نسل کی گردن پر بوجھ ہی بنی رہی۔وہ تو اس نسل کا رحم وکرم تھاکہ اسے اتنے دنوں تک رہنانصیب ہوااور اس نے آنے والی نسل کے بارے میں یہ ناروافیصلے کرنا شروع کردیئے۔
اس موجودہ نسل کو تو اپنی کیفیت پر بھی توجہ دینا چاہئے تھا۔وہی نسل ہے جس نے برسہابرس دنیا کا سرمایہ صرف کرنے کے بعد بھی صرف ایک مشکل کا اندازہ کیاہے اور اس کا کوئی حل نہیں تلاش کیا۔ایسی نسل کو تو آنے والی نسل کے نام پرقربان ہوجانا چاہئے تھاکہ اس میں مسئلہ کے ادراک کے ساتھ مسئلہ کے حل کے بھی امکانات پائے جاتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کی ایجاد کسی اقتصادی بنیاد پر نہیں کی گئی اس کی پشت پر صرف چند سرمایہ داروں کا مفاد،چند اقتدار کے بھوکوں کی ہوس کارفرماہے۔ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے بڑھتے ہوئے سرمایہ اور ہماری ملکی تقسیم کی طرف متوجہ نہ ہوسکیں اور انہیں
یہ باورکرادیاجائے کہ ملک کی بگڑتی ہوئی غذائی صورتِ حال کی ذمہ داری ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی پر ہے۔اس میں نہ بنیوں کے گودام کا کوئی ہاتھ ہے نہ بینکوں کے لاکرزکا، اس کا حل نہ اقتدار کی گرفت کو ڈھیلا کردینے سے نکل سکتاہے اور نہ ایک ملک کا سرمایہ دوسرے ملک کو مفت سپلائی کرنے سے۔
آپ یہ نہ پوچھیں کہ اگر فیملی پلاننگ کی بنیاد سرمایہ کے تحفظ پر ہے تو امریکہ جیسے سرمایہ دار ملک میں ایسا قانون کیوں نہیں ہے اور وہاں جبری طور پر بچوں کی پیدائش کو کیوں نہیں روکا جاتا۔
امریکہ والے جن حالات سے دوچارہیں اور جن نعمتوں میں زندگی بسرکرہے ہیں ان میں فی الحال کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن پھر بھی وہ مستقبل سے غافل نہیں ہیں۔انہوں نے مستقبل کے لئے دواہم تدبیریں سوچ لی ہیں۔ایک طرف دوسرے ممالک کی توجہ اپنے سرمایہ کی طرف سے ہٹانے کے لئے انہیں ملک کے حالات میں مبتلا کردیاہے۔اور فیملی پلاننگ جیسے قوانین رائج کردیئے ہیں۔اور دوسری طرف اپنے ملک کے قانون میں عیاشی اور بدکاری کو اتنا عام کر دیاہے کہ ہر شخص اپنی جنسی پیاس بجھانے کو زیادہ اہم سمجھتاہے۔بچہ پیداکرنے کو غیراہم چونکہ بچہ ماں باپ کی جنسی آزادی میں بہرحال کسی حدتک مخل ہوتاہے اس لئے وہ اپنے راستے سے کانٹے کوہٹانے کے لئے خودہی تیار ہوجاتے ہیں۔کسی قانون اور قاعدہ کے وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
مختصر یہ ہے کہ سرمایہ دار ممالک نے اپنے سرمایہ کے تحفظ اور اپنے اقتدار کی گرفت کو مضبوط رکھنے کے لئے دوسرے کمزورو ناتوان ممالک میں نسل بندی کے قوانین رائج کردیئے ہیں تاکہ ان ممالک کے آدمی اپنی پریشانیوں اور الجھنوں کا سبب ملک کے اندر اور آنے والی نسل میں تلاش کریں۔ ملک کے باہر کائنات کے بیشتر سرمایہ پر قابض صاحبانِ
اقتدارکی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں۔
اسلام نے ایسے ہی سینکڑوں نکات کو پیش نظررکھ کر یہ اعلان کیاتھا:
(إنْ مِنْ شَیْئٍ ِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ ِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ)
ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں اور ہم صرف بقدر معلوم نازل کیا کرتے ہیں۔ (حجر/21)
یعنی اس کائنات کے واقعی ذخیرے تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں ہم ان سب سے آگاہ اور باخبر ہیں۔جب جس قدر ضرورت محسوس کرتے ہیں نازل فرماتے ہیں۔دنیا اس اعلان پر اعتماد کرتی اور مالتھس جیسے دوسرے علماء اقتصادیات کے مجہول افکار نے اسے گمراہ نہ کردیاہوتاتو اس کے سامنے اقتصادی مسئلہ نہ ہوتااور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کائنات میں بقدر ضرورت سامان آج بھی موجود ہے اور قرآنی وعدے کے مطابق کل جب نسل بڑھے گی تو اس کی ضروریات کے مطابق مزید نعمتیں نازل ہوں گی۔
دوسری طر ف اس نے یہ بھی سمجھادیاتھاکہ:
اپنی اولاد کو فقر وفاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو۔ہم تمہیںبھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔
یعنی اگر تخلیق کا کام تم نے انجام دیاہوتااور رزق پہنچانا تمہارا کام ہوتاتو تمہیں یہ اختیار ہوتاکہ جسے اپنے عیش وعشرت کی راہ میں رکاوٹ پیداکرتے دیکھو اسے تباہ وبرباد کر دو لیکن جب ہم نے رزق کی ذمہ داری تمہارے سر نہیں ڈالی ہے اور خلقت کاکام تمہارے حوالے نہیں کیاہے تو تمہیں کیاحق پہنچاہے کہ ہماری مخلوق کو ہمارے اوپر اعتماد نہ کرتے ہوئے تباہ برباد کردو۔یادکھو یہ فیملی پلاننگ اپنے نفس پر تصرف کا نام نہیں ہے بلکہ آنے والی نسل کا راستہ روکنے کی دوسری تعبیر ہے۔اپنے نفس پر تصرف کا مطلب تویہ ہے کہ عیاشی کے راستے رک جائیں،ناجائز تعلقات بند ہوجائیں،شادی کے بعدعورتوں سے انسانوں جیسے
تعلقات ہی رہیں۔بہیمیت غالب نہ آنے پائے نہ کہ اس میں نسل کشی جیسے وسیع اختیارات بھی شامل ہوجائیں۔
زیر نظرکتاب
زیر نظرکتاب کیاہے؟اس کا اندازہ توآپ کو کتاب کے پڑھنے کے بعدہی ہوسکے گا۔لیکن عراق وحجاز اور مصر وشام کے ارباب جرائد ورسائل کے تبصروں کی روشنی میں کہا جاسکتاہے کہ معاشیات کے ایسے اہم موضوع پر عالم اسلام میں اب تک کوئی ایسی جامع کتاب نہیں پیش کی گئی ہے جس میں اسلام کے علاوہ دیگر نظامہائے معاشیات پر مکمل علمی تبصرہ بھی ہواور اسلامی معاشیات کو وسیع اور ہمہ گیر خاکہ بھی۔
زیر نظرکتاب پہلی کتاب ہے جو اس جامعیت اور ہمہ گیری کے ساتھ تصنیف کی گئی ہے اس کتاب کو بیسویں صدی کے معجزۂ فکروفن سے تعبیر کیاجائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس کی تصنیف کا کام ایک ایسے دماغ نے انجام دیاہے جو نجف اشرف کے فقہی ماحول کا پرورش یافتہ ہے۔
اس کی تحریر وتمحیص کا فریضہ ایک ایسے ذہن نے اداکیاہے جو تمام ترفقہ واصول کے سانچہ میں ڈھلاہواہے۔جہاں ایک مخصوص زاویۂ فکر سے بحث کی جاتی ہے اور ایک
مخصوص میدان کو فکر کی جولانگاہ بنایاجاتاہے،لیکن استاد محترم دام ظلہ نے ماحول کے شکنجوں کو توڑکر ایک طویل وعریض دنیا میں قدم رکھاہے۔دنیا کے قدیم وجدید معاشی نظریات کا مطالعہ کیاہے۔ان کے افکار واصول کوعقل ومنطق کی میزان پہ تولااور پرکھاہے اور آخر میں اس پوری جدوجہد کو کتابی شکل میں پیش کردیاہے جو دور حاضر کا شاہکار بھی ہے اور مصنف کی وسعت نظرکا برہان قاطع بھی۔
کتاب کے مطالعہ کے وقت اس بات کا پیش نظررکھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی افسانوی کتاب یارومانی ناول نہیں ہے۔جس میں ادب کی چاشنی یازبان وبیان کا لطف تلاش کیاجائے۔یہ دور حاضر کے سب سے اہم مسئلہ کا علمی حل اور کائنات کے سب سے زیادہ بنیادی مرض کا سمجھابوجھاعلاج ہے۔اس کا مطالعہ ایک ذی شعور دماغ اور صاحب فکر ذہن کے ساتھ کرنا چاہئے۔
اس کے آئینہ میں سماج کی خرابیاں اور دنیا کے نظاموں کے نقائص کا مشاہدہ کرنا چاہئے۔اور اسلام کے اس آئین کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہئے جسے چودہ صدیوں کا فرسودہ نظام کہاجاتاہے۔
کتاب کے پہلے حصہ میں معاشیات کے علمی پہلو کو محور بحث بنایاگیاہے جہاں آدم اسمتھ،ریکارڈو، کارل مارکس سے لے کرلنین اور اسٹالین تک کے اشتراکی نظریات اور جدید ترین امریکہ کے راسمالی تصورات کا تجزیہ کیاگیاہے۔قیمت کی بنیاد،قیمت کے اقسام ذاتی ملکیت کے فوائد ونقائص،سرمایہ داری کی بنیادیں، اشتراکیت کے اصول،اسلام کے امتیازی نشانات وغیرہ سے بحث کرکے یہ واضح کیاگیاہے کہ علمی اصول وقوانین کی روشنی میں اشتراکیت وراسمالیت کے اصول وتعلیمات نامکمل ہیںاور اسلام دنیا کا وہ واحد نظام ہے جس کے اصول وآئین کسی دور معاشیات میں ناکام نہیں ہوسکتے ہیں۔
دوسری جلد میں اسلام کے احکام کی تفصیلات سے بحث کی گئی ہے اور یہ واضح
کیاگیاہے کہ اگر دنیا میں اسلامی نظام قائم ہوجائے تو اسلام کے اصول وآئین کیاہوں گے۔وہ اس میدان کو کیونکر سرکرے گا اور اپنی تنظیم کسی طرح قائم کرے گا۔
اس جلد میں ماقبل پیداوار کے ان خام مواد کو بھی مرکزیت دی گئی ہے۔جنہیں اشتراکیت وراسمالیت نے بالکل نظرانداز کر دیاہے۔اور ان سے بحث کرنے کو معاشیات کے مسائل سے الگ کوئی مسئلہ سمجھ لیاہے۔
زمینوں کی تقسیم اور ان کی نوعیتوں کو واضح کرکے یہ بتایاگیاہے کہ محنت کی بنیاد پر تقسیم کا نظریہ اپنانے کے بعد بھی اسلام میں اسٹیٹ کے پاس ایسی ملکیتیں رہ جاتی ہیں جو غریب وناتوان،عاجزوبیکس افراد کی کفالت کرسکیں اور اجتماعی توازن کے قیام میں مدد پہنچاسکیں۔
پیداوار کے بعد کے مسائل کو بھی نہایت ہی شرح وبسط کے ساتھ بیان کیاگیاہے اور یہ واضح کردیاگیاہے کہ بساطِ ارض کے بسنے والے انسانوں کے لئے اسلام سے بہتر کوئی نظام معاش نہیں ہے جو انسان کی انسانیت،حریت اور شرافت اخلاق کا بھی احترام کرے اور اس کے معاشی مشکلات کو بھی حل کردے۔مشین کے کل پرزوں کی طرح آدمی سے کام لینا آسان ہے اور اس کی حریت وکرامت کا اعتراف کرکے اسے خدمت کی راہوں پر لگادینا بہت مشکل ہے۔یہ کام اسلام ہی نے انجام دیاہے اور یہ شرف اسی کو حاصل ہے۔
کتاب ایک سمندر ہے جسے کوزہ کے بجائے قطرہ میں سمویاگیاہے اور ایک گلستان ہے جسے پھول کے بجائے کلی میں بندکیاگیاہے۔خدا وندعالم سے دعاہے کہ وہ استاد محترم کے سایہ کو قائم ودائم رکھے۔ان کے قلم کی جولانیاں برقراررہیں۔کتاب مرکز توجہ واستفادہ بنے اور حیران وسرگردان انسانیت اسے اپنے مستقبل کے لئے مشعل راہ بنا سکے۔ وہی ہمارامالک ہے اور اسی سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں۔
والسلام
سید ذیشان حیدرجوادی
26نومبر1970ئ
افسوس صدافسوس کہ آج جب کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا جارہاہے تو استاد علام کی چوتھی برسی منائی جارہی ہے اور ان کی شمع حیات عراق کے ظالم حکمراں بے دین صدام کے ہاتھوں خاموش ہو چکی۔رب کریم اس قبراطہر پر بیشمار رحمتیں نازل کرے جس کا نشان بھی معلوم نہیں ہے اور کتاب کی افادیت کے ساتھ عراق میں وہ اسلامی نظام نافذ کردے جو استاد شہید کی پہلی اور آخری آرزو تھی۔
جوادی
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
کلمۂ مؤلف(برائے طبع دوم)
''اقتصادنا''کے دوسرے ایڈیشن پر مقدمہ لکھتے ہوئے مجھے اس بات کی مسرت ہورہی ہے کہ امت اسلامیہ حقیقی پیغام کی طرف متوجہ ہوگئی ہے جو اسلام کی شکل میں مجسم ہوکر آیاتھا اور استعمار کے گوناگوں ضلالت آمیز پروپیگنڈوں کے باوجود اس بات کا احساس کر رہی ہے کہ اسلام ہی وہ واحد وسیلہ ہے جس سے امت مصائب وآلام سے چھٹکاراپاسکتی ہے اور یہی وہ منفرد نظام ہے جس کے زیر سایہ زندگی کی طاقتوں کو ابھرنا چاہئے اور اسی کی بنیاد پر اس کی عمارت تعمیر ہونی چاہئے۔
دل چاہتاتھاکہ اس مرتبہ کتاب کے بعض موضوعات پر اور بھی تفصیلی بحث کرتااور مخصوص نکات پر اور بھی روشنی ڈالتالیکن حالات کی ناسازگاری نے موقع نہ دیا۔اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کارنہیں ہے کہ چند کلمۂ اصل کتاب کے موضوع کے بارے میں تحریر کردئے جائیں تاکہ موضوع کی اہمیت اور مشاکل حیات سے اس کے رابطے کی کچھ وضاحت ہوجائے اور عام انسانی سطح کے ساتھ ساتھ اسلامی سطح پر بھی معاشیات کی قدروقیمت کا اندازہ کیاجاسکے۔
اس سطح پرامت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی پسماندگی اور ذلت کے خلاف مسلسل جہاد میں مشغول ہے۔ اس کے سامنے وہ سیاسی اور اجتماعی حرکت ہے جس سے بہتر حالات پیداہوسکیںاور بارسوخ وجود حاصل ہوسکے وہ بارفاہیت زندگی اور بے نیاز اقتصادکی طالب ہے۔اسے یہ معلوم ہے کہ ان اچھے برے مسلسل تجربات کے بعد حرکت کا ایک ہی راستہ رہ جائے گا۔جس کے زیر اثرمشاکل ذلت ورسوائی کا علاج کیاجائے گا اور انسانیت کو اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچایاجائے گا اور اسی کانام اسلام ہے۔
بشری میدان میں انسانیت دو عالمی نظاموں کے درمیان پس رہی ہے۔ اسے انتہائی قلق واضطراب اور انتشار وتذبذب کا سامنا کرنا پڑرہاہے وہ ایٹم وہائیڈروجن کے مسلح نظاموں کے باوجود یہ محسوس کر رہی ہے کہ مستقبل میں ان مصائب وآلام سے چھٹکارے کا ذریعہ صرف اسلام ہوگاجو آسمانی برکتوںکا کھلاہوادروازہ ہے۔
اسلامی سطح
جب سے عالم اسلام نے یورپ کی زندگی کا جائزہ لینا شروع کیاہے اور تہذیب وتمدن کے قافلہ میں اسے میرکارواں کی حیثیت دے کر اپنے حقیقی پیغام اور آسمانی نظام کو نظرانداز کردیاہے اسے بھی یورپ جیسی تقلیدی تقسیم کا احساس ہونے لگاہے اور وہ بھی یہ سوچتاہے کہ اقتصادی سطح پرممالک دنیا دوحصوں پربٹے ہوئے ہیں۔ترقی یافتہ اور پسماندہ اور چونکہ اسلامی ممالک کا شمار پسماندہ ممالک میں ہوتاہے۔اس لئے یورپ کی منطق کے اعتبار سے اس کا فرض ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی رہنمائی پر ایمان لاکر اس کے لئے راستے
کھول دے اور وہ اپنی روح پھونک کر سطحی ارتقاء کے راستے ہموار کرے۔
یہی وہ طرزفکر تھاجس نے عالم اسلامی کو مغربی تہذیب وتمدن کی گود میں ڈال دیا ہے اور اسے یہ باورکرادیاہے کہ توترقی کے راستوں میں پسماندہ ہے اور تجھے اس یورپ کے افکار کو اپنانا چاہئے جس نے اقتصادی میدان میں اپنے کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑاکر دیاہے۔وہ ممالک اسلامیہ کو ارتقاء کی راہوں پر لگاکرایک حاوی اور ہمہ گیر اقتصادی نظام دے سکتاہے۔اس نے قیادت کے تجربے کئے ہیں اور اس کے پاس ان تجربات کے خطوط اور نشانات محفوظ ہیں۔
یورپ کی قیادت اور اس کے تجربات کی رہنمائی کا تصور عالم اسلام میں ایک مدت سے چلا آرہاہے اور اس سلسلے میں ممالک اسلامیہ مختلف ادوار میں یورپ کے مختلف تجربات زندگی کو اپنا چکے ہیں اور آج بلاداسلامیہ کے مختلف گوشوں میں یہ تینوں تجربات پھیلے ہوئے ہیں۔کل یہ تجربات تدریجی اور زمانی تھے اور آج سب بیک وقت مکانی ہوگئے ہیں۔
یورپ کے اتباع کی سب سے پہلی شکل سیاسی تھی۔یورپ ممالک اسلامیہ کے مختلف گوشوں پر حکومت کررہاتھا اور مسلمان اس کی قیادت میں رفاہیت وارتقاء کے خواب دیکھ رہے تھے۔
دوسری شکل یہ ہوئی کہ سیاسی اعتبار سے مستقل حکومتیں قائم ہوجائیں لیکن اقتصادی اعتبار سے یورپ کو عمل دخل کا موقع دیاجائے تاکہ وہ ان ممالک میں مختلف کارگزاریاں کرکے ان کے خام مواد سے استفادہ کرے اور اس کی جگہ پر خارج سے مواد درآمد کرے۔اقتصادی زندگی کے مختلف گوشے اس کے قبضہ میں ہوں اور وہ ابناء ملک کو ارتقاء کے منازل طے کرانے کی مشق کرائے۔
تیسری شکل طریقِ کار کی پیروی ہے جس کی کار فرمائی مختلف اسلامی حکومتوں میں رہی ہے۔ان حکومتوں کا ابتدائی مطمح نظریہ تھا کہ سیاسی اعتبار سے یورپ سے آزاد ہوکر
معاشی میدان میں اپنی ابتری کا خود علاج کریں لیکن جب اقتصادی مشکلات کو سمجھنے کے لئے آگے بڑھے تو اپنے ذہن کو یورپ کے طریقِ فکر سے آگے نہ بڑھاسکے اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگئے کہ اقتصادی بدحالی کو دور کرنے کے لئے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ یورپ کے انداز فکر اور طریقِ کارکو اپنا لیاجائے۔
طریقِ کار اور تطبیق کے سلسلہ میں عظیم نظریاتی اختلافات کے باوجود عالم اسلام یورپ ہی کے تجربات کا دلدادہ رہاہے۔اور اسی کے طریقِ کار کو مختلف شکلوں میں اختیار کرتا رہاہے یہاں تک کہ آج کے یورپ کی رفتار ترقی پر اتفاق ہوگیا اور یہ بات محل نزاع میں آگئی کہ یورپ کے کس انداز فکر کو اپنایاجائے۔
آج کا مغرب دو مختلف اقتصادی نظریات پر بٹاہواہے ایک راسمالیت جس کی بنیاد آزاد اقتصادی نظام پر ہے اور ایک اشتراکیت جس کی بنیاد محدود اقتصادی نظام پر ہے۔
عالم اسلام نے یہ فیصلہ کرلیاکہ ہماری معاشی بدحالی کا علاج مغرب کے اتباع میں ہے ہماری سیاسی سربراہی کا حق مغرب کو ہے لیکن یہ طے کرنے سے عاجز ہے کہ مغرب اقتصاد کی کون سی شکل ہمارے حق میں مفید ہوگی اور کون سی مضر۔یورپ میں دونوں کے خدمات ہیں۔دونوں نے اقتصادی معیارکے ارتقاء میں حصہ لیاہے اور معاشی بدحالی کو دور کیاہے۔لیکن ہمارے لئے کون سی شکل اصلح ہوگی اور ہم کس طرح اقتصادی قصر کو تیار کرسکتے ہیں یہ محل فکر ہے۔
تاریخی اعتبار سے عالم اسلام میں پہلے راسمالیت کا عمل دخل ہواہے اور نتیجہ میں سرمایہ دارانہ نظام حکومت کو جگہ ملی ہے اس لئے کہ راسمالیت ان ممالک کے ذہن سے زیادہ قریب تھی۔اور اسے مرکزیت حاصل کرنے میں سہولت تھی لیکن دھیرے دھیرے جب امت نے استعمار سے اپنی سیاسی لڑائیوں کا آغاز کیااور استعمار کے اس نظام سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیاتو اس کے سامنے یورپ کا یہ نقشہ آیاکہ وہاں سرمایہ داری سے
نجات حاصل کرنے کا واحد راستہ اشتراکیت ہے اور یہ سوچ کر وہ اسی کی طرف مائل ہوگیا۔ اسلامی ممالک میں اشتراکیت کی طرف رجحان دو مختلف کشمکشوں کا نتیجہ تھا۔
ایک طرف استعمار سے سیاسی جنگیں جاری تھیں جو آزادی کا مطالبہ کررہی تھی اور دوسری طرف یورپ کا ذہنی رعب اور سیاسی تجربہ تھا جو اعلان کر رہاتھاکہ راسمالیت سے بچنے کا واحدراستہ اشتراکیت ہے۔عالم اسلام نے اس راستہ کو اختیار کرلیااور اس وقت تک اختیار کئے رہے گا جب تک اس کے ذہن ودل ودماغ پر یورپ کا تسلط ہے اورر اسمالیت واقعی حالات سے ہم آہنگ وہم رنگ نہیں ہے۔
راسمالیت واشتراکیت دونوں اپنے اندر ایک جذب رکھتی ہیں اور دونوں کے پاس اپنے نظر یات کی کشش کے لئے دلائل ہیں۔راسمالیت کی دلیل یہ ہے کہ یورپ کے سرمایہ دار ممالک کا یہ ارتقاء ان میں پیداوار اور صنعت کی یہ بلندی اسی آزاد معاشی نظام کے اپنانے کا نتیجہ ہے۔
پسماندہ ممالک کا فرض ہے کہ وہ اسی طریقۂ کا رکواپنا کر اپنی بدحالی کا علاج کریں اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آجائیں۔آج اعلیٰ سطح تک پہنچنے کے لئے اتنے تجربات اور زمانے کی ضرورت نہیں ہے جتنی کل تھی۔آج سرمایہ داری کے تمام تجربات رہنمائی کے لئے موجود ہیں۔آج سینکڑوں سال کی محنت ومشقت سے ایجاد کئے ہوئے وسائل پیش پا افتادہ ہیں۔آج راسمالیت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچنے میں کوئی دقت یا دشواری نہیں پیش آئے گی۔
اشتراکیت کی دلیل یہ ہے کہ آزاد معاشی نظام یورپی ممالک میں ضرورفائدہ مند ہوسکتاہے وہاں ٹیکنیک، پیداوار اور اضافہ ثروت کے وسائل ضرور مہیاکرسکتاہے اور کیابھی ہے لیکن دوسرے پسماندہ ممالک میں یہ کارنمایاں نہیں انجام دے سکتا۔ان ممالک کے سامنے مغربی ممالک کی ہولناک ترقی ہے اور ان کے بے پناہ وسائل پیداوار ہیں جوان کو دعوت مقابلہ دے رہے ہیں۔ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔کل کے انسانی نظام میں ایسا
کوئی مقابلہ نہ تھا۔کل کی راسمالیت ان مشکلات سے دوچارنہ تھی۔اس نے فضاکو خوشگوار اور زمین کو ہموار پایاتھا اس لئے آزاد نظام معاش کو اپناکرآگے بڑھ گیاتھا۔اور آج پسماندہ ممالک کو بے شمار پیداواری وسائل وآلات کی ضرورت ہے جن کا مہیاکرنا اشتراکی طرزِ فکر کو اپنائے بغیر ناممکن ہے۔
واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ دونوں نظاموں نے ابتلاء ات ومصائب کا سہارا لیتے ہوئے اسے یہ باور کرادیاہے کہ استعمار کے پیداکئے ہوئے ماحول کا حال راسمالیت و اشتراکیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور وہ بھی گھروندے میں چکر لگاتارہاہے۔ حالانکہ اس کے سامنے ان دونوں علاجوں کے علاوہ سماجی امراض کا ایک مکمل علاج موجود ہے جو نظریات وعقائد کی حد تک ہمیشہ امت اسلامیہ کے ساتھ رہاہے۔یہ اور بات ہے کہ انطباق کے میدان میں اس کی سربراہی نہیں تسلیم کی گئی۔
ہمارامقصد اسلام اور راسمالیت واشتراکیت کا تقابل نہیں ہے۔یہ بات تو کتاب میں مفصل طور پر موجود ہے۔ہمارا مقصد صرف یہ ظاہر کرناہے کہ دنیاکے ان تینوں نظاموں میں کون سا نظام مسلمانوں کے پسماندہ ممالک کی سربراہی کرسکتاہے اور مسلمان کس طرزِفکر کو اپنا کر معاشی دنیا میں قدم آگے بڑھاسکتے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ ہماری بحث ان نظاموں کے فلسفی افکار سے نہ ہوگی بلکہ واقعی حالات سے ہوگی۔
فلسفی افکار نظریہ کی صحت وخطاکا فیصلہ کرتے ہیں اور انطباق کا مرحلہ اس سے بالکل اجنبی ہے۔ایک صحیح وصالح نظریہ بھی میدان انطباق میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتا جب تک اس کے لئے حالات سازگارنہ ہو ں اور معاشرہ کی نفسیاتی اور تاریخی کیفیت کا مطالعہ نہ کرلیاجائے۔خودیورپ میں راسمالیت یاشتراکیت کی کامیابی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے نظریات وافکار میں معاشرہ کی ارتقاء کے عناصر پائے جاتے ہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ حالات کی سازگاری نے اثردکھلایاہو اور یہ نظام ایک تاریخی کڑی بن کر منظر
عام پر آئے ہوں۔ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوگاتو اس تاریخی تسلسل اور اس ماحول سے الگ کرنے کے بعد ان نظاموں کی تاثیر اور فعالیت خود بخود ختم ہوجائے گی۔
ایسے حالات میں اسلام اور اشتراکیت وراسمالیت کی صلاحیتوں کا جائز لیتے ہوئے اس حقیقت کا واضح کردینا ضروری ہے کہ اقتصادی خوشحالی کے لئے کسی اقتصادی نظام کے اپنانے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ ہر حکومت کو ایک اجتماعی نظام چاہئے اور یہ بھی ایک نظام ہے بلکہ اس نظام کی ضرورت اقتصادی حالات کو خوشگوار اور معاشی ابتری کو دور کرنے کے لئے ہے۔ اور یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پوری امت عمل درآمد پر آمادہ نہ ہوجائے اور ایسا نظام رائج نہ کیاجائے جس کے ساتھ چلنے کی اسپرٹ سماج کے اندر بھی ہو۔
سماج کا ارتقاء اور اس کے ارادوں کا استحکام اور فکری صلاحیتوںکی کارکردگی ہی کا دوسرا نام معاشی ارتقاء اور اقتصادی خوشحالی ہے۔رعایا فعال، ارادے مستحکم اور سماج مطمئن نہیں ہے تو معاشی خوشحالی کچھ بھی نہیں ہے۔خارجی ثروت اور داخلی اطمینان کو ایک لائن پر چلنا چاہئے جس کی واضح دلیل خود یورپ کا موجودہ معاشرہ ہے جہاں اقتصادی نظاموں نے اضافہ پیداوار کا وسیلہ بن کر کام نہیں کیاہے بلکہ ان قبائل واقوام کے جہد عمل اور ان کی فعالیت سے فائدہ اٹھایاہے۔نظام طرزِعمل معین کرتارہاہے اور قوم اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لئے نفسیاتی قربانیاں دیتی رہی ہے۔
عالم اسلام کے اندر کسی اقتصادی ارتقاء کا منہاج ودستور معین کرتے وقت ہمیں یورپ کے ان تجربات سے فائدہ اٹھانا پڑے گا اور ان کی روشنی میں ایک ایسے تمدن کو ایجاد کرنا ہوگاجو امت کی تحریک عمل کا باعث ہواور اسے پستی رزبوں حالی کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آمادہ کرسکے اور ایسے حالات کے لئے امت کے تصورات واحساسات اور عقائد وتخیلات کابھی جائزہ لینا پڑے گا تاکہ اس کی قدیم تاریخ کی روشنی میں عوامل ومحرکات
کی تعین کی جاسکے۔
اکثر علماء اقتصاد نے اس مقام پر یہ اشتباہ کیاہے کہ انہوں نے یورپ کے نظام ارتقاء کو پسماندہ ممالک کے لئے صالح قرار دے دیا اور اس نکتہ کو قابل توجہ نہیں بنایاکہ یہ نظام ان ممالک کے باشندوں کے مزاج سے ہم آہنگ ہوسکتاہے یا نہیں اور ان ممالک کی رعایا اس نظام کی متحمل ہوسکتی ہے یا نہیں؟
امت اسلامیہ ایک خاص نفسیاتی شعور رکھتی ہے۔اس کا مزاج استعماری مزاج سے بالکل مختلف ہے۔استعمار کی بنیاد شک وخوف واتہام پر ہے اور امت اسلامیہ نے اپنی برسہابرس کی تاریخ میں بڑے سخت حالات سے مقابلہ کیاہے اس کے دل میں یورپ کے تنظیمی مقاصد کی طرف سے ایک کدورت ونفرت پیدا ہوگئی ہے اور اس کے خلاف شدید قسم کی حساسیت ابھرآئی ہے۔
یورپ کا اقتصادی نظام سیاسی اعتبار سے استعماری طاقتوں سے الگ اور صلاحیتی اعتبار سے کافی ووافی بھی ہوجائے تو امت کی طاقتوں کو ابھارنہیں سکتا اور تعمیر کے معرکہ میں اس کی قیادت نہیں کرسکتا۔ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اسلامیہ اپنے ان نفسیاتی عوامل اور نفرت آمیزجذبات کی بناء پر اپنے اقدام کی بنیاد ایک ایسے صالح اجتماعی نظام پر رکھے جس کا کوئی رابطہ استعماری ممالک سے نہ ہو۔
یہی وہ تلخ حقیقت تھی جس کی بناپرعالم اسلام کے بہت سے سیاسی اجزاء نے قومیت کو اپنانے کا خیال قائم کیا۔ان کے ذہن میں یہ تصورراسخ تھا کہ قومیت ہی زندگی کا فلسفہ اور تمدن کی بنیاد ہے۔وہ اس بات سے قطعی غافل تھے کہ قومیت صرف ایک تاریخی رابطے اور لسانی ارتباط کا نام ہے۔
اس کی کوئی فلسفی بنیادیاعقائدی اصل نہیں ہے۔یہ نتیجہ کارمیں کسی نہ کسی نظریہ کی محتاج ہوجائے گی اور حیات وکائنات کے بارے میں کسی نہ کسی تصور کو اپنالے گی اور اس
طرح اس کی انفرادی حیثیت ختم ہوجائے گی۔
قومیت کی بہت سی تحریکات نے اس کمزوری کا احساس کرلیااور ان کو یہ اندازہ ہوگیا کہ قومیت صرف ایک خام مواد ہے جس کی تکمیل کے لئے ایک اجتماعی فلسفہ اور سماجی تنظیم کی ضرورت ہے۔اسی لئے اس نے اس بنیادی ضرورت کو استعمار کے خلاف استقلالی نعروں کے ساتھ جمع کرنے کی یہ صورت نکالی کہ نظام زندگی کا نام''عربی اشتراکیت''رکھ دیا۔عربی اشتراکیت کا تصورخودہی آواز دے رہاہے کہ قومیت تنہا مصلح عالم نہیں ہوسکتی اس کے لئے ایک سماجی نظام کی ضرورت ہے جس کا نام اشتراکیت ہے لیکن اس اشتراکیت پر بھی عربیت کی چھاپ ہونی چاہئے تاکہ قومیت کا تصور زندہ رہے اور استعمار کے ساتھ انضمام نہ ہونے پائے۔
خارجی تنظیم کی یہ قومی پردہ پوشی بھی ایک مغالطہ سے زیادہ اہمیت پیدانہ کرسکی اور امت اسلامیہ بہت جلد اس نکتہ کی طرف متوجہ ہوگئی کہ یہ صرف ظاہر رنگ وروغن ہے جس میں اجنبی تصورکو چھپایاگیاہے۔ورنہ اشتراکی تنظیم کے کاروبار میں یہ قومی تصور کیادخل اندازی کرسکتاہے یاعربی عامل کے موقف میں یہ اشتراکی تصورکیا انقلاب لاسکتاہے؟بھلا اس لفظ کے کیامعنی ہیں کہ عربیت ایک زبان،تاریخ خون یا جنس ہونے کے اعتبار سے اجتماعی تنظیم کے پورے فلسفہ کو متغیر کرسکتی ہے۔
ہم نے توانطباق کی منزل میں یہی دیکھاہے کہ عربی ذہن نے سماجی میدان میں عربیت کے ان تمام تصورات کو ترک کرد یاہے جو اشتراکیت کے منافی اور مخالف تھے اور جہاں تغیرو تبدل کا امکان نہ تھا۔وہاں عقیدۂ توحید روحانی مسائل اشتراکیت میں کوئی ایسی تازہ روح نہیں پھونک سکے جو اسے استعماری ممالک کی اشتراکیت سے الگ کرسکے۔اتنا ضرور ہواہے کہ ان مسائل کو استثنائی حیثیت دے دی گئی ہے لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ استثناء حقیقت واقعہ کو نہیں بدل سکتاجو ہر جوہر رہے گا اور پردہ،پردہ۔
اشتراکیت عربیہ کے پرستاروں کے لئے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ عربی اشتراکیت، فارسی اشتراکیت اور دوسری اشتراکیتوں کے درمیان کوئی خط فاصل کھینچ سکیں اور یہ بتاسکیں کہ مختلف قومیتوں کی چھاپ لگ جانے سے اشتراکیت کے مفہوم میں کیا فرق پیدا ہوجاتاہے۔
اور جب ایسا نہیں ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ اشتراکیت ایک اشتراکیت ہے جسے قومیت کے ناقص اور محدود تصور کا غلاف اڑھادیاگیاہے اور ہر قوم اپنے قدیم عقائدو نظریات کے تحت اشتراکی قوانین میں استثناء پیدا کرنا چاہتی ہے۔جو ہر سب کا ایک ہے شکلیں بدلی ہوئی ہیں اور شکلوں کے اختلاف کے ساتھ جوہر کا اتحاد خود اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ قومیت اشتراکیت کے مقابلہ میں کوئی نظریہ اجتماعی نظام نہیں ہے۔استعمار سے بچنے کے لئے قومیت کاسہارالینا انتہائی مہمل کام ہے۔
حیرت کی بات تویہ ہے کہ قومیت کے علمبردار اشتراکیت سے الگ تصور قائم کرنے سے عاجز ہوجانے کے باوجود ببانگ دہل اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے قومیت کا تصور صرف اس لئے اپنایاہے کہ امت اسلامیہ استعمار کے مظالم کے خلاف شدید حساسیت کی بناپر کسی استعماری نظام کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔وہ ایک ایسا نظام زندگی اور دستور حیات چاہتی ہے جس کا کوئی رابطہ استعماری ممالک سے نہ ہو اور جس پر کوئی چھاپ اجنبی افراد کی نہ لگ سکی ہو۔
یہیں سے امت اسلامیہ کے سامنے یورپ کے اقتصادیات کے جملہ نظام چاہے ان کی شکل کسی قسم کی کیوں نہ ہو،اسلام کے اس مستحکم نظام سے الگ ہوجاتے ہیں جس کا تعلق اس کی تاریخ اور اس کے ذاتی کمالات سے ہے۔امت اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اسلام ہی اس کی ذاتی تعبیر اور اس کی شخصیت وعظمت کا عنوان ہے۔اسی سے اس کی اصالت و واقعیت اور اسی سے اس کی تاریخی عظمت وبلندی وابستہ ہے اور یہی وہ بات ہے
کہ جو اس کوزبوں حالی کے خلاف ہر معرکہ میں کھڑاکر سکتی ہے اور ارتقاء وعروج کی ہر تحریک میں اس کے قدم آگے بڑھاسکتی ہے بشرطیکہ اس کا طریقۂ کار اسلام کے حقیقی قوانین سے لیاگیا ہواوراس کی حرکت کاعنوان''قیام اسلام''ہو۔
استعمار واستعماریت کے خلاف امت اسلامیہ کا یہ شعور واحساس ہی کیاکم تھاکہ استعمار ظالم ہے اور مظلوم کبھی اپنے ملک میں ظالم نظام کو رائج نہ ہونے دے گا کہ ایک اور عظیم مصیبت سامنے آگئی جو استعماری نظام کے خلاف سد سکندری کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ ہے استعماریت وعقائد کی مخالفت وضدیت میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں استعماراور اسلام کے عقائد وافکار کا تذکرہ کرکے ان کاتقابلی مطالعہ کروں اور آخرمیں یہ ثابت کروں کہ اسلام استعمار کے افکار سے بلند وبالا اور بہتر وبرتر ہے اس لئے اس طرح یہ بحث خالص مذہبی اور عقائدی ہوجائے گی۔میراعقیدہ تو صرف یہ ہے کہ یورپ کے تصورات مرد مسلم کے عقائد کے ساتھ جمع نہیںہوسکتے۔
عقیدہ عالم اسلام کے اندر کار فرماطاقت کا نام ہے جو استعماری تبلیغات کی وجہ سے بڑی حد تک ضعیف ومضمحل ہوگئی ہے لیکن اس کے باوجود انسان مسلم کے سلوک زندگی ایجاد، احساس اور تجدید نظریات پر بہت زیادہ اثرانداز ہے اور یہ پہلے ثابت ہوچکا ہے کہ اقتصادی ارتقاء کا کام کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے حکومت براہِ راست قانون سازی کے ذریعہ انجام دے سکے بلکہ اس کے لئے عوامی جذبات اور قومی خدمات کی ضرورت پرتی ہے جو نظام وعقیدہ کے تناقض واختلاف کی صورت میں ممکن نہیں ہے۔عقیدہ امت کا سرمایۂ افتخار اور زندگی کے اکثر شعبوں میں اس کا نشان زندگی ہے۔اس کے ہوتے ہوئے کوئی مخالف نظریہ اس کی قوتِ عمل کو تیز نہیں کرسکتااور اس طرح ارتقاء وعروج کا عمل بھی انجام نہیں پاسکتا۔
اس کے برخلاف اسلام دشواریوں کا شکار نہیں ہے۔اس کی راہ میں یہ تضاد
وتناقض حائل نہیں ہے۔وہ اس عقیدہ ونظریہ کو میدان عمل میں بہترین معاون ومددگار تصور کرتاہے۔اس کے لئے یہ نفسیت وروحیت بہترین سند اور اعلیٰ ترین حامل ومحرک ہے۔اس کے نظام کی بنیادہی اسلامی شریعت وتعلیمات ہے جسے مرد مومن پہلے سے اپنے گلے لگائے ہوئے ہے اور اس کی تقدیس وعظمت کا قائل ہے۔
وہ یہ سمجھتاہے کہ اسلام ایک سماوی دین اور الٰہی نظام ہے جس کی تطبیق انسانیت کا اولین فرض اور اسلام کی بنیادی مسئولیت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی نظام کے انطباق کے لئے اس کے نفسیاتی احترام اور عقائدی اعزاز سے بالاتر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہی طاقت اس کے جذبۂ ایمان کو آمادہ کرتی ہے اور یہی حقیقت اس کے احساس تطبیق کو بیدار بناتی ہے۔
میں نے ماناکہ یورپین انداز اقتصاد نے معاشرہ کو عروج وارتقاء دے کر اکثرانسانی ذہنوں کو اس بات کی طرف مائل کر لیاہے کہ دین کوئی طاقت نہیں ہے وہ ان تنظیمات کے مقابلہ میں قیام نہیں کرسکتالیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح چودہ صدیوں سے زیادہ مدت میں عقیدہ کی بنیاد پر قائم ہونے والی ہر تعمیر کو مہمل تصور کر لیاجائے اور اس کی پائیداری کا اعتراف نہ کیاجائے بلکہ اس نے عالم اسلام کے انسانوں کے ذہن ودماغ میں عظیم فکری انقلاب پیداکردیاہے اور انہیں اپنے سانچہ میں ڈھال لیاہے اور اگریہ تسلیم کر ہی لیاجائے کہ یورپین نظام اقتصادنے عقیدہ کو بالکل مہمل وبیکار بنادیاہے تو بھی اس بات کا قرار توبہرحال نہیں کیاجاسکتاکہ مسلم معاشرہ میں وہ ذہنیت پیداہوگئی ہے جو یورپ میں وہاں کے نظام اقتصاد کے رواج کے لئے موجود تھی۔مسلم معاشرہ میں یورپین روح کا سرایت کرجانا تقریناً محال ہے اور اس کے بغیر اس نظام کا اس معاشرہ پر نافذ ہونا بھی محال ہے۔
اسلامی معاشرہ میں پیدا ہونے والی اخلاقیت اور ہے اور پورپ کی آغوش میں
پلنے والی اخلاقیت اور ۔دنوں میں نظریات، اقدار ،انداز وسلیقہ وغیرہ کے اعتبار سے بنیادی امتیازات پائے جاتے ہیں اور جب تک اختلافات موجود رہیں گے یورپین ذہن جس قدر یورپی نظام اقتصاد کے لئے سازگار رہے گا اسی قدر اسلامی ذہن اس نظام کے لئے مضر اور غیر موافق رہے گا اور یہ وہ جڑیں ہیں جو عقیدہ کی کمزوری کی وجہ سے اکھاڑی نہیں جا سکتیں اور ان کا استیصال ان معمولی ذرائع سے ناممکن ہے۔
مقصد یہ ہے کہ پسماندگی اور زبوں حالی کے خلاف جہاد کرنے کے لئے جس طرح ملک کی طبیعی کے استحکام کی ضرورت ہے تاکہ وسائل پیداوار سے سازگاری پیدا ہو سکے اسی طرح انسانی عنصر کے استحکام اور اس کے مفروضہ نظام ودستور سے ہم آہنگ ہونے کی بھی ضرورت ہے جو موجودہ صورت حال میں قطعی مفقود ہے۔یورپ کا انسان صرف زمین کو دیکھنا چاہتا ہے اس کا مسیحی مذہب سینکڑوں سال کا دین وآئین ہونے کے باوجود یورپ کے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور ذہن انسان کو زمین سے بلند کرکے آسمان تک پہنچانے کے بجائے اللہ ہی کو آسمان سے زمین پر اتارلایا اور اسے ایک خاکی مخلوق کی شکل دے دی۔
یورپ میں عام حیوانات کے درمیان انسانی آباء و اجداد کی تلاش اور انسان کو حیوانات کی ترقی یافتہ شکل قرار دینے کا فلسفہ عالم انسانیت کی پیداواری وسائل کی بنیاد پر تعمیر اس بات کی شاہد ہے کہ یورپ نے آسمان والے کو زمین پراتار لیا ہے اور انسان اکبر کو حیوانات کی بزم میں بٹھا دیا ہے۔ اس کی نفسیات اور اخلاقی قدریں انسان کو خاک سے مربوط کرنا چاہتی ہیں۔
اگر چہ ارتباط کی شکلیں اور اس کے انداز واسلوب بدلے ہوئے ہیں۔
یورپ میں زمین کی یہی وہ عظمت تھی جس نے مادہ، ثروت اور ملکیت کے ایسے مفاہیم جنم دئیے جو اس نظریہ سے ہم آہنگ ہو سکیں اور دھیرے دھیرے ان مفاہیم وتصورات نے یورپین ذہن پر قبضہ کر لیا۔لذت ومنفعت جیسے مذاہب پیدا ہوئے اور
اخلاقیات کا فلسفہ میدان سے ہٹا دیا گیا۔ لذتیت مقامی پیداوار تھی اس لئے اسے سازگار فضائلی اور اخلاقیات دوسرے ماحول کے پروردہ تھے ۔ اس لئے انہیں سانس لینے کا موقع نہ مل سکا۔
جدید تصورات نے عوام کی طاقتوں کی ابھارنے میں بہت اہم رول ادا کیا اور ارتقاء وعروج کا سارا کاروبار انہیں کے زیر سایہ ہونے لگا۔امت کی رگ رگ میں ایک نشاط انگیز حرکت پیدا ہو گئی اور ہر ایک کی ذہنیت یہ طے پائی کہ جب تک مادہ اور اس کے خیرات ملکیت اور اس کے برکات سے سیری نہ ہو جائے رفتار عمل کو سست نہ ہونا چاہئے۔
دوسری طرف یورپین انسان کے ذہن سے تصور الٰہ کا محوہو جانا اور اس کا آسمان کے بجائے زمین سے رشتہ قائم کر لینا اس کے ذہن ودل کی گہرائیوں سے ہر بلند وبالا اخلاقی قدر کو نکلا پھینکنے کا باعث ہو گیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھ سے بالا تر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو میرے لئے قوانین وضع کر سکے۔نتیجہ کے طور پر حریت و آزادی کا عقیدہ مستحکم ہو گیا اور احساس شعور نے استقلال وانفرادیت میں غرق کر دیا اور جب اسی خود پرستی کو فلسفہ کے سانچہ میں ڈھالنا ہوا تو یورپ کی تاریخ کا سب سے اہم فلسفہ ''وجودیت''منظر عام پر آگیا۔ اس فلسفہ نے یورپ کے خیالات کو علمی رنگ دے دیا اور اس کی روشنی میں یورپین انسان اپنے تمام احساسات وجذبات کی تکمیل کا جلوہ دیکھنے لگا۔
حریت وآزادی نے یورپین اقتصادیات میں بہت بڑا کار نمایاں انجام دیا۔ اس نے یورپ کے ذہن میں استقلال و انفرادیت کے چھپے ہوئے جذبات سے بے حد فائدہ اٹھایا اور اسے یہ باور کرادیا کہ انسانی خواہشات وجذبات کی تکمیل کا واحد سہارا یہی آزاد اقتصاد اور فلسفہ حریت ہے۔الٰہیات کی منزل میں ذہنی آزادی یورپ کے دل و دماغ میں یوں سرایت کر گئی تھی کہ وہ خود پرستی کے علاوہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے یہاں وہی نظام کامیاب تھا جس میں تسکین نفس کے اسباب اور احساس انفرادیت کے وسائل موجود
ہوں یہی وجہ ہے کہ یورپ میں سرمایہ داری کی جگہ پر آنے والی اشتراکیت نے اس جذبہ سے ٹکر نہیں لی اور عوام کو خود پرستی ہی کی تعلیم دی ۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے کی انفرادیت تھی اور اب طبقاتی ہو گئی ۔ اب ہر طبقہ ایک فرد ہے اور ہر جماعت ایک شخص۔
کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ تمام امور اتفاقی نہ تھے بلکہ ایک سمجھے بوجھنے فلسفہ کا نتیجہ تھے ۔حریت کے عقیدہ نے میدان عمل میں بہت کچھ سہارا دیا تھا اورمسئولیت کے احساس کے فقدان نے ہر میدان عمل میںتیز قدم بنا دیا تھا جو ایک اقتصادی تحریک کے لئے بڑی حد تک ضروری تھا وہاں سماجی تناقض وتصادم کو سمجھانے کے لئے کسی فلسفہ کی ضرورت نہ تھی۔
خود حریت ہی اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ ہر آدمی کو اپنے میدان میں مطلق العنان اور آزادد ہونا چاہئے۔اور یہ بات اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کوئی دوسرا مقابلے میں آکر اس کی حریت کو محدود نہ بنا دے۔مقابلہ و تصادم کے اسی تصور نے اسے سماجی ٹکراؤ پرآمادہ کر دیا .....اور وہ بغیر کسی خارجی تحریک کے مقابلہ کے میدان میں اتر آیا۔
ضرورت اس بات کی تھی کہ اس نفس پرستی کو بھی کوئی فلسفی رنگ دیا جائے اور اس تصادم کے جواز کی بھی کوئی عملی شکل تلاش کی جائے ۔چنانچہ دوسرے ماحول زدہ تصورات کی طرح '' تنازع للبقائ'' کا فلسفہ منظر عام پر آ گیا اور یہ طے پا گیا کہ '' بقاء کے لئے نزاع حیات کا طبیعی قانون ہے ۔'''' سماج میں طبقاتی تصادم فطری بات ہے۔''دنیا کا سارا نظام تین چیزوں کی بنیاد چل رہا ہے۔''
(1)اثبات
(2)نفی
(3)نتیجہ
یورپ کے پورے فلسفہ کا یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ اس کے فلسفہ کے پیچھے کوئی علمی بنیاد یا فلسفی تقاضہ نہیں ہے ۔وہ موجودہ معاشرہ کی ایک آواز عوام کے ذہنوں میں راسخ جذبات کی
علمی تعبیر ہے۔
یورپین اقتصاد اور اس کے کاروباری ترقی میں اس تصادم نے بھی بڑا کام کیا ہے چاہے اس کی شکل انفرادی رہی ہو جہاں ٹکراؤ ذاتی کارخانوں اور ملوں کے مالکوں ہیں ہوتا ہے اور ہر ایک بقاء کے لئے نزاع کرتا ہے یا اس کی شکل طبقاتی ہو جہاں انقلابی جماعتیں پیداوار کے کلیدی امور پر قبضہ کرکے ملک کی پوری پیداواری طاقت کو اقتصادی صلاح پر صرف کرتی ہیں۔
یورپ کی یہی اخلاقی اور نفسیاتی صورت حال ہے جس کی بناء پر اس کے اقتصادیات نے قدم آگے بڑھائے اور آخر میں ترقی کرکے بڑے بڑے فوائد حاصل کر لئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورت حال عالم اسلام کے حالات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں کی پوری تاریخ دینی ہے ۔یہاں کا انسان آسمانی رسالتوں کا پروردہ اور سماوی ممالک کا باشندہ ہے۔ اس کی تربیت دین کے ہاتھوں اسلام کی آغوش میں ہوئی ہے ۔ اس نے زمین سے پہلے آسمان پر نظر ڈالی ہے اور عالم مادہ احساس سے پہلے عالم غیب پر اعتماد کیا ہے۔
غیب کا یہی عقیدہ اور غیبات سے یہی عشق تھا جس نے مسلمانوں کی زندگی کی فکری سطح بڈل ڈالی اور وہ ہر مسئلہ پر محسوسات سے بلند ہو کر عقلی پہلوؤں پر غور کرنے لگے ۔ مزاجی طور پر اتنا انقلاب پیدا ہو گیا کہ مادہ کی ابھارنے والی طاقتیں ممدود ہو گئیں اور معنوی اعتبار سے مادہ سے ہم آہنگ وہم رنگ نہ ہو سکنے کی صورت میں منفی موقف اختیار کرنا پڑا۔ جس کا نام کبھی زہد پڑا،کبھی قناعت اور کبھی کسلمندی اور سستی۔
ایمان بالغیب کا دوسرا اثر یہ تھا کہ انسان ذہنی طور پر ایک غیبی نگرانی سے متاثر رہنے لگا جسے صاحب تقویٰ مسلمان کے الفاظ میں رب العالمین کے سامنے احساس مسئولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آزاد خیال مسلمان کے الفاظ میں ضمیر کے محاسبہ سے یاد کیا جاتا ہے اور دونوں صورتوں میں یہ مسلم ہے کہ مسلمان ذہن اس احساس حریت سے کوسوں دور ہے جو
یورپی معاشرہ کا سرمایۂ افتخار ہے اور اس کے اخلاقیات اس اقدار سے بالکل مختلف ہیں۔
مرد مسلم کا یہی غیبی شعور جو اسے اخلاقی احکام کی بناء پر داخلی طور پر مفید وممدود بنا دیتا ہے۔ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس جماعت کے مفاد کے بارے میں غور وفکر کرے جس کے درمیان زندگی گذارتا ہے اور جس سے ایک داخلی وابستگی رکھتا ہے۔ اس کے ذہن پروہ تنازع وتصادم مسلط نہیں ہونے پاتا جسے یورپ کے افکار نے پیدا کیا ہے اور جس کی بنیاد داخلی حریت و آزادی پر ہے۔
مرد مسلم کی جماعتی فکر نے اسلامی پیغام کے عالمی ڈھانچہ کو اتنا معزز بنا دیا ہے کہ اب ہر مسلمان اپنے اوپر ایک عالمی مسئولیت محسوس کرتا ہے جو حدود زمان ومکان سے بالاتر ہے مسلمانوں نے ہر دور میں عالمی رسالت کا کام انجام دیا ہے اور پوری انسانی جماعت کا پاس ولحاظ رکھا ہے۔
اس اخلاقیت نے اس کے دل ودماغ پر ایسا قبضہ کیا ہے کہ امت کے پورے وجود میں سرایت کر گئی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی حقیقت اقتصادی نظام کو آگے بڑھانے میں بھی کافی کار آمد ہو سکتی ہے اور اسے بھی اپنے سانچہ میں ڈھال سکتی ہے۔ اخلاقی قدریں مسلم معاشرہ میں ویسی ہی فعال ومحرک ہی جیسی فعالیت حریت وآزادی کو یورپ معاشرہ میں حاصل ہے۔
مسلمان کا زمین سے پہلے آسمان پر نظر رکھنا اور شہود سے پہلے غیب سے متاثر ہونا زمین و مادہ کے مقابلہ میں اس کے ذہن کو منفی پہلو بھی عطا کر سکتا ہے اور یہ بہت ممکن ہے کہ زمین کے آسمان سے الگ ہو جانے کی صورت وہ زہد و قناعت یا کسلمندی کا راستہ اختیار کر لے اور ان خیرات وبرکات کو خیرباد کہہ دے ۔ ہاں اگر زمین کو آسمانی رنگ دے دیا جائے اور عمل کو واجب کا درجہ یا عبادت کا تصور دے دیا جائے تو غیبی نظریہ سے بالاتر کوئی ایجابی طاقت بھی نہیں ہے ۔ یہی طاقت میدان عمل میں جد وجہد پر آمادہ کر سکتی ہے اور یہی طاقت اقتصادی سطح کو بلند تر بنا سکتی ہے۔
مسلمان را سمالیت واشتراکیت کے زیرسایہ جس نفسیاتی قلق واضطراب کا احساس رکھتا ہے اور مذہب کے مسئلہ میں سہل انگاری اور لا پروائی کے باوجود جس کشمکش کا شکار ہے اس کا حل اس کی اخلاقی قدروں کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے ۔ مسلمان جب تک اسلامی ذہن اور یورپین نظام کو ہم آہنگ بنانے کی کوشش کرتا رہے گا اس وقت تک اس الجھن اور اضطراب سے نجات نہیں پا سکتا ہے۔
اضطراب وانتشار سے نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اسلام کے نظام اقتصاد کو بروئے کار لایا جائے اور ذہنی کشمکش کی جگہ ذہنی توافق وتناسب کو دی جائے۔جیسی زمین ہو ویسی تخم ریزی اور جیسی ذہنیت ہو ویسا ہی نظام داخلی۔ مسئولیت اور غیبی نگرانی جہاں یورپین نظام کو کامیاب نہیں بننے دیتی وہاں مسلمان میں اس نظام سے پیدا ہونے والے مصائب کے مقابلہ میں جذبۂ قربانی بھی پیدا کر دیتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان صرف اس دستور نظام کو پانا چاہتا ہے جو اس کے عقیدۂ مسئولیت ونگرانی سے ہم آہنگ ہو اور اس کی اخلاقی قدروں کا تحفظ کرتا ہو۔
اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان میں پوری جماعت کے مفاد کا تصور زبوں حالی اور پسماندگی کے خلاف معرکہ آرائی کے لئے طاقتیں بھی فراہم کرتاہے۔خصوصیت کے ساتھ اس وقت جب معرکہ کا شعار اس کے مخصوص عقائد ونظریات سے ہم آہنگ ہوجائے اور جدوجہد کو تحفظ امت کے لئے جہادفی سبیل اللہ کا درجہ دے دیاجائے جیساکہ قرآن کریم نے اعلان کیاہے''دشمنوں کے مقابلہ کے لئے ہر قسم کی قوت مہیارکھو۔''
مقصد یہ ہے کہ پیداوار کی سطح بلندکرنے کے لئے اقتصادی طاقتوں کو بھی ابھارتے رہو۔اس لئے کہ یہ بھی امت کے تحفظ وبقاء کے بہترین جہاد اور اس کی سیادت وشرافت کو قائم ودائم رکھنے کے لئے بہترین معرکہ ہے۔
در حقیقت یہی وہ حالات ہیں جن سے مسلم معاشرہ میں اسلامی اقتصادیات
کی اہمیت کا اندازہ ہوتاہے اور یہ محسوس ہوتاہے کہ اسلامی اخلاقیت کس طرح ایک فعال طاقت اور تعمیری اقدام کا کام دیتی ہے۔
اسلامی نظام کا رواج اس اخلاقیت سے فائدہ اٹھاسکتاہے۔اسے پسماندگی کے خلاف جدوجہد میں استعمال کرسکتاہے اور دوسرا نظام اس سے کوئی استفادہ نہیں کرسکتابلکہ اس کے لئے یہ نظریات ونفسیات ایک سنگ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔جیسا کہ یورپ کے بعض مفکرین نے احساس کیاہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اقتصادی نظام اسلامی طبیعت وعقلیت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوسکتا۔
''جوک اسٹروی''اپنی کتاب''اقتصادی ارتقائ''میں اس حقیقت کا کھلاہوا اعتراف کرتاہے۔یہ اور بات ہے کہ وہ اس کے منطقی تسلسل کا ادراک نہیں کرسکا اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ یورپین اخلاقیت اور اسلامی ذہنیت کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟
ان کی کڑیاں اور حدود اربعہ کہاں سے کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں اور اسی لئے اس نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائی ہیںجن کی طرف استاد محمد المبارک نے مقدمۂ کتاب ہی میں اشارہ کر دیاہے۔اور استاد نبیل صبحی الطویل نے عربی ترجمہ میں واضح کردیاہے۔
میرادل چاہتاہے کہ میں آئندہ کسی فرصت میں اس موضوع کو تفصیل سے لکھوں اور یہ واضح کروں کہ اس کے اسباب وعوامل کیاہیں؟
لیکن اس وقت تو اختصار کے ساتھ صرف اتنا کہنا ہے کہ عالم اسلامی کا آسمان کی طرف متوجہ رہنا۔اس کے قضاوقدر کے سپردہوکراپنے کو حالات کے حوالے کردینے کے مرادف نہیں ہے۔
آسمانی غیبیات پر عقیدہ اس کی قوت عمل کو مفلوج ومشلول نہیں بناتاجیساکہ جوک اسٹروی نے خیال کیاہے بلکہ یہ عقیدہ انسان میں آسمانی خلافت کے تصور کو مستحکم بناتاہے اور اسے یہ احساس دلاتاہے کہ وہ زمین پر اللہ کاخلیفہ اور جانشین ہے اس کی ذمہ داری روئے
زمین کو آبادومعمور رکھنا ہے۔
میری نظرمیں انسانی طاقت وقدرت کی کوئی ضمانت اس سے بالاتر نہیں ہے کہ وہ کائنات کے مالک اور احکم الحاکمین کا نمائندہ ہے اور اس کی مسئولیت وذمہ داری کی اس سے بلند تر کوئی دلیل نہیں ہے جتنی خلافت ونیابت کی مسئولیت ہے۔خلافت مملکت میں مسئولیت کا تقاضہ کرتی ہے اور مسئولیت حریت و ارادہ۔شعور واختیار کے ساتھ حالات کو بدلنے کا مطالبہ کرتی ہے۔
وہ خلافت بے معنی ہے جس کے ساتھ اختیار واقتدار نہ ہو اور وہ نیابت بے مقصد ومفہوم ہے جو کسی مقیدواسیر کے حوالہ کر دی جائے۔اسی لئے میں نے یہ دعویٰ کیاہے کہ زمین کو آسمان کا رنگ دے دینا مرد مسلم کی طاقتوں کو ابھاردینے اور اس کے امکانات کو بیدار کردینے کے مرادف ہے۔اورزمین کا آسمان سے جداکرکے اس کے رشتے کو منقطع کردینا معنیٰ خلافت کو معطل کرکے اسے جامد بنادینے کے برابر ہے۔
انسان کی سلبیت اور ا س کی طاقتوں کا منفی پہلو آسمان کے رابطہ سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ قوائے عمل کے سست ہوجانے سے پیداہوتاہے جو زمین کو اسلامی عقلیت واخلاقیت کے مخالف رنگ دے دینے کا واضح نتیجہ ہے۔
اس کے علاوہ اسلام کوپوری زندگی کی بنیاد قراردینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس طرح زندگی کے مادی اور روحانی دونوں پہلو ایک بنیاد پر قائم ہوں گے اور روح وجسم دونوں کی تسکین کا مکمل سامان ہوگا اور دوسرے نظاموں کے اپنانے میں اجتماعی تعلقات اور مادی حیات کی اصلاح ہوسکے گی لیکن روحانیت پامال ہوجائے گی اور اس کے لئے دوسرے نظام کی تلاش کرنا پڑے گی۔جو دور حاضر میں اسلام کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔
مقصد یہ ہے کہ اجتماعی تنظیم میں کسی ایسے دستور کا اپنانا جس سے اسلام کے روحانی نظام کی ضرورت باقی رہ جائے انتہائی مہمل کام ہے جب کہ اسلام جیساجامع اور ہمہ گیر نظام
موجود ہے جو روح وجسم کی بیک وقت تسکین کرتاہے اور ایک کودوسرے سے الگ نہیں ہونے دیتا۔اسلام وہ واحد دستور حیات ہے جو اپنی ضرورت کو اس وقت تک محسوس کرتارہے گا جب تک اسلام میں روحانی اور اجتماعی نشاط کی ضرورت باقی ہے اور دونوں باہمی اتفاق واتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔
محمد باقرالصدر
ابتدائیہ
ناظرین کرام !کتاب'' فلسفتنا'' کے خاتمہ میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ کتاب ان اسلامی درسیات کی پہلی کڑی ہے جن کا تعلق براہ راست اسلام کی بنیادی عقیدہ ''توحید''سے ہے اور اس کے بعد اس تعمیر کے دیگر طبقات سے بحث کی جائے گی تاکہ اس طرح انسا ن کے ذہن میں اسلام کی ایک مکمل تصویر آ جائے اور وہ یہ اندازہ کر سکے کہ اسلام ایک زندہ عقیدہ اور زندگی کے لئے ایک مکمل نظام ہے جس میں تربیت فکر کے صحیح طریقے بیان کئے گئے ہیں۔
''فلسفتنا''کے اختتام پر یہ تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اس سلسلہ کی دوسری کڑی اسلامی اجتماعیات کو قرار دیا جائے گاتاکہ اس سے حیات کے بارے میں اسلامی افکار اور پھر ان کے تحت تشکیل پانے والے عملی نظام کا صحیح تجزیہ کیا جا سکے لیکن بعض احباب کے اصرار نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ معاشیات کی بحث کو اجتماعیات پر مقدم کر دیا جائے۔
اس لئے کہ معاشیات عصر حاضر کا حساس ترین موضوع ہے اور اس کے بارے میں اسلام کے افکار واقدار، تعلیمات وامتیازات کا سامنے آنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے
اسی اصرار کا لحاظ کرتے ہوئے انتہائی کوشش سے اس سلسلہ کو قلیل مدت میں مکمل کر دیا تاکہ کتاب بر وقت منظر عام پر آ سکے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض نا گزیر حالات کی بناء پر کسی نہ کسی قدر تاخیر ضرورہو گئی تاہم علامہ جلیل السید محمدباقر الحکیم کے خدمات کاتذکرہ بھی انتہائی ضروری ہے ۔ جن کے ذریعے ان سخت حالات کا مقابلہ کرکے کتاب کو منظر عام پرلایا گیا ہے۔
اقتصادیات کے بارے میں بحث کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتاہے کہ اس لفظ کے سلسلہ میں بعض ان اشتباہات کا ازالہ کردیاجائے جن میں اکثر اہل قلم مبتلا ہوگئے ہیںاور اس طرح یہ موضوع اپنے تاریخی ابہام پر باقی رہ گیاہے۔
یادرکھئے اقتصادیات کے بارے میں دوقسم کی بحثیں ہوتی ہیں۔جن میں سے ایک کو دوسرے سے جداکرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ مطلوب نہایت ہی واضح شکل میں ہمارے سامنے آسکے۔ان دونوں قسموں کا عنوان ہے نظری اقتصاد اور عملی اقتصاد جس کو علمی اور مذہبی کے عنوان سے بھی دیا کیاجاسکتاہے۔
نظری یا علمی اقتصاد سے مراد ان قوانین کا معلوم کرناہے جن کے ذریعہ اقتصادی زندگی کے آثار وظواہر کے اسباب وعلل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔
ظاہر ہے کہ اس پہلو کے اعتبار سے یہ علم بالکل نوزائیدہ ہے اس کا وجود چار صدی قبل بھی نہ تھا۔یہ اور بات ہے کہ تاریخ کے ہردور میں انسان نے لاشعوری طور پر ان اسباب وعلل کو معلوم کرنے کی کوشش کی ہے خواہ وہ ان نتائج تک نہ پہنچ سکا ہوجو قدرت نے آخری صدیوں کے لئے محفوظ کر رکھے تھے۔
عملی یا مذہبی اعتبار سے اقتصاد سے مراد اس طریقۂ زندگی کا معلوم کرنا ہے جس سے انسان کے اجتماعی حالات خوشگوار ہوسکیں اور وہ اپنے عملی مشکلات کو حل کرسکے۔
اس پہلو کے اعتبار سے کوئی ایسا معاشرہ متصور ہی نہیں ہوسکتاجو عملی اقتصادیات سے خالی رہاہو۔ اسلئے کہ جب بھی کسی معاشرہ نے پیداوار اور تقسیم ثروت کے اعمال انجام
دئے ہوں گے تو ان کے لئے کوئی نہ کوئی نظام یا دستور ضرورمرتب ہوگا اسی نظام سے اس کے عملی اقتصاد کی تحدید ہوسکتی ہے۔
اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اقتصادی زندگی کی تنظیم کے لئے کسی ایک طریقہ کاا ختیار کرلینا کوئی اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ اس کی پشت پر کچھ اخلاقی ،عملی یا کسی دوسرے قسم کے افکار ہوتے ہیں جو اس طریقہ کے خطوط ونشانات معین کرتے ہیں لہٰذا ہر عملی بحث سے پہلے ان افکار کا جائزہ لینا ضروری ہے جن کی بناپر کوئی طریقۂ کار اپنایاگیاہے یا کسی نظام معیشت کو حتمی قرار دیاگیاہے۔
مثال کے طور پر اگر ہم سرمایہ دار نظام کی اقتصادی آزادی پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان افکار کا جائزہ لینا پڑے گا جن کی بناپر سرمایہ دار نظام آزادی کا احترام کرتاہے اور اس کی بقاء کی راہیں پیداکرتاہے۔
نظری اقتصاد نے جب سے انسانی فکر کی راہوں پر تسلط پیداکرنا شروع کیاہے اسی وقت سے ایسا ہونے لگاہے کہ عملی اقتصادیات ان نظری فکروں سے متاثر ہوجاتے ہیں۔
مثال کے لئے یوں سمجھ لیجئے کہ اہل تجارت نے جب یہ طے کر لیاکہ نظری اعتبار سے ثروت وسرمایہ نقد مال کا نام ہے تو انہوں نے فوراً یہ عملی نظام تشکیل دے دیاکہ تجارت کو فروغ دیاجائے۔زیادہ سے زیادہ مقدار میں مال باہر بھیجا جائے۔درآمد کی قیمت برآمد سے کم لگائی جائے تاکہ اس طرح ثروت یعنی نقدمال کا اضافہ ہوسکے۔
مالتھس نے مردم شماری کی بناپر یہ فیصلہ کیا کہ انسانی پیدائش غلہ کی پیداوار سے کہیں زیادہ ہے اور اس طرح مستقبل میں ایک ہولناک قحط کا اندیشہ ہے۔چنانچہ اس نے تحدید نسل کا قانون وضع کر دیااور اس کے سیاسی واخلاقی احکام بھی بناڈالے۔
اشتراکی مفکرین نے مال کی قدروقیمت کو مزدور کی محنت ومشقت کا نتیجہ قرار دیا اس لئے ان کی نظرمیں سرمایہ دارانہ منافع حرام ہوگئے اور مال تمام ترمزدوروں کاحق
ہوگیااس لئے کہ انہیں کے تواناہاتھوں نے مادر گیتی کے شکم سے قیمت کو پیداکیاہے۔
مارکس نے اپنے دور میں اتنا اضافہ اور کر دیا کہ تاریخ کے جملہ تغیرات زمانہ کے بعض مادی حالات کے تغیر کا نتیجہ ہیں۔چنانچہ اس کی اس تازہ فکر کی بناپر یہ ضروری ہوگیاکہ عملی اقتصاد کی بحث سے پہلے ان تاریخی عناصر کا تجزیہ کیاجائے جن کی بناپر مارکس کے خیال میں نظام زندگی کا بروئے کارآناقہری اور لازمی تھا۔
دوسرے لفظوں میں یہ کہاجاسکتاہے کہ اب تک عملی اقتصادیات کے قوانین پر تجارتی طبیعیاتی اور جنسی قوانین حکومت کر رہے تھے اور اب مارکس کے نظریہ کی بناپر تاریخ کے قوانین بھی ان اقتصادی قوانین میں دخل اندازی کرنے لگے اوران کا تجزیہ بھی ضروری ہوگیا۔
اس تمہید سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اسلامی اقتصادیات سے مراد نظری اقتصاد نہیں ہے۔اس لئے کہ یہ علم صفحۂ تاریخ پر بالکل نوزائندہ ہے بلکہ اس سے مراد علمی اور مذہبی اقتصاد ہے کہ جس کا موضوع بحث وہ احکام وتعلیمات ہیں جنہیں اسلام نے انسان کی اقتصادی زندگی کے لئے وضع کئے ہیں۔یہ اور بات ہے کہ انہیں احکام کی روشنی میں علوم جدیدہ کے قوانین کا سہارا لیتے ہوئے ان بنیادی نظریات کا بھی اندازہ لگایا جاسکتاہے جو اسلام نے نظری اقتصاد کے میدان میں اختیارکئے ہیں۔
اقتصادیات کے بارے میں اسلام نے اپنا نظریہ کبھی توبراہ راست ظاہر کر دیا ہے اور کبھی ضمنی طور پر دیگر تعلیمات کے ساتھ ملاکر بیان کیاہے۔مثال کے طورپر یوں سمجھ لیجئے کہ سرمایہ کے بارے میںاسلام کا نقطۂ نظر معلوم کرنے کے لئے ہمیں اس معاملہ پر نظر کرنا پڑے گی جو اس نے سرمایہ دارانہ منافع کے ساتھ کیاہے۔
پیداوار کے آلات ووسائل کے بارے میں اس کا نظریہ ان احکام سے معلوم ہوگاجو اس نے اجارہ(کرایہ پرکسی شیء کودے دینا)،مضاربہ(کسی شخص کو تجارت کے لئے
مال دینا اور پھر منافع کی فیصدی تقسیم کرنا)،مزارعہ(کسی شخص کوزراعت کے لئے زمین دینا پھر منافع کی بانسبت تقسیم کرنا) وغیرہ کے ابواب میں تقسیم ثروت کے موقع پر وضع کئے ہیں۔
مالتھسکے نظریہ کے بارے میں اس کا نصب العین تحدید نسل کے قانون سے معلوم ہوسکے گا۔اسی طرح تاریخی مادیت کے بارے میں اس کا عقیدہ اس کی اس ثابت و پائیدار طبیعت سے معلوم کیاجائے گا جو تاریخ کے ہر دور کی رہبری کرتی رہی ہے اور اس کے کسی دور سے بھی متاثر نہیں ہوئی۔
اب جب کہ ہم اسلامی اقتصادیات کے مفہوم کو بقدرضرورت واضح کر چکے ہیں تو اصل موضوع کی طرف توجہ کرتے ہوئے کتاب کے اجزاء کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کتاب کی پہلی فصل میں مارکس کے نظریہ سے بحث کی گئی ہے اور چونکہ اس نظریہ کا دارومدار تاریخی مادیت پرہے۔اس لئے پہلے اس کا تجزیہ کیاگیاہے۔اس کے بعد اصل موضوع کو چھیڑاگیاہے۔
دوسری فصل کا تعلق سرمایہ داری سے ہے جس میں اس نظام کے اصول اور اس کے نظری اقتصاد سے ارتباط کو واضح کیاگیاہے۔تیسری فصل میں اسلامی اقتصاد کے بنیادی افکار کی طرف اشارہ کیاگیاہے۔
چوتھی اور پانچویں فصل میں انہیں افکار کے تفصیلات کو عنوان قرار دیتے ہوئے طبیعی ثروت کی تقسیم، شخصی ملکیت کی تحدید،توازن اجتماعی، کفالت باہمی،ضمانت معاشرتی ، صلاحیات حکومت، سیاست مال،وسائل پیداوار وغیرہ سے بحث کی گئی ہے اور اس طرح اسلامی معاشیات کا مکمل نقشہ بالبصیرت حضرات کے سامنے پیش کیاگیاہے۔
آخر کلام میں چند اہم نکات کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے جن کی طرف متوجہ رہنا اصل کتاب کے سمجھنے کے لئے بیحد ضروری ہے:
(1) اقتصادیات کے بارے میں اسلام کے افکار کو کتاب میں استدلالی رنگ نہیں دیا گیا
اس لئے کہ یہ بات موضوع کتاب سے خارج ہے بلکہ اگر کسی مقام پر آیت یا روایت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے تو اس کا مقصد بھی اجمالی اشارہ ہے۔اصل استدلال اپنی پوری تفصیل کے ساتھ فقہ کی کتابوں سے معلوم کیاجاسکتاہے۔
(2) فقہ کے اکثرمسائل اس کتاب میں صرف اس لئے اختیارکئے گئے ہیں کہ انہیں دیگر فقہاء کرام نے پسند فرمایاہے۔اگرچہ مؤلف کی ذاتی رائے اس کے خلاف ہے۔
(3) کتاب کے اکثرمقامات پر شرعی احکام صرف قوانین واصول کی شکل میں بیان کردیئے گئے ہیں اس لئے کہ تفصیلات کا بیان کرنا ہمارے موضوع سے خارج تھا۔
(4) کتاب کے اکثر مقامات پر یہ اشارہ کیاگیاہے کہ اسلام کے جملہ احکام ایک باہمی تسلسل وارتباط رکھتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ احکام صرف ارتباطی قسم کے ہیں کہ ایک حکم کے ساقط ہوجانے سے پوری شریعت ساقط ہوجائے۔بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان احکام سے صحیح استفادہ اسی وقت ہوسکتاہے جب انہیں مکمل طورپر اپنی زندگی پر منطبق کر لیاجائے۔
(5) بعض مقامات پر اسلامی اقتصادیات کی ایسی تقسیم کی گئی ہیں۔جنہیں آپ صریحی طورپر کسی آیت وروایت میں نہ دیکھیں گے۔یہ خیال رکھیں کہ ان باتوں کو اسلام کے مجموعی احکام سے اخذ کیاگیاہے۔اگرچہ اس مطلب کے سمجھنے کے لئے کافی غور وفکر کی ضرورت ہے۔
(6) کتاب میں بعض ایسی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں جن سے شبہہ کا احتمال تھا اسلئے ہم نے بقدرضرورت ان کی توضیح کردی ہے چنانچہ حکومتی ملکیت کے بارے میں ہم نے واضح کردیاہے کہ اس سے مراد خدائی منصب کی ملکیت ہے،جس میں صاحب منصب یا اس کا وکیل تصرف کرتاہے۔اس کا تعلق عام حکومتوں سے نہیں ہے۔
خاتمۂ کلام میں یہ بات بھی واضح کردی جائے کہ اس کتاب میں نہ سطحی مطالب
ہیں اور نہ ادبی رنگ،نہ ضخیم کلمات ہیں نہ مغلق الفاظ۔یہ تو ہماراایک بنیادی اقدام ہے اسلامی اقتصادیات کے ان اسرار کو معلوم کرنے کا جن پر اس نظام کی بنیادیں قائم ہیں(اب ہم جس قدر بھی کامیاب ہوسکیں)۔
آپ سے التماس ہے کہ کتاب کا مطالعہ ایک بنیادی اقدام کی نظر سے کریں تاکہ آپ پر یہ واضح ہوسکے کہ اقتصادی زندگی اور تاریخ انسانیت کے حدود اسلام کی نظرمیں کیاہیں؟
اس کے بعد ہماری توفیقات ذات واجب سے وابستہ ہیں اسی پر ہمارا اعتماد ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ۔
محمد باقرالصدر ،النجف الاشرف
مارکسیت کے ساتھ
WITH MARXISM
نظریۂ مادیت تاریخ:
1۔تمہید
2۔نظریہ، فلسفہ کی روشنی میں
3۔نظریہ،اجمالی رنگ میں
4۔نظریہ، تفصیلی تبصرہ کے ساتھ
مارکسی مذاہب
1۔اشتراکیت
2۔اشتمالیت
نظریۂ مادیت تاریخ
تمہید
جب ہم مارکسیت کے اقتصادی نظام کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تویہ بالکل غیر ممکن ہے کہ اس کے اقتصادی نظام یعنی اشتراکیت واشتمالیت کو اس کے نظری اقتصاد(جس کی روح رواں تاریخی مادیت ہے)سے الگ کردیں اس لئے کہ یہی مادیت وہ اہم اصول ہے جس کے تحت پورا کاروانِ تاریخ چل رہاہے اور اسی کے قواعدوہ محکم قواعد ہیں جو تاریخ بشریت کے ہردور کے لئے ایک حتمی نظام تشکیل دے رہے ہیں۔
مارکسیت اور تاریخی مادیت کاگہراارتباط ہی ہے جو اس کے بارے میں کوئی موافق یا مخالف فیصلہ دینے سے اس وقت تک مانع رہے گا جب تک کہ اس مادیت کی صحیح تحلیل نہ ہوجائے اس لئے کہ تحقیقی اعتبار سے مارکسیت اس مادیت کے قہری نتیجہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
مادیت تاریخ اپنے امتحان میں کامیاب ہوگئی اور اس نے یہ ثابت کردیاکہ تاریخ کے جملہ انقلابات اسی کے ممنون کرم ہیں تو ہر اس مذہب کو قبول کرلینا پڑے گا جو اس مادیت کا نتیجہ ہوں اور ہر اس نظام کو ترک کر دینا پڑے گا جو اس بات کا مدعی ہوکہ ہمارے اجتماعی
اصول ہمارے سیاسی قوانین اور ہمارے اقتصادی قواعد تاریخ کے ہر دور کے لئے کافی ہیں۔ جیسا کہ نظام اسلامی کادعویٰ ہے کہ وہ چودہ صدیوں کے تغیرات وانقلابات کے باوجود آج بھی انسانیت کے مشکلات کو حل کرسکتاہے۔
اسی مادیت کی روشنی میں انگلز نے یہ دعویٰ کیاتھاکہ:
انسان جن حالات میں پیدا ہوتاہے وہ ہر قطر زمین کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ ایک ہی گوشہ میں نسلوں کے تغیر وتبدل سے بدل جاتے ہیں۔ بنابریں مختلف اطراف وادوار کے لئے ایک ہی اقتصادی نظام کا کافی ہونا غیر ممکن ہے۔ (صنددوہرنگ،ج2،ص5)
لیکن اگرتاریخی مادیت اپنے علمی جائزہ میں کامیاب نہ ہوسکی اور اس نے یہ ثابت نہ کیا کہ اس کے قوانین ابدی اور حتمی حیثیت رکھتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگاکہ مارکسیت کی عمارت منہدم ہوجائے اور وہ مذہب برسرکارآجائے جو تاریخی تغیرات سے اپنے اندر کوئی ضعف محسوس نہیںکرتااور اپنی وسعت وہمہ گیری کو ہر دور کے لئے کافی تصور کرتاہے۔
مقصد یہ ہے کہ اقتصادیات کے موضوع پر بحث کرنا اور مارکسیت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ دینا اس وقت تک ناممکن ہے ۔جب تک کہ تاریخی مادیت کا صحیح تجزیہ نہ کرلیا جائے اس لئے اب ہم اسی مادیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ مارکسیت کی بنیادوں کی کمزوری کا اندازہ لگایاجاسکے اور اس کے بارے میں آسانی سے فیصلہ دیاجاسکے۔
مارکسیت کے بارے میں ہمارے بحث کے دو حصہ ہیں:
(1) مارکسیت نظری اقتصاد کی روشنی میں
(2) مارکسیت عملی میدان میں
یگانہ محرک تاریخ
تاریخی مادیت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری تاریخ کو ایک ہی محرک کی تاثیر کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔اس کا خیال ہے کہ اس نے عالم غیب سے ایک ایسے راز کا پتہ لگا لیاہے جس سے تمام تاریخی مشکلات کا حل مل سکتاہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس نے یہ کوئی نئی بات نہیں کہی بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے مفکرین گزرے ہیں جو تاریخ کو کسی ایک ہی عامل کی تحریک کا نتیجہ قرار دیتے رہے ہیں۔
چنانچہ انہیں مفکرین میں سے بعض نظریۂ جنس کے قائل تھے اور ان کا خیال تھاکہ معاشرہ کی تبدیلی وترقی کا راز جنس کے اندر مخفی قوتوں میں مضمر ہے۔اسی جنس سے تاریخی ادوارتشکیل پاتے ہیں اور اسی سے انسان کی عضوی ونفسی ترکیب کا عمل انجام پاتاہے،گویاکہ پوری تاریخ اس جنسی جہاد کا نتیجہ ہے جس میں قوی اجناس کو فتح اور ضعیف جنس کو شکست دواماندگی نصیب ہوتی ہے۔
بعض دوسرے مفکرین نے''تاریخ تغیرات''کا سرچشمہ جغرافیائی حالات کو قرار دیاہے۔ان کا خیال تھاکہ تاریخ کے تمام تغیرات کا منشاء طبیعی جغرافیہ ہے اس لئے کہ اسی کے تغیر سے راحت وآسائش کے اسباب میں تغیر ہوتاہے اسی سے معاشرہ آگے بڑھتاہے اور اسی کی بے رخی سے انحطاط کی منزلوں میں جاگرتاہے گویا جغرافیہ ہی پوری تاریخ کو اپنے اشاروں پر چلارہاہے۔
علماء نفسیات کا خیال یہ ہے کہ تاریخ میں تغیر کا سلسلہ انسان کے شعوری یالاشعوری جذبات واحساسات سے شروع ہوتاہے۔انہیں احساسات کے مختلف حالات سے تاریخ کے مختلف ادوار وجود میں آتے ہیں۔
مادیت تاریخ بھی انہیں''یگانہ''محرک تاریخ کے نظریات میں سے ایک نظریہ ہے جس کی بشارت کارل مارکس نے دی ہے جس کے متعلق اس کا خیال ہے کہ اقتصادیات ہی وہ بنیادی محرک ہیں جن کی بناپر تاریخ کے تمام تغیرات رونما ہوتے ہیں۔انہیں سے انسان کے جذبات واحساسات پیداہوتے ہیں اور یہی اس کے افکار تشکیل دیتے ہیں۔اس کے علاوہ تمام عوامل وموثرات ثانوی درجہ رکھتے ہیں جو خود بھی بنیادی محرک کے تغیر کے ساتھ متغیر ہوتے رہتے ہیں۔
ہمارا خیال ہے کہ یہ تمام ہی نظریات وافکار وہ ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ انہیں اسلام ہی قبول کرتاہے اس لئے کہ یہ تمام نظریات کسی ایک عامل ومحرک کو اتنی طاقت دینا چاہتے ہیں جو قطعاً اس کے لئے مناسب نہیں ہے۔لیکن اس وقت ہماراروئے سخن صرف مادیت تاریخ کی طرف ہے ۔ہم اسی سے بحث کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔باقی نظریات کی بنیادیوں بھی ختم ہوجائے گی کہ ہم آخر کلام میں ''محرک یگانہ''کے نظریہ ہی کو باطل ومہمل ثابت کر دیں گے۔
اقتصادی محرک یا تاریخی مادیت
مارکس نے ہمارے سامنے تاریخی تغیرات کاجو فلسفہ پیش کیاہے اس میں اقتصادی محرک کو پوری تاریخ کی قیادت سپرد کی گئی ہے۔اس کا خیال یہہے کہ معاشرہ کے دینی، اجتماعی، سیاسی اور اخلاقی اقدار کا سرچشمہ اس کا اقتصادی توازن ہے۔اسی اقتصاد سے اس کے مستقبل کا تعین ہوتاہے اور اس سے اس کے حال کی توجیہ وتفسیر کا کام بھی لیاجاتاہے۔
یہ اور بات ہے کہ دنیا کی دیگر اشیاء کی طرح اقتصاد کی بھی ایک علت ہے جو واقعاً قافلۂ تاریخ کی قیادت کی حامل ہے اور اس کا نام ہے''وسائل پیداوار''در حقیقت یہی وسائل وہ ہیں جو تاریخ کے جملہ تغیرات،انقلابات اور ادوار ے موجود ہواکرتے ہیں۔اس مقام پر فطری طور پر دو سوال اٹھے ہیں۔
اول یہ کہ وسائل پیداوار سے مراد کیاہے؟
اور دوسرے یہ کہ ان وسائل کو تاریخ حرکات وتغیرات سے کیاربط ہے اور یہ اجتماعی زندگی پر کیونکر اثراندازہوتے ہیں۔
مارکس نے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہاہے کہ وسائل پیداوار ان آلات کا نام ہے جن کی مدد سے انسان طبیعی اشیاء کو حاصل کرتاہے۔چونکہ انسان اس دنیا میں جینے کے لئے طبیعت سے استفادہ کرنے کا محتاج ہے اور طبیعت سہولت سے اپنے برکات پیش کرنے پرآمادہ نہیں ہے لہٰذا جن آلات کے ذریعہ اس سرکشی کا مقابلہ کیاجاسکے اور جن کی طاقت سے طبیعی مواد سے استفادہ کیاجاسکے۔انہیں وسائل پیداوار کانام دیا جائے گا۔
سب سے پہلے ان وسائل کا ظہور ہاتھوں کی شکل میں ہواجب انسان دستکاری کرکے اپناپیٹ پالتاتھا۔اس کے بعد پتھر کے ٹکڑوں نے اس کی جگہ لی جن سے قطع وبرید کا کام لیاگیا۔آگے چل کر اس میں دستہ لگاکر ہتھوڑابنالیاگیا یعنی پیداوار کے ساتھ پیداوار کے وسائل بنائے گئے۔پھر مزید ترقی تیروکمان ،نیزہ وشمشیر وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوئی اور پھر انسانیت کی ترقی بظاہر رینگنے لگی۔یہاں تک کہ آخری دنوں میں بخاروبرق وذرات کے آلات کاپتہ لگالیاگیاجن پر آج کی ترقی کادارومدار ہے اور جن سے تاریخ کاموجودہ دور قائم ہے۔
دوسرے سوال کے جواب میں مارکسیت نے یہ بیان دیاہے کہ وسائل پیداوار ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پیداوار بھی بدلتی جائے۔ظاہر ہے
کہ صیادکے ہاتھوں کی پیداوار اور ہوگی اور کاشتکار کے ہاتھوں کی پیداوار اور۔پھر طبیعت سے مقابلہ کرنے کے لئے انسان تن تنہا قیام بھی نہیں کرسکتابلکہ اپنے ابناء نوع کا محتاج ہے۔
اس لئے پیداوار کے بدلنے سے اجتماع کا رنگ بدل جانابھی ناگزیر ہے۔جو شخص اس کام میں جس قدر حصہ لے گا اسی قدر اس کی ملکیت تصور کی جائے گی۔ملکیت کے حدود کام کی نوعیت ہی سے مقرر کئے جاتے ہیں چاہے ان حدود کی شکل غلامی کی ہویا مساوات کی،جاگیرداری کی ہویاسرمایہ داری کی،اشتراکیت کی ہو یا اشتمالیت کی۔
مارکس کی نظرمیں انسان کے تمام سیاسی،دینی ،فکری اور اخلاقی تعلقات کی بنیاد انہیں پیداواری تعلقات سے وابستہ ہے۔انہیںتعلقات سے ملکیت کی تحدید ہوتی ہے اور اسی ملکیت سے تقسیم ثروت ہی سے یہ تمام تعلقات قائم ہیں۔
اس مقام پر ایک سوال یہ پیداہوتاہے کہ اگر تاریخ کے جملہ تغیرات ملکیتی تعلقات کے اختلاف سے وابستہ ہیں تو خودان ملکیتوں کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟مارکس نے اس سوال کا جواب یہ دیاہے کہ یہ اختلاف ایک قہری اور لازمی شیء ہے۔جیسے جیسے وسائل پیداوار ترقی کرتے جائیں گے اسی اعتبار سے ملکیت کے حدود بھی بدلتے جائیں گے اور ملکیت کے تغیر کے ساتھ تاریخی انقلابات لازمی حیثیت رکھتے ہیں۔
ان وسائل کی ترقی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگاکہ تازہ ترین وسائل ایک جدید نظام معیشت کے طالب ہوں گے جو موجودہ نظام سے مختلف ہو اور اس طرح موجودہ نظام اور مناسب نظام میں ٹکراؤ ہوگا جس کے نتیجہ میں تیسرا نظام بروئے کارآئے گا اور ساتھ ہی ساتھ طبقاتی نظام کی بھی بنیاد پڑجائے گی۔مطمئن طبقہ موجودہ نظام کا ہم آہنگ ہوگا اور پامال شدہ طبقہ آئندہ نظام کادمساز۔
چنانچہ آج کی دنیا میں مزدور اور سرمایہ دار کی جنگ کا تمام تردارومدار اسی طبقاتی نزاع پر ہے۔سرمایہ دار کی منشاء ہے کہ سابق نظام معیشت باقی رہے تاکہ اس کو منافع سے
باقاعدہ استفادہ کا موقع مل سکے اور مزدور کی آرزوہے کہ جدید وسائل کے ساتھ ایک جدید نظام تشکیل پائے جس میں اس کے حقوق کی صحیح رعایت کی گئی ہو۔
اس تجزیہ کا حاصل یہ ہے کہ تاریخ کے تمام ادوار میں دو قسم کے نزاعوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے ۔ایک نزاع قدیم وجدید وسائل پیدا وار میں اور ایک اسی کے زیر اثر قدیم وجدید طبقات میں۔
اب چونکہ پیداوار کے وسائل ہی کی قوت پرپوری تاریخ گردش کرہی ہے لہٰذا ہر میدان میں اس کی فتح لازمی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ عالمی حالات کا تغیر وتبدل ناگزیر ہے۔
علم الاجتماع کی اصطلاح میں اسے یوں بیان کیاجاسکتاہے کہ وسائل معیشت کا حامی طبقہ فاتح قرار پاتاہے اور سابقہ تعلقات کا دلدادہ طبقہ شکست خوردہ ۔
اور ظاہر ہے کہ جب وسائل کی فتح ہوتی ہے تو اس کے نتیجہ میں اقتصادی حالات ترقی کرتے ہیں اور جب اقتصادی حالات ترقی کرتے ہیں تو اس کے زیر اثرپوری تاریخ بدل جاتی ہے اس لئے کہ سب کی بنیاد انہیں اقتصادیات پر قائم تھی۔
یادرہے کہ یہ سلسلہ اسی فتح وشکست پر تمام نہیں ہوتابلکہ یہ وسائل پھر بھی روبہ ترقی کرتے ہیں اور ان کے آگے بڑھ جانے سے نظام کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں اور اس طرح پھر ایک نئی جنگ قائم ہوجاتی ہے جو خود بھی کسی دوسری جنگ کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور اسی طبقاتی حرب وضرب اور طبیعاتی جنگ وجدل کا نام جدلیت یا دیا لکٹیک ہے جس پر مادیت تاریخ کی بنیادیں قائم ہیں۔
تاریخی مادیت اور واقعیت
بعض مارکسی نظریہ کے حضرات کا خیال ہے کہ تاریخ کے جملہ حرکات کا علم صرف اسی مادیت سے حاصل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس علم کاکوئی دوسرا وسیلہ و ذریعہ نہیں ہے۔چنانچہ بعض فریفتگان مارکسیت نے اس مادیت کے منکرین کو دشمن تاریخ اور عدو حقیقت کے القاب سے سرفراز فرمایا ہے اور اس سرفرازی کا سبب یہ قرار دیا ہے کہ مادیت کی بنیا ددو باتوں پر ہے ۔ اعتراف حقیقت اور اقرار قانون علت ومعلول اور ظاہر ہے کہ دونوں ہی باتیں واضحات میں سے ہیں۔ لہٰذا مادیت کا انکار یا تو مثالیت کی دمسازی کا نتیجہ ہوگا یا علت و معلول کے قوانین سے انحراف ہوگا اور یہ باتیں تاریخ وحقیقت کی واقعی دشمنی کا نتیجہ ہیں۔
بعض مارکسیت کے پرستار افراد کا خیال ہے کہ یہ علم تاریخ کے دشمنوں کا طریقہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کے ادراک کے سلسلے میں واقع ہونے والے اختلافات کو اس کی بے بنیادی کی دلیل قرار دیتے ہیں اور یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جب کل کے حوادث کا صحیح ادراک نہیں ہو پاتا تو صدیوں قبل کے واقعات کے متعلق ادراک کا دعویٰ کیا قیمت رکھتا ہے۔''
(الثقافة الجدیدہ سال ہفتم ،عدد11،ص10)
اس مقالہ نگار کی کوشش یہ ہے کہ تاریخی مادیت کو اصل تاریخ و حقیقت سے اس طرح متحد کر دے کہ ایک کا انکار خود بخود دوسرے کے انکار کے مرادف ہو جائے اور اس طرح اصل حقیقت کا واسطہ دے کر اپنی مادیت کا اقرار کرالے لیکن اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ مادیت کا منکر حقیقت تاریخ کا منکر نہیں ہے بلکہ اس میں شک کر رہا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ علمائے مارکسیت نے اس قسم کے مغالطات اکثر مقامات پر
استعمال کئے ہیں اور ان کے فریب سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی مکمل کوشش کی ہے ۔ فلسفی میدان میں عالم کے مادی مفہوم کے منوانے کے لئے بھی ان لوگوں نے یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مثالیت کے مقابلہ میں واقعیت کوئی چیز ہے تو عالم بھی کل کا کل مادی ہے۔
ہم نے اپنی فلسفہ کی کتاب میں اس مطلب کو پوری طرح واضح کر دیا کہ یہ ایک کھلا ہوا مغالطہ ہے جس میں سادہ لوح افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے ۔ اس لئے کہ اگر ہمارے سامنے صرف دو ہی صورتیں ہوتیں کہ ہم یا تو حقیقت ہی کے منکر ہو جاتے اور مثالیت کے فلسفہ کو اپنا لیتے یا پھر مادیت کے فریفتہ ہو جاتے تو یہ بات بڑی حد تک معقول ہوتی ۔لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے اور بھی راستے موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے اس مفہوم کا قبول کر لینا ایک بے جا اقدام کی حیثیت رکھتا ہے ۔آپ خود ملاحظہ کر لیں کہ مثالیت کے مخالفین جو حقیقت واقعہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ بھی عالم کے مادی مفہوم پر متفق نہیں ہیں جس طرح کہ اس مقام پر حقیقت تاریخ کے ماننے والے سب ایک بات کے قائل نہیں ہیں بلکہ کوئی جنس کو محرک تاریخ قرار دیتا ہے اور کوئی اخلاق ونفسیات کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کا ایمان اور ہے اور مادیت کا اعتراف اور۔پہلا مسئلہ تمام مثالیت کے مخالفین کی نظر میں مسلم ہے۔لیکن دوسرا مسئلہ ان کی نظر میں بھی محل اختلاف ہے۔
رہ گیا استدلال کا یہ جزء کہ عالم قانون علت ومعلول کا تابع ہے تو حقیقتاً اسے اصل مطلب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ۔ اس پر تو ہر صاحب عقل وشعور ایمان لائے ہوئے ہے۔ اصل نزاع تو یہ ہے وہ علت کیا ہے اور وہ محرک کون ہے جس کے اشاروں پر قافلہ تاریخ سیر کر رہا ہے۔
اس اجمال کے بعد ہم مادیت تاریخ پر ایک تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں جس کے تین حصے ہوں گے:
1۔ مادیت ؛فلسفہ اور منطق کی روشنی میں
2۔ مادیت؛ایک عام نظریہ کی حیثیت سے
3۔ مادیت؛کا انطباق تاریخ کے ادوار پر
مادیت تاریخ (فلسفہ مادی کی روشنی میں)
مارکسیت کا خیال ہے کہ تاریخ کی مادی تفسیر عالم کے مادی مفہوم کی ایک فرع ہے اس لئے کہ تاریخ عالم کے حوادث کا ایک جزء ہے اور جب سارا عالم مادی فرض کر لیا جائے گا تو تاریخ کا مادی ہونا ایک قہری اور لازمی شے ہوگا۔چنانچہ اس نے اسی بنیاد پر اٹھارہویں صدی کی مادیت پر سخت تنقید کی ہے کہ ان مادیت پرستوں نے اپنے بعض روحانی افکار اور اخلاقی اقدار پر ایمان کی وجہ سے انہیں بھی تاریخ کے محرکات میں شمار کر لیا ہے اور یہ بات مارکسیت کی نظر میں مادیت پرست شخص کے لئے انتہائی افسوس ناک ہے۔
چنانچہ انگلزنے اسی سطحیت پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ :
ہم میدان تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ قدیم مادیت آپ اپنی مخالفت کر رہی ہے ، وہ مثالی قوتوں کو تاریخ کی محرک مانتی ہے اور حقیقی عوامل ومحرکات کی تلاش نہیں کرتی۔نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسے ایک عجیب تضاد سے دوچار ہونا پڑا ہے ۔ نہ صرف اس لئے کہ وہ مثالی قوتوں کو تسلیم کر تی تھی بلکہ اس لئے کہ وہ عالم کو مادی بھی جانتی تھی ۔'' (تاریخ کی اشتراکی تفسیر ،ص57)
میں اس وقت عالم کے مادی مفہوم کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس موضوع پر سیر حاصل تبصرہ میں نے اس سلسلہ کی پہلی کتاب یعنی ''ہمارا فلسفہ'' میں کر دیا ہے
اس وقت تو اس ارتباط سے بحث کرنا ہے جو عالم کے مادی ہونے اور تاریخ کے مادی ہونے میں قائم کیا گیاہے اور جس کی بنیاد پر اٹھارہویں صدی کی مادیت مورد الزام قرار پائی ہے۔
اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مارکسیت کی نظر میں عالمی مادیت اور تاریخی مادیت کے مفاہیم میں بڑا فرق ہے اور شاید اسی فرق کے ادراک نہ کر سکنے کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے پرستاروں نے دونوں کو لازم و ملزوم قرار دے کر ایک کے ساتھ دوسرے کا اقرار بھی ضروری بنا دیا۔
حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ مارکسیت کی نظر میں عالم کے مادی ہونے کا مفہوم صرف یہ ہے کہ عالم کے جملہ حوادث و کیفیات اسی ایک مادہ کے تلون وتنوع کا نتیجہ ہیں۔ اس کے علاوہ مجرد افکار وغیر مادی مشاعر (ادراکات) کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فکر کو کسی قدر بلند کیوں نہ فرض کر لیا جائے اس کی حیثیت ایک دماغی نشاط سے زیادہ نہ ہوگی۔
ظاہر ہے کہ اس مادیت کے اعتبار سے تمام عالم کو مادی ہونا چاہئے ۔ چاہے وہ وسائل پیداوار سے آگے بڑھے اور چاہے وسائل پیداوار اس کے دست وبازو کی قوت سے ترقی کریں ۔ بس دونوں مادی ہیں اور مادی رہیں گے۔ایسی صورت میں اس نظریہ کی بناء پر تاریخ کی ابتدائی کڑی وسائل کو قرار دینا اور انسان کے سر سے اس تاج کرامت کا سلب کر لینا ایک زبردستی کے سواکچھ نہیں ہے۔
اس کے بر خلاف تاریخی مادیت کا تمام ترتقاضہ یہ ہے کہ سیر تاریخ کی ابتدا ء وسائل پیداوار سے ہو، انہیں کو اولیت کا شرف دیا جائے اور انہیں کو محرک تاریخ کے زریں لقب سے یاد کیا جائے ۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں میں دور کا بھی رابطہ نہیں ہے چہ جائیکہ ایک کو دوسرے کا لازمی اثر قرار دیا جائے۔
قوانین جدلیت کی روشنی میں
قوانین جدلیت وہ قوانین ہیں جو عالم کے ہر تغیر وانقلاب کی توجیہ اس کے باطنی تنازع کی بنا پر کرتے ہیں۔
ان قوانین کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ہر شے اپنے اندر اپنے مخالف جراثیم بھی رکھتی ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک دن موجودہ شکل سے بر سر پیکار ہو جاتے ہیں اور اس نزاع کے نتیجہ میں ایک نئی مثال ظہور میں آتی ہے جو پہلی صورت سے اجنبی اور اس سے ترقی یافتہ ہوتی ہے۔
مارکسیت کا خیال ہے کہ تاریخ کے جملہ تغیرات کی تفسیر بھی انہیں قوانین کی روشنی میں کی جائے اور یہ اعتراف کیا جائے کہ تاریخی ادوار ، طبقاتی نزاع سے تشکیل پاتے ہیں ہر موجودہ طبقہ اپنے اندر مخالف جراثیم رکھتا ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک کیفیتی تغیر پیدا کر دیتے ہیں اور تاریخ ایک نئے موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مقام پر ایک لمحہ ٹھہر کر یہ دیکھ لیں کہ آیا مارکسیت تاریخ پر ان قوانین کے انطباق میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں۔
بظاہر ایسا معلوم ہوا ہے کہ اس نے ابتدائی منزلوں میں ان قوانین کو منطبق کرنے میں کسی حد تک کامیابی ضرور حاصل کی تھی لیکن نتیجہ تک پہنچتے پہنچتے اپنے ان قوانین کو بالکل فراموش کر بیٹھی بلکہ انہیں سے بر سر پیکار ہو گئی ۔جس کی تفصیل یہ ہے :
طریقۂ جدلیت
مارکسیت نے اس طریقہ کو فقط تاریخ کے تجزیہ میں نہیں اپنایا بلکہ اس نے عالم کے
ہر حادثہ کی تحلیل اسی طریقہ کی بنیاد پر کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک عجیب تضاد اور کشمکش میں مبتلا ہو گئی ہے۔
اسے ایک طرف قانون جدلیت کی بناء پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کا ہر انقلاب داخلی نزاع کی بناء پر ہوتا ہے اور دوسری طرف قانون علت ومعلول کے ایمان کی بناء پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان حوادث کی ایک خارجی علت بھی ہے جن سے یہ وجود میں آتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ کشمکش اس کے ساتھ لگ کر دامن تاریخ تک چلی آئی ہے وہ جہاں تاریخ کے ہر حادثہ کو طبقاتی نزاع کا نتیجہ بناناچاہتی ہے وہاں ان سب کی ایک علت ''وسائل پیداوار'' پر بھی ایمان لانا چاہتی ہے تاکہ اس کے علاوہ تمام اسباب ثانوی حیثیت اختیار کر لیں۔
مزید یہ کہ تاریخ کا محرک در حقیقت طبقاتی اختلاف نہیں ہے بلکہ قدیم ملکیت کا نظام اور جدید وسائل پیداوار کا اختلاف ہے کہ جسے طبقاتی نزاع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
مارکسیت نے اپنے دہرے ایمان میں جب اس کشمکش کا صحیح احساس کر لیا تو اس کا یہ حل نکالا کہ علت ومعلول کے فلسفی مفہوم سے انکار کرکے اسے بھی جدلیت کا رنگ دے دیا جائے۔ فلسفی اعتبار سے علت معلول سے جدا شے ہوتی تھی ۔ اس کی صلاحیتیں معلول سے زیادہ ہوا کرتی تھیں لیکن جدلیت کی بناء پر یہ سارا نظام بدل گیا ہے ۔ یہاں معلول علت کے شکم سے بر آمد ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتیں علت سے زیادہ ہوتی ہیں اور اسی لئے وہ اس سے ٹکرا کر نئے نظام کو تشکیل دیتا ہے۔
یہاں علت کو اثبات معلول کو نفی اور نتیجہ کو نفی نفی کہا جاتا ہے۔یہی طریقہ مارکسیت نے تاریخ کی تشریح میں بھی استعمال کیا ہے اور جملہ حوادث کو ایک شے کا نتیجہ قرار دیا ہے جو اس سے بطریقۂ جدلیت ظہور میں آئے ہیں۔
ہم مارکسیت کی اس تشریح کو بسر وچشم قبول کر لیتے اور ہمیں یہ باور ہو جاتا کہ سارا کاروان تاریخ جدلی اصولوں پر چل رہا ہے اور پوری تاریخ داخلی نزاعات سے بدلتی جا رہی
ہے لیکن افسوس کہ خود مارکسی قلمکاروں نے ہمارا ساتھ نہ دیا اور آخرکار یہ اعتراف کر لیا کہ مارکسیت کا یہ نظریہ ہمہ گیر نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ نقائص ضرور ہیں چنانچہ انگلزبیان کرتا ہے:
قدیمی معاشروں کے لئے یہ بات ممکن تھی کہ وہ ہزاروں برس تک زندہ و قائم رہتے جیسا کہ ہندو وغیرہ اس وقت تک باقی رہے جب تک کہ ان لوگوں نے خارجی دنیا سے تعلقات قائم نہیں کئے ، اس کے بعد خارجی معاملات سے ان میں مساوات کا خاتمہ ہو گیا اور طبقاتی اختلاف پیدا ہو گیا۔''
(ضددوہرنگ ،2،ص8)
تاریخی جدلیت کی کمزوری
بات کے یہاں تک پہنچ جانے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس جدلیت کے بارے میں ہم اپنی رائے بھی ظاہر کر دیں ۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ طریقہ نہ تو فلسفہ کے میدان میں کامیاب ہو سکا ہے اور نہ تاریخ کے میدان میں۔
فلسفی بحث کے تفصیلات ہماری پہلی کتاب میں موجود ہیں۔ تاریخ کے سلسلہ میں ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ جہاں مارکس نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ تاریخ کی صحیح توجیہ اپنے جدلی قوانین کی بناء پر نہیں کر سکا۔ وہاں وہ سرمایہ داری سے اشتراکیت کی طرف رخ بدلنے کی توجیہ ان الفاظ میں کرتا ہے:
''سرمایہ دارانہ پیداوار سے جو سرمایہ دارانہ ملکیت پیدا ہوئی تھی وہ درحقیقت دستکاری کے اعمال کے نتائج کی نفی تھی ۔ پھر اس سرمایہ داری نے خود
اپنی نفی کی بنیاد ڈالی۔اس لئے کہ نظام کائنات اسی طریقہ پر چل رہا ہے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شخصی ملکیت پلٹ آئی لیکن پہلی شکل میں نہیں بلکہ اس انداز سے کہ پیداوار میں ایک باہمی اشتراک وتعاون تھا اور تمام وسائل پیداوار مع زمین کے مشترک تھے ۔'' (راس المال،ج3،ق2،ص128)
آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مارکس نے کاریگری کو علت اور سرمایہ داری کو معلول قرار دے کر اپنی نظر میں طریقۂ جدلیت کو استدلالی رنگ دے دیا ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقۂ استدلال ذہنی تاریخ کے لئے تو بھلا معلوم ہوتا ہے لیکن واقعی تاریخ کے اعتبار سے بڑا افسوسناک ہے ۔ کوئی مارکس سے یہ پوچھے کہ کاریگری نے کب علت کے فرائض انجام دئیے تھے اور سرمایہ داری کب اس سے پیدا ہوئی ہے ۔ کیا صرف ایک طریقہ کا دوسرے کی جگہ پر آ جانا علت ومعلول ہونے کے لئے کافی ہے چاہے اس کے اسباب وعلل کچھ ہی کیوں نہ ہوں؟
حقیقت امر یہ ہے کہ تاجروں نے اپنے سرمایہ کی فراوانی کی بنا پر اس قسم کی پیدوار کا کام شروع کیا ۔ کاریگروں نے اپنے تحفظ کے لئے ان کا مقابلہ کیا لیکن سرمایہ کی طاقت سے مجبور ہو گئے۔ان لوگوں نے بازاروں پر قبضہ کر لیا۔ان غریبوں کے وسائل سلب کر لئے اور اس طرح سرمایہ داری وجود میں آ گئی۔
واضح الفاظ میں یہ کہا جائے کہ تجارت کا فروغ ، زمینوں کی لوٹ مار ، معاون کا ظہور یہ سب وہ اسباب تھے جن کی بنا پر کاریگری کی جگہ سرمایہ دارانہ پیداوار کو مل گئی ۔ کاریگری کو اس نظام کی علت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس میں ایسی کوئی طاقت تھی ۔ یہ تمام کام خارجی طاقت کی بنا پر انجام پاتے ہیں۔
مقصد یہ ہے کہ ہم نے اب تک فلسفہ میں کوئی ایسی مثال دیکھی ہے جہاں مارکس کا یہ قانون منطبق ہوتا ہو اور نہ تاریخ میں کوئی ایسا حادثہ دیکھا ہے جس کی صحیح توجیہ اس قانون
کی بنا پر کی جا سکے۔جیسا کہ آئندہ ہم اس مطلب کی مزید وضاحت کریں گے۔
دلیل ونتیجہ کا تضاد
مارکسیت کے لئے سب سے اہم حادثہ پیش آیا کہ اس نے جدلیت کو جس مقصد کے لئے اپنایا تھا وہ حاصل نہ ہو سکا۔بلکہ آخری منزل تک پہنچتے پہنچتے نتیجہ اصل جدلیت سے بالکل متضاد ہوگیا۔اس کا خیال تھا کہ تاریخ کا واحد محرک قانون جدلیت ہے جو طبقاتی نزاع کی بنیاد پر قافلۂ تاریخ کو تا ابد رواں دواں رکھے گا لیکن اس نے اسی کے ساتھ یہ بشارت بھی دے دی کہ عنقریب ایک ایسا دورآنے والا ہے جب یہ طبقاتی نزاع ختم ہو جائے گا اور عالم یک رنگ ہو کر زندگی بسر کرے گا مزدور کی فتح ہوگی اور سرمایہ داری کی شکست ، اشتراکیت اور اشتمالیت کی زندگی ہوگی اور پھر چین ہی چین۔
یہ بشارت سنتے ہی انسان چونک پڑا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر قانون جدلیت کا کیا حشر ہوگا۔یہ شعلۂ جوالہ کیونکر خاموش ہو جائے گا؟ یہ رواں دواں قافلہ کیوں کر تھک کر موت کی نیند سو جائے گا؟ اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوگا تو پھر اشتراکیت ایک اثبات ہوگی تو اس کی نفی کیا ہوگی اور ان دونوں کے باہمی تنازع سے کون سا نظام وجود میں آئے گا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کی بنا پر اشتراکیت سر بگریباں ہے اور مارکسیت متحیر۔آخر ان بنیادی سوالات کا کیا جواب دیا جائے گا۔
مادیت تاریخ کی روشنی میں
اب ہم تاریخی مادیت کو خود اسی کی روشنی میں لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسکے اصول و قوانین میں کتنا زور اور کتنا استحکام ہے۔
ظاہر ہے کہ ابتدائے امر میں آپ کو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوگی لیکن ہمیں یقین ہے کہ نتیجہ پر پہنچ کر آپ کا یہ تعجب دور ہو جائے گا۔ چونکہ مارکسیت کا خیال یہ ہے کہ تاریخی مادیت دنیا کے تمام علوم وافکار کا تجزیہ کرتی ہے۔ وہ انسانی معرفت کے پیدا ہونے کا صحیح سبب بیان کرتی ہے اور پھر اسی قانون کی روشنی میں اس نے فیصلہ دیا ہے کہ عالم کے جملہ حوادث کی آخری علت دنیا کی اقتصادی حالت ہے۔ جیسے جیسے اقتصادی حالات ترقی کرتے جائیں گے انسان کے علوم ومعارف میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
علوم درحقیقت اقتصادی حالات کا ذہنی انعکاس ہیں جو معاشرہ کے بدلنے سے بدلتے رہتے ہیں۔
مارکسیت نے تمام حقائق کے بارے میں نسبیت کا عقیدہ اسی تاریخی مادیت کی روشنی میں اختیار کیا ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ جب ہر عقیدہ اپنے حالات کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی قدر وقیمت بھی اسی وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ حالات باقی رہیں گے پھر اس کے بعد اس فکر ونظر کی کوئی وقعت نہیں رہ جائے گی۔اس کی نظر میں دنیا میں کوئی فکر ایسی نہیں ہے جوتاریخ کے ہر دور میں باوزن وقیمت اور باحیثیت واہمیت ہو۔
ہم مارکسیت کے نظریہ کو بھی تسلیم کر لیتے مگر افسوس کہ وہ اپنے اس نظریہ کو ''تاریخی مادیت ''پر منطبق کرنے پر تیار نہیں ہے وہ اسے ایک مطلق حقیقت کا درجہ دے کر یہ خیال کرتی ہے کہ اس کی قدر وقیمت ہمیشہ ہر ماحول میں باقی رہے گی۔
ضرورت اس بات کی تھی کہ مارکسیت خود ہی یہ سوال اٹھاتی کہ یہ نظریہ کیونکر پیدا ہوا؟اور اس میں یہ دوام وثبات کہاں سے آ گیا ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ سوال اس کے دماغ میں پیدا ہو جاتا تو وہ خود بھی اس بات کی قائل ہو جاتی کہ یہ نظریہ ایک خاص ماحول کی پیداوار تھا جو اس ماحول کے ساتھ بے قدر وقیمت ہو گیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ مادیت تاریخ نے خود ہی اپنے گھر کو آگ لگا دی۔اس نے ایک طرف تمام نظر یات وافکار کو وقتی اور ایک خاص معاشرہ کی پیداوار قرار دیا اور دوسری طرف اپنے اندر ابدی طاقت محسوس کر لی جو اسے قیام تاریخ تک قائم رکھ سکے۔
ہم اگر چہ اقتصادی حالات کونظریات وافکار کی تشکیل کا واحد سبب تسلیم نہیں کرتے لیکن ہمیں اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ خارجی حالات کو انسان کے افکار میں یک گونہ دخل ضرور ہوتا ہے ۔ ہم اس کی مثال کارل مارکس ہی کے کلام سے پیش کئے دیتے ہیں۔
مارکس کا کہنا ہے کہ'' سرمایہ دار نظام کا ختم کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان ایک انقلابی جنگ نہ ہو۔''
مارکس نے اپنے اس بیان میں انقلاب کو تغیر تاریخ کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے اور اس کے پرستاروں نے بلا چون وچرا اسی حقیقت کو تسلیم بھی کر لیا ہے ۔ ان لوگوںنے اس بات کی طرف توجہ کی زحمت بھی نہیں کی کہ مارکس کی یہ فکر چند خاص حالات کا نتیجہ تھی اور اب یہ حالات بدل چکے ہیں۔
مارکس نے انیسویں صدی کے سرمایہ دارانہ نظام میں آنکھیں کھولیں جہاں ایک طرف سرمایہ اور تعیش کی فراوانی تھی اوردوسری طرف فقر وفاقہ کا تسلط۔سیاسی حالات انتہائی
تنگ و تاریک تھے ۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ایک انقلابی تصور کا ذہن میں پیدا ہو جانا ناگریز تھا ۔ لیکن مارکس کے مرنے کے بعد اب وہ حالات بدل چکے ہیں۔اب نہ عیش و عشرت کی فراوانی ہے اور نہ فقر وفاقہ کی ارزانی ۔ اب تو سیاسی تجربات یہ بات صاف طور پر واضح کر چکے ہیں کہ فقیر طبقہ کے لئے زندگی کے وسائل مہیا کر دینا ہی اصلاح مملکت کے لئے کافی ہے۔ نہ کسی خونی انقلاب کی ضرورت ہے اورنہ کسی طوفانی جنگ کی۔
بظاہر یہی وجہ ہے کہ اب مارکسیت پرست افراد خود بھی دو گروہوں پر تقسیم ہو چکے ہیں ۔ مغربی یورپ کے لوگ اصلاحی ڈیموکریسی کے حامی ہیں۔ان کے یہاں کے ترقی یافتہ سیاسی اور اقتصادی حالات نے انقلاب کو قطعی طور پر غیر ضرروی قرار دے دیا ہے۔
لیکن مشرقی یورپ میں انقلاب کے جراثیم ابھی تک موجود ہیںان لوگوں نے اقتصادی اعتبار سے مغرب کے برابر ترقی نہیں کی ہے یہ اور بات ہے کہ مشرق کے انقلابی تصور نے کامیابی حاصل کر لی اور اب یہ بات عمومی طور پر سمجھی جانے لگی ہے کہ مارکس کا صحیح تصور '' انقلابی '' تھا۔
افسوس کہ ان تمام حضرات نے اس اصل نکتہ کی طرف توجہ نہیں کی کہ اس نظریہ کی پیداوار چند خاص حالات میں ہوئی تھی۔ اسے آج مارکسیت کا دوام نہیں قرار دیا جا سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ با ت خود مارکس کے ذہن میں نہیں آئی ت اس کے پرستاروں کا کیا حال ہوگا۔
مارکسیت کے وقتی نظریہ ہونے کی سب سے اہم دلیل یہی اختلاف ہے جو اس کی تفسیر کے بارے میں واقع ہوا ہے ۔ درحقیقت یہ اختلاف مارکسیت کی تفسیر میں نہ تھا بلکہ اس کی محدودیت کی بنا پر تھا۔یہ اور بات ہے کہ فکر کی محدودیت کی طرف توجہ کے نہ ہونے ی وجہ سے مشرق نے اسے انقلابی رنگ پر باقی رکھا اور مغرب نے اپنی ترقی سے متاثر ہو کر اسے اصلاحی رنگ دے دیا۔
ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام ہی افکار اقتصادی حالات سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ ہمیں واضح کرنا ہے کہ بعض افکار کی پیدائش میں حالات زمانہ کو دخل ہوتا ہے اور انہیں افکار میں مارکس کی وہ انقلابی فکر تھی جو انیسویں صدی کے ناگفتہ بہ حالات کے پیش نظر پیدا ہوئی تھی اور پھر بعد کے حالات اس کا صحیح صحیح ساتھ نہ دے سکے۔
دوسری بات یہ ہے کہ مارکس تمام افکار کو نسبی اور حالات کا تابع تصور کرتا ہے تو اس کی اس فکر کو حقیقت مطلق اور ابدی خیال کرنا خود اس کے نظریہ کی صریحی مخالفت ہے جس کے بارے میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاریخی مادیت غوروفکر کے بعد خود ہی اپنے ابطال کے لئے کافی ہے۔
مادیت تاریخ(ایک عام نظریہ کی حیثیت سے)
تاریخی مادیت کا تجزیہ فلسفہ جدلیت بلکہ خود اسی کی روشنی میں کر لینے کے بعد اس بات کا موقع ہے کہ گفتگو کو دوسرے موضوع کی طرف موڑ دیا جائے جو فی الحال اس مادیت کی عمومیت ہے۔
تاریخی مادیت کے شیدائیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تاریخ کے تمام حوادث کی توجیہ و تعلیل کر سکتی ہے ۔ ضرورت ہے کہ ہم اسے میدان بحث میں لا کر دیکھیں کہ آیا اس میں اتنی وسعت وہمہ گیری ہے بھی یا نہیں۔
اس وقت ہمارے سامنے تین سوالات آ رہے ہیں:
(1) تاریخی مادیت کی بنیاد یعنی وسائل پیداوار کا پوری تاریخ بشریت پر اثر انداز ہونا کیونکر ثابت ہو سکتا ہے؟
(2) کیا علمی نظریات کو پرکھنے کا کوئی معیار موجود ہے؟اگر ہے تو اس پر اس مادیت کا کیا وزن قائم ہوتا ہے؟
(3) کیا اس مادیت نے دنیائے تاریخ کے تمام شعبوں کا احاطہ کر لیا ہے؟یا ابھی کچھ گوشے تشنہ تفسیر وتوجیہ رہ گئے ہیں؟
ہماری پوری بحث کا تعلق انہیں بنیای سوالات سے ہے ۔یہ اور بات ہے کہ ان سے فارغ ہونے کے بعد ہم مارکسیت کے تفصیلات سے بھی تعرض کریں گے۔
مادیت تاریخ کے دلائل
جب ہم مارکسیت کے ان دلائل کو معلوم کرنا چاہتے ہیں جو اس نے اس مادیت کے اثبات کے لئے مہیا کئے ہیں تو ہمیں مختلف کتابوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے اور ان سے مختلف دلیلوں کا خلاصہ تین دلیلوں کی شکل میں حاصل ہوتا ہے ۔ ان کتابوں میں اگر چہ دلیلوں کی شکل اور ان کا یہ انداز نہیں لیکن علمی رنگ میں لانے کے بعد ان سب کا ماحصل یہی ہے جو اس وقت ذکر کیا جا رہا ہے۔
فلسفی دلیل
فلسفی دلیل سے مراد وہ دلیل ہے جو ہر واقعہ کی فلسفی تحصیل کرتی ہے اور اس کو عالم کے تجربات وحالات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
اس دلیل کے تحت مادیت تاریخ کو یوں ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عالم میں ایک قانون سببیت ہے جو اس کے رگ وپے میں سرایت کئے ہوئے ہے ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بغیر سبب کے عالم وجود میں آگئی ہو ۔ اس لئے ہم ہر شے کو دیکھ کر اس کے اسباب کی تلاش
شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کا آج کا معاشرہ ہزار سال قبل کے معاشرہ سے کہیں بہتر ہے تو ہمیں فوراً یہ فکر ہو جاتی ہے کہ آخر یہ ترقی کیسے ہوئی ہے۔
پھر یہ طے کرتے ہیں کہ اس ترقی کا راز فکر کی بلندی میں مضمر ہے ۔ جب تک یورپ کی فکر ابتدائی منازل میں تھی اس کا معاشرہ پست تھا اور جب سے اس نے فکری منازل طے کرنا شروع کئے ہیں اس کا معاشرہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا ذہن اسی مقام پر نہیں ٹھہرتا بلکہ آگے بڑھ کر پھر یہ سوال کرتا ہے کہ آخر اس فکری ارتقاء کا سبب کیا ہے؟
کیا یہ سب بلا سبب پیدا ہو گیا ہے ؟ یا یہ انسان کے ساتھ پیدا ہوا تھا ؟ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بات نہ تھی ۔
پھر آخر یہ بلندی کہاں سے آئی اور یہ تغیر کیسے پیدا ہو گیا؟
اب ہمارا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس فکری ارتقاء کے پس منظر میں بھی ایک علت پوشیدہ ہے جو علت اول کا مرتبہ رکھتی ہے اور جس کے فیض سے یہ سارا نظام تاریخ قائم ہے۔
اس وقت یہ ممکن ہے کہ ہم اس ارتقاء کا سبب اقتصادی حالات کو قرار دیں لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اقتصادی حالات کے تغیر کا کیا سبب ہوگا؟ اگر ہم پلٹ کر پھر افکار کا نام لے لیں تو افکار اقتصاد کا نام لینے پر مجبور کریں گے اور اس طرح یہ ایک دوری نظام ہو جائے گا اور انسان ہمیشہ اسی دائرہ میں گردش کرتا رہے گا۔ جیسا کہ فلسفہ مثالیت کا انجام ہوا ہے۔ چنانچہ بلخا نوف کہتا ہے کہ ہیگل اپنی ذات کو ایک دائرہ میں گرفتار پا رہا تھا:
وہ فرانسیسی مورخین کی طرح اقتصادیات کے انقلاب کو افکار کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور افکار کے تغیرات وترقیات کو اقتصادیات کا نتیجہ ۔ جس کا واضح اثر یہ تھا کہ وہ فکری انجام سے محروم ہو کر ایک دائرہ کے اندر گردش کر رہا تھا۔''
(فلسفہ تاریخ ،ص44)
اب اس کے بعد ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم میدان تحقیق میں ایک قدم آگے بڑھائیں اور یہ پتہ لگائیں کہ آخر ان اقتصادی حالات کی علت کیا ہے جو تاریخ کی محرک ہو اور تاریخ سے باہر؟ ہمارے سامنے ایسے وقت میں پیداواری طاقتوں کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ آخری علت ہے جس کے اشاروں پر سارا نظام تاریخ گردش کر رہا ہے۔
خلاصۂ دلیل یہ ہے کہ اگر عالم کی ہر شے کسی نہ کسی علت وسبب کی محتاج ہے تو سوائے ''پیداواری طاقتوں'' کے اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے تاریخ کے جملہ انقلابات کی علت قرار دیا جا سکے لہٰذا انہیں طاقتوں کو علت العلل اور محرک اول کا درجہ عطا ہونا چاہئے۔ مارکسیت کی اس دلیل کو ہم نے مختلف کتابوں سے جمع کرکے نہایت ہی متین اور سنجیدہ شکل میں پیش کیا ہے ورنہ بلخانوف کی کتاب '' فلسفہ تاریخ'' جس کا موضوع ہی یہ تھا اس نے بھی اس دلیل کو اس حسین وشکیل انداز میں ترتیب نہیں دیا۔
اس دلیل پر تبصرہ کرنے کے لئے پہلے قانون علت کاجائزہ لینا پڑے گا تاکہ دلیل کی صحت وعدم صحت کا باقاعدہ اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ تاریخ کا سبب اول ان طاقتوں کے علاوہ کسی اور شے کو قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔
تمہید ی طور پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ '' وسائل پیداوار '' کوئی جامد وثابت شے نہیں ہیں بلکہ زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی تغیر پذیر اور رو بہ ارتقاء ہیں ۔ کل کا وسیلہ کچھ اور تھا اور آج کا وسیلہ کچھ اور۔کل کے اسباب اور تھے اور آ ج کے اور۔ لہٰذا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے ہم ان مفکرین سے وسائل میں پیدا ہونے والے تغیرات کے بارے میں بھی سوال کریں اور یہ پوچھیں کہ آخر ان وسائل میں ترقی وتغیر کے اسباب وعلل کیا ہیں؟
ظاہر ہے کہ بلخا نوف جیسے مورخین تو اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں ۔ اس لئے کہ یہ سوال خود ہی ان کی فلسفی تعمیر کو منہدم کر دیتا ہے لیکن پھر بھی مارکسیت نے اتنی جرأت کی
ہے کہ ان وسائل کی علت خود انہیں وسائل کو قرار دیا ہے ۔آپ تعجب کریں گے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن مارکس پرستوں کا کہنا ہے کہ یہ وسائل اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ ذہن انسانی میں علوم ومعارف کا ایک خزانہ تحویل دیتے جاتے ہیں اور یہ معارف انسان میں اتنی استعداد و صلاحیت پیدا کرتے جاتے ہیں کہ وہ نئے وسائل ایجاد کرسکے اور جدید طاقتوں کو بروئے کار لا سکے۔
مقصد یہ ہے کہ یہی وسائل انسانی افکار کی تخلیق کرکے انہیں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ جدید وسائل کی ایجاد کر سکے اور اس طرح کاروان تاریخ باقی منازل طے کرلے۔
انگلز نے اس مقام پر اس بیان کے امکانات پر زور دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ گردش قائم رہ سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیاہے کہ یہ طریقہ قوانین جدلیت کے خلاف ہے۔
ہماری اس تمہید سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مارکسیت کا یہ طریقہ استدلال انتہائی کمزور اوربے جان ہے ۔ اس لئے کہ اگر مارکس اس قسم کا گردشی نظام تیار کر سکتا ہے تو دوسرے صاحب فکر کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان وسائل کو میدان حساب سے بالکل الگ کرکے یہ کہہ دے کہ اجتماعی حالات باہمی تجربات سے پیدا ہوتے ہیں ۔پھر یہی حالات ترقی کرکے جدید تجربات تشکیل دیتے ہیں اور اس طرح جدید افکار کے وسیلہ سے معاشرہ سے معاشرہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ظاہر ہے کہ مارکس کو ہمارے اس بیان پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لئے کہ اس نے وسائل پیداوار کے بارے میں اسی گردش پذیر نظام کو قبول کیا ہے۔
اگر کوئی شخص قانون علیت کا سہارا لے کر ہماری رد کرنا چاہے تو وہ بھی بالکل غلط اقدام ہوگا ۔ اس لئے کہ یہ قانون ہر شے کی ایک علت چاہتا ہے جس کی برکت سے وہ شے عالم وجود میں آئی ہو ،چاہے وہ وسائل پیداوار ہوں یا اجتماعی حالات ۔ قانون علیت کو ان
باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مارکس تاریخی اعتبار سے اس بات پر یہ اعتراض کرے کہ یہ طریقہ تجربات کے خلاف ہے تو اس کا جواب تاریخی اور تجرباتی دلیل کے ذیل میں دیا جا سکتا ہے ۔ فلسفی بحثوں کو ان تجربات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
نفسیاتی دلیل
اس دلیل کی بنیاد اس امر پر قائم ہے کہ انسان کے افکار اس کے اجتماعی حالات سے پیدا ہوتے ہیں یعنی تاریخی وجود کے اعتبار سے معاشرہ فکر پر مقدم ہوتا ہے لہٰذا کسی معاشرہ کی علت کا درجہ فکر کو ہرگز نہیں دیا جا سکتا ۔
علت کو اپنے معلول سے مقدم ہونا چاہئے اور فکر معاشرہ کے بعد وجود میں آتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب فکر کی علیت باطل ہو گئی تو اب وسائل پیداوار کے علاوہ اور کوئی چیز اس قابل نہیں ہے جسے علت قرار دیا جا سکے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیونکر ثابت کیا جائے گا کہ معاشرہ فکر کی پیداوار نہیں ہے بلکہ فکر معاشرہ کے حالات سے پیدا ہوتی ہے۔
مارکس پرست افراد نے اس سوال کا جواب دینے کے لئے زبان کا سہارا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فکر بغیر لغت کے ناممکن ہے اور لغت معاشرہ کے حالات میں سے ایک حالت اور اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے ۔ چنانچہ اسٹالین نے اس مقصد کو اس طرح بیان کیا ہے :
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ افکار روح انسانی کے تکلم سے پیدا ہوتے ہیں اور انہیں لغت سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔انسان کسی قدر فکر کیوں نہ کرے سب کی بینادلغت پر ہوگی، بغیر الفاظ کے سوچنا غیر ممکن ہے ۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر ایک ذہنی تاثر اور انعکاس ہے اور لغت کا جو ہمارے درمیان رائج ہوتی ہے ۔ (مادیت ومثالیت فلسفہ ،ص77، G.POLITZER )
(اس مقام پر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ خود جارج کی تالیف نہیں ہے بلکہ اسے دو مارکسی اہل قلم JAMS اور M.KAFIG نے تالیف کیا ہے لیکن چونکہ ان دونوں نے اسے جارج کا نام دے دیا ہے لہٰذا ہم بھی اسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔)
اسٹالین نے اپنے اس بیان میں فکر ولغت میں ایک ایسا رابطہ پیدا کر دیا ہے جس کی بناء پر بغیر الفاظ کے فکر کرنا محال ہو گیا ہے اور الفاظ کو افکار کی علت کا درجہ مل گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب جارج مذکور کا دور آیا تو اس نے اس دعویٰ کو علم النفس کی رو سے مدلل ومحکم بنانے کی مکمل کوشش کی اور I.P.BOULOO مکے کلام کا سہارا لیتے ہوئے اسٹالین کے کلام پر اس طرح حاشیہ تحریر کیا:
PHYSIALAGY کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے طبیعیات میں جدلی مادیت کے لئے بہت بڑا مواد کر دیا ہے اور یہ بھی BOULOO کے تحقیقات کا نتیجہ ہے اس لئے کہ اسی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انسان کے جملہ دماغی افعال اس کے ظاہری حالات کا پرتو ہوتے ہیں جو ان احساسات کی بناء پر پیدا ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے حالات سے حاصل کرتا ہے ۔پھر اس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ لغت کے الفاظ وکلمات کو انہیں احساسات کا درجہ دیا جا سکتا ہے جو افکار کی پیدائش کاسبب بنتے تھے لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہوگی اور احساسات کا درجہ اولیٰ ۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسانی افکار کا منشاء اس کے داخلی کیفیات نہیں ہیں بلکہ ان کا تمام تر تعلق اس کے اجتماعی حالات سے ہے جن کے احساس سے فکر کی تولید ہوتی ہے۔
جارج مذکورنے باولوف کے کلام سے جو نتیجہ نکالاہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جملہ دماغی افعال چند معین اشارات کے انعکاس وتاثر کا نام ہیں۔ابتدائے امرمیں یہ اشارے
احساس کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جگہ الفاظ وکلمات کو مل جاتی ہے جو بجائے احساس ظاہری کے خود ہی وہ تاثرات پیدا کردیتے ہیں جو احساس سے پیداہوتے ہیںاور یہی وجہ ہے کہ انسان کوئی غیر مادی فکر کرنے سے قاصر ہے۔اس لئے کہ احساس کسی مجردشیء سے متعلق نہیں ہوتااورجب تمام کام احساس سے متعلق ہوگیا تو احساس خارجی حالات سے تاثر کانام ہے لہٰذا فکر بھی انہیں حالات کے تاثر کا نتیجہ ہوگی اور یہ واضح ہوجائے گاکہ اجتماعی حالات پہلے ہیں اور افکار بعد میں۔
ہم اس مقام پر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیایہ صحیح ہے کہ افکار لغت سے پیدا ہوتے ہیں؟کیا لغت سے آزادکوئی فکر انسانی دماغ میں نہیں آسکتی ؟کیا الفاظ ان افکار کے ذوقِ ظہور کا نتیجہ ہیںجو انسانی فطرت میں تڑپ رہے تھے؟
حقیقت یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے سے پہلے ہمیں خود باولوف کے فلسفہ پر نظرکرنی چاہئے تاکہ اس کا مقصد واضح ہوسکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ جارجنے اس کلام سے کس طرح استفادہ کیاہے۔
باولوف کا کہناہے کہ دنیا کی ہر شیء کے لئے ایک طبیعی محرک ہوتاہے جو فطرت پر ایک خاص اثرڈالتاہے لہٰذا اگر کوئی چیزاس محرک سے ارتباط پیداکرلے تو اسے بھی وہی موثریت کامرتبہ مل جائے گا۔
اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کتے کے سامنے کھانالایاجائے تو اس پر ایک خاص اثر پڑے گا اور اس کے دہن سے لعاب جاری ہوجائے گا۔اب اس کے بعداگر ہم یہ طریقہ اختیار کرلیں کہ کھانالانے کے ساتھ جرس بجادیاکریں تو رفتہ رفتہ کتا اس بات کا عادی ہوجائے گا کہ گھنٹی کی آواز سنتے ہیں اس کی رال بہنے لگے۔چاہے اسے کھانانہ بھی دیاجائے اس لئے کہ اب فرضی اور جعلی محرک نے طبیعی اور واقعی موثر کی جگہ لے لی ہے۔
اس کے بعد اس نظریہ کو انسانی افکار پر منطبق کیاگیااور یہ کہاگیاکہ انسانی افکار بھی
دیگر اشیاء کی طرح چند طبیعی محرکات کا داخلی نتیجہ ہیں جن کا نام احساس وادراک رکھا گیاہے۔
یہی محرکات ہیں جو انسان کے دماغ میں فکر کی ایجاد کرتے ہیں اور یہی وہ موثرات ہیں جن کے پرتوکانام علم ومعرفت،فکر ونظرہے۔اب جس طرح کتے کے یہاں گھنٹی نے طبیعی محرک کی جگہ لے لی تھی اور وہی اثرکرنا شروع کردیاتھا جو کھانا پیش کرنے سے حاصل ہوتاتھا۔اسی طرح انسان کے یہاں بھی ایک جعلی محرک ہے جو اصلی محرک کا کام کرتاہے اور وہ ہے زبان۔آپ تجربہ کرکے دیکھ لیں آپ کے نفس پر لفظ پانی سے وہی اثر پڑے گا جو خود پانی کو دیکھ کر قائم ہوتاہے۔
باولوفنے اپنی اس تحقیق کی بناپر دو مستقل نظام بناڈالے ہیں۔ایک کی بنیاد طبیعی محرکات پر ہے اور دوسرے کی بنیاد فرضی اشارات پر۔پھر ہر ایک کے ترتیبات وتفصیلات معین کئے ہیں اور ان کے آثار کا تعین کیاہے جس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ نہ فکر بغیر احساس کے ممکن ہے اور نہ غیبی اشیاء کے متعلق سوچناممکن ہے۔اس لئے کہ ان کا احساس غیر ممکن ہے۔
ہم باولوفکے ان تمام انکشافات کو تسلیم کرتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان تمام مفروضات کے بعد یہ ثابت ہوجاتاہے کہ فکر لغت وزبان سے پیداہوتی ہے ۔ہمارا جواب اس سلسلہ میں نفی کی صورت میں ہوگا۔اس لئے کہ طبیعی محرکات کے علاوہ جعلی محرکات کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔کبھی یہ محرکات طبیعی طور پر پیداہوجاتے ہیں جس طرح کہ انسان پرپانی کی صورت دیکھ کر ایک خاص حالت طاری ہوجائے تو ظاہر ہے کہ پانی خودطبیعی محرک ہوگا اور وہ حالت جعلی محرک،لیکن یہ جعلی محرک وہ ہوگا جسے ہم نے نہیں بنایاہے بلکہ وہ طبیعی طور پر پیداہوجاتاہے۔
اس کے برخلاف کبھی ایسا ہوتاہے کہ یہ جعلی محرکات ہمارے اجتماعی فرض کے محتاج ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم بچہ کو دودھ دیتے وقت باربار لفظ دودھ کا استعمال کریں تو یہ لفظ
جعلی محرک ضرور ہے لیکن ہمارے استعمال کی بناپر۔
معلوم ہوتاہے کہ الفاظ کی تحریک اور ان کی اشاریت جعلی ہے اور وہ اس قسم کی ہے جس میں اجتماعی عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس بنیاد پر یہ کہاجاسکتاہے کہ انسان کے ذہن میں افکار کی تڑپ موجود تھی اور اس کی خواہش تھی کہ ان افکار کو دوسروں تک منتقل کیاجائے اور اس کے لئے کوئی دوسرا وسیلہ سوائے لغت کے نہ تھا۔اس لئے اس نے لغت کا سہارالیااور اس نے اپنے رازوں کا اظہار شروع کردیاکہ انسانی اجتماع میں پہلے افکار تھے اس کے بعد لغت کا وجود ہوا۔اس کا ایک شاہد یہ بھی ہے کہ حیوانات کے پاس کوئی مرتب لغت نہیں ہے اس لئے کہ ان کے پاس مختلف افکار نہ تھے جن کی تغیر کے لئے انہیں لغت کی ضرورت پیش آتی ۔
انسان نے اپنی زندگی میں لغت کا استعمال اس لئے شروع کیاہے کہ اس نے دنیا کے مختلف محرکات پر نظرکرکے یہ دیکھ لیاہے کہ اکثر جعلی محرکات طبیعی محرکات کی جگہ لے لیتے ہیں۔چنانچہ اس نے بھی طے کر لیاکہ مجھے ایسے فرضی محرکات کا بنانا انتہائی ضروری ہے تاکہ ان کے ذریعہ اپنے مافی الضمیر کو دوسرے افراد نوع تک پہنچایاجاسکے۔ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں اسی وقت صحیح ہوں گی جب احساس وفکرکادرجہ لغت سے پہلے ہو،لغت کے بعد نہ ہو۔ورنہ اگر احساس لغت کے بعد پیداہوتاتو لغت کے اختیار کرنے کی کوئی علت نہ ہوتی اور پھر اس کا انسانوں ہی کے ساتھ مخصوص ہونا بالکل بے معنی ہوتا۔
ہمارے اس بیان سے یہ بھی واضح ہوجاتاہے کہ معاشرہ کا وجود فقط انسانوں میںکیوں ہے حیوانات میں ایسے اجتماعات کیوں نہیں ہیں۔حقیقتاً اس کاراز صرف یہ ہے کہ چونکہ انسانی افکار لغت واحساس سے مافوق ہیں لہٰذا وہ اپنے افکار کے ذریعہ مختلف معاشروںکی تشکیل دے سکتاہے لیکن حیوانات میں یہ قوت نہیں ہے۔ان کے علوم احساس کے تابع ہوتے ہیںاور احساس کا تعلق صرف موجودہ حالات سے ہوتاہے اس کو حالات کے
بدل دینے سے کوئی ربط نہیں ہوتا۔
دوسری بات یہ بھی ہے کہ واقعات کابدل دینایہ ایک ایسا کام ہے جو اکثرا جتماعی عمل کا محتاج ہوتاہے اسی سے انسانوں میں باہمی تعلقات پیداہوتے ہیں اور ان سے ایک معاشرہ وجود میں آجاتاہے۔حیوانات میں چونکہ یہ طاقت نہیں ہے لہٰذا ان کے یہاں معاشرہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔حقیقت امر یہ ہے کہ واقعات کا تغیر وتبدل ہی ایک ایسا اجتماعی کام تھا جس کے لئے انسان کو لغت کی ضرورت پڑی۔یہ کام احساس ومشاہدہ سے نہیں ہوسکتاتھا احساس کا تعلق موجودہ حالات سے ہوتاہے۔اس میں انقلابی حالات کی عکاسی کی قوت نہیں ہوتی ہے۔حیوانات میں اسی فکری سرمایہ کے نہ ہونے کی بناپر ان میں کسی منظم لغت کا وجود نہیں ہے۔
تجربیاتی دلیل
کسی مطلب پر تجربیاتی دلیل قائم کرنے کا طریقہ یہ ہوتاہے کہ پہلے اس کے تمام احتمالات جمع کئے جاتے ہیں۔اس کے بعد انہیں ایک ایک کرکے باطل کیاجاتاہے۔یہاں تک کہ آخر میں جب ایک احتمال باقی رہ جاتاہے تو اسی کو اس واقعہ کی واقعی علت تسلیم کرلیاجاتاہے۔
اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کو روزانہ ایک مخصوص سمت میں جاتے ہوئے دیکھیں تو آپ کے ذہن میں چنداحتمالات پیداہوں گے۔ممکن ہے کہ یہ شخص اپنی کسی خاص ضرورت کی بناپر جاتاہے۔
ممکن ہے کہ اس کا مدرسہ اس طرف ہو،ممکن ہے کہ کسی ایسے طبیب کا علاج کراتا ہوجس کا مکان اس سمت میں ہو،ممکن ہے کہ کوئی اور ضرورت ہو۔ ایسے موقع پر اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ وہ کسی مخصوص ضرورت ہی کے لئے جاتاہے تو آپ کا فریضہ ہوگاکہ طبیب اور مدرسہ جیسے احتمالات کو باطل کریں اس لئے کہ جب تک یہ احتمالات باطل نہ ہوں گے کوئی ایک احتمال قابل قبول نہ ہوگا۔
مارکسیت کی تاریخی مادیت کے بارے میں بھی ہماراقول یہی ہے کہ اگر مارکس تمام تاریخی حادثات کو اقتصادی حالات کا نتیجہ قرار دینا چاہتاہے تو اس کا فرض ہوگاکہ ا س سلسلہ میں پیداہونے والے تمام احتمالات کا سدباب کردے کہ جب تک ایسا نہ ہوگا منطقی اعتبار سے اس کا قول قابل قبول نہ ہوگا۔یہ اور بات ہے کہ عقیدت مندلوگ اسے تسلیم کرلیں گے۔
مثال کے طور پر حکومت کی نشودنما کو لیجئے۔مارکسیت کا خیال ہے کہ حکومت کا تصور بھی اقتصادی حالات کی بناپر پیداہوتاہے جب ایک طبقہ کی ثروت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے کی کم،تو ثروت مند طبقہ اپنے اغراض ومصالح کے تحفظ کے لئے چند قوانین بنالیتا ہے اور پھر اسی کا نام حکومت ہوجاتاہے۔
ہماراکہنا یہ ہے کہ مارکسیت کی یہ توجیہ اسی وقت قبول کی جائے گی جب حکومت کے بارے میں دیگر نظریات باطل قرار دے دیئے جائیں ورنہ جب تک ان نظریات کو تاریخی مدد ملتی رہے گی مارکسیت کا کوئی وزن نہ رہے گا۔جیسا کہ قدیم مصر کے بارے میں کہاجاسکتا ہے کہ وہاں کی اجتماعی زندگی انتہائی خراب تھی زراعت کے لئے نہروں کی شدید ضرورت تھی۔اب جو شخص بھی ان تکالیف ومصائب کو برداشت کرکے ان کے لئے نہروں کا انتظام کردیتاحکومت کرنا اسی کا حق ہوجاتا،چاہے اس کی اقتصادی حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔چنانچہ مصر قدیم میں اکلیروس کی تمام تربزرگی اسی ہنرمندی کا نتیجہ تھی کہ ان لوگوں نے
مصریوں کو زراعت کی سہولتیں بہم پہنچائیں اور پھر کرسی ٔ ریاست پر متمکن ہوگئے۔
اس طرح سے یونان میں اہل کنیسہ کی عظمت وسلطنت بھی کسی اقتصادی خوشحالی کا نتیجہ نہ تھی بلکہ جرمان کے یونان پر حملہ کے نتیجہ میں یونان کی ثقافتی حالت اس قدر خراب ہوگئی تھی کہ اب وہ ہر شخص کے سامنے ثقافت کی بھیک مانگنے کر تیار تھا۔اتفاق وقت کہ وہاں کتابت وقرأت سے آشنا اہل کنیسہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا۔چنانچہ ان لوگوں نے اپنی علمیت کا سہارالے کر قوم کے حالت سدھارنے کا بیڑااٹھالیا۔اب کیاتھا ریاست ان کے قدم چوم رہی تھی اور جرمانی سیاہی سوراور بارہ سنگھے کے شکار میں مشغول تھے۔
ظاہر ہے کہ ان کنیسہ کی یہ اجتماعی اہمیت کسی ثروت مندی کا نتیجہ نہ تھی بلکہ یہ ان کا فکری اور علمی سرمایہ تھا جس کی برکت سے ان کی اقتصادی حالت بھی سدھرگئی اور وہ ثروت مندوں کے طبقہ اول میں شمار ہونے لگے۔
اسی طرح سے اور بہت سی حکومتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد دین ومذہب پر قائم تھی اور ان کی تعمیرمیں اقتصادیات کاکوئی ہاتھ نہ تھا۔
اس کے علاوہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حکومت نفسیات کی بنیاد پر قائم ہو،اس لئے کہ ذی استعداد انسان میں ہمیشہ تفوق وبرتری کا جذبہ ہوتاہے۔ہوسکتاہے کہ یہی جذبہ ایک دن اس کے لئے راستہ ہموار کر دے اور وہ ایک حکومت کی تشکیل پرقادر ہوجائے۔
اس قسم کے اور متعدد احتمالات ہیں جن کے تاریخی ثبوت موجودہیں اور ان کا باطل کرنا مارکسیت کا فرض اولین ہے ورنہ اس کے بغیر اس کی توجیہ کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوگی۔
دیکھایہ ہے کہ مارکسیت نے اس سلسلہ میں کون سی دلیل مہیا کی ہے؟
اس مطلب کو سمجھنے کے لئے ایک بات کو پیش نظررکھ لینا انتہائی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری بحث تاریخی ہے طبیعاتی نہیںہے اور تاریخ کی بحثیں طبیعات کی بحثوں سے بالکل مختلف ہواکرتی ہے۔ان دونوں بحثوں میں دواہم بنیادی فرق ہوتے ہیں:
(1) طبیعات کا ماہر جب یہ تجربہ کرناچاہتاہے کہ حرارت کیسے پیداہوتی ہے؟نور کی علت کیاہے؟تو اس کے سامنے تحقیق وتجربہ کے تمام عناصر ومواد موجود ہوتے ہیں۔ وہ تجربہ گاہ میں تمام اسباب کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتاہے۔
لیکن تاریخ کا ماہر جب کسی مطلب پر تاریخی استدلال قائم کرنا چاہتاہے تو اس کے پاس دلیل کے مواد میں سے کوئی شیء اپنی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ سابق کے روایات اور ماضی کی ان داستانوں پر اعتماد کرتاہے جن کا مشاہدہ خود اس نے نہیں کیاہے بلکہ انہیں لوگوں کی زبانی حاصل کیاہے۔
ظاہر ہے کہ تاریخی استدلال کے لئے یہ بہت بڑانقص ہے جس سے ہر مورخ کو دوچار ہوناپڑتاہے۔چنانچہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ خودانگلز نے بھی اپنی کتاب''اصل خاندان''میں استدلال کی پوری بنیاد ایک سیاح یعنی مورغانکے بیانات پر قائم کی ہے۔
(2) ماہر طبیعات کے لئے ایک سہولت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی واقعہ کے مختلف احتمالات کو اپنی نظروں کے سامنے لاسکتاہے۔اس کی قدرت کسی ایک صورت سے مخصوص نہیں ہوتی۔ اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی حادثہ کو پچاس شکلوں میں ڈھال کریہ اندازہ کر لے کہ اس حادثہ کی صحیح علت کیاہے۔
وہ جس وقت یہ طے کرناچاہتاہے کہ''حرکت سے حرارت پیداہوتی ہے''تو پہلے حرکت کے ساتھ جتنی چیزیں ہوتی ہیں انہیں ایک ایک کرکے الگ کرتاہے اور یہ دیکھتاجاتا ہے کہ ابھی حرارت باقی ہے۔اس کے بعد ان تمام چیزوں کو جمع کرکے حرکت کوالگ کر لیتا ہے اور یہ دیکھتاہے کہ اب حرارت ختم ہوگئی ہے تو اس طریقۂ جمع و تحقیق سے یہ طے کر لیتاہے کہ حرارت کی علت یہی حرکت ہے جس کے وجود سے حرارت کا وجود ہے اور جس کے عدم سے حرارت کا عدم ہوجاتاہے۔
ماہر تاریخ کے لئے یہ کوئی بات ممکن نہیں ہے۔ وہ اس قدرمجبور ہوتاہے کہ تاریخ کے کسی ایک حادثہ کے کسی ایک معمولی سے معمولی جزو میں بھی تغیر نہیں پیداکر سکتاوہ یہ تو کرسکتاہے کہ حکومت کی تشکیل کا سبب اقتصادی حالات کو فرض کرلے لیکن اس کے امکان میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی اقتصادیات کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومت سے اقتصادی حالات کو ایک کرکے سیاست یا ثقافت کو اس کی جگہ پر رکھ دے اور پھر وہ دیکھے کہ اب حکومت قائم ہوتی ہے یا نہیں
مورخ کی یہی وہ مجبوری ہے جو اسے ہر قطعی دلیل کے قائم کرنے سے روک دیتی ہے او رنتیجہ کا ر میں اس کی بنیاد وروایات واوہام پر قائم ہوجاتی ہے۔ نہ اس کی بحث کے عناصر اس کے مشاہدہ میں آتے ہیں اور نہ اس میں تغیر وتبدل کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔مورخ کے پاس صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ وہ مختلف حوادث کا جائزہ لے کر انہیں کی بنیاد پر کوئی نتیجہ برآمد کرلے چاہے وہ غیر یقینی ہی کیوں نہ ہو۔
چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مارکسیت نے بھی اپنے تاریخی مفہوم پر استدلال کا یہی طریقہ اختیار کیاہے اور اس نے بھی چند حوادث وواقعات کا مشاہدہ کرکے تاریخ کی ایک عمارت کھڑی کر دی ہے۔
بلکہ اس نے تو ایک غضب یہ بھی کر دیاہے کہ چند واقعات کو ملاحظہ کرکے پوری تاریخ انسانیت کی توجیہ انہیں چند واقعات کی بناپر کردی ہے۔چنانچہ انگلز کہتاہے:
چونکہ تمام ادوارتاریخ میں حرکات تاریخ سے بحث کرنا تقریباً محال ہے اس لئے کہ ان کے تعلقات اور ان کے ردفعل سب ہم سے مخفی ہوچکے ہیںلیکن اس کے باوجود زمانہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اس معمہ کو حل کرسکتے ہیں۔ انگلینڈمیں بڑی صنعتوں کی ترقی نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ سیاسی جنگ کی ساری بنیاد دو طبقوں کی خواہش جاہ طلبی پر ہوتی ہے۔ایک طبقہ
کاشتکاروں کاہوتاہے اور ایک سرمایہ داروں کا۔ (لاڈفیج فیور باخ،ص90)
اس عبارت کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ مارکسیت کی نظر میں یورپ یا جاپان کی زندگی کے چند لمحات کا مشاہدہ کرلینا اس فیصلہ کے لئے کافی ہے کہ طبقاتی نزاع اور اقتصادی حالات ہی پوری تاریخ انسانیت کے محرک وموثر رہے ہیں۔اس کے نزدیک اٹھارہویں یا انیسویں صدی کے تاریخی مناظرمیں سے کسی ایک منظر کا دیکھنا اس بات کے لئے کافی ہے کہ وہی حکم پوری تاریخ بشریت پر نافذ کردیاجائے جب کہ اس کے حالات ہمارے نگاہوں سے اوجھل بلکہ بقول انگلز ان کے اسباب کا معلوم کرنا تقریباً محال ہے۔
اس وقت مناسب یہ معلوم ہوتاہے کہ انگلز کی اس عبارت کوبھی نقل کردیاجائے جس میں اس نے جدلیت کی ہمہ گیری کا اعلان کیاہے۔چنانچہ اس کا بیان ہے کہ:
یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ میراارادہ ریاضیات اور طبیعات کے بارے میں مختصر طریقہ پر بیان دینے کا تھا تاکہ تفصیلی طور پر اس بات کو بیان کروں جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے اور وہ یہ کہ جدلیت کے قوانین تاریخی حوادث کے لئے بنائے گئے تھے اور وہ خود بخود طبیعات تک راہ پیداکئے چلے جارہے ہیں۔
(ضددوہرنگ،ج2،ص193)
اگر آپ اس عبارت کو سابقہ عبارت سے ملاکردیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پر یہ معلوم ہوجائے گا کہ مارکسیت نے پہلے تو ایک حادثۂ تاریخ سے پوری تاریخ کے اسباب ومحرکات طے کئے اور پھر انہیں قوانین کو طبیعات میں بھی راستہ دے دیا اور اس طرح ایک حادثہ سے پوری کائنات تاریخ وطبیعات کے علل واسباب کا فیصلہ ہوگیا اور کائنات ایک داخلی نزاع کا نتیجہ قرار پاگئی۔
کیاکوئی اعلیٰ معیار موجودہے
مارکسیت کی نظر میں کسی نظریہ کی صحت کا سب سے اچھا معیار یہ ہے کہ اسے انطباق کے میدان میں آزماکر دیکھاجائے اگر تاریخ پر اس کا انطباق صحیح ہے تو نظریہ بھی صائب ہے لیکن اگر تاریخی انطباق اس کا ساتھ نہ دے سکے تو پھر اسے باطل ہی خیال کرنا چاہئے۔چنانچہ اس سلسلہ میں مادزی تنگ MAD TSETUNG لکھتاہے:
جدلی مادیت میں نظریۂ معرفت تطبیق کو سب سے اونچا مقام عطا کرتاہے۔اس کی نظرمیں کوئی نظریہ تطبیق سے جدانہیں ہوسکتا بلکہ انطباق سے الگ ہونا ہی نظریہ کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ (حول التطبیق،ص4)
جارج پولتیزر لکھتاہے:
سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نظریہ اور انطباق کے اتحاد کو سمجھیں اور اس سلسلہ میں قابل غوربات یہ ہے کہ جو شخص بغیر نظریہ کے چلے گا اس کی رفتار نابینا جیسی ہوگی اور جو تطبیق کو ترک کردے گا وہ جمود میں گرفتار ہوکر رہ جائے گا۔
(مادیت ومثالیت فلسفہ،ص114)
ہمارافریضہ ہے کہ ہم مارکسیت کو بھی اسی بنیاد پر آزمائیں تاکہ یہ معلوم ہوسکے کہ وہ تاریخ کے مختلف ادوار پرکس طرح منطبق ہوتی ہے۔
ظاہر ہے کہ مارکسیت کی تمام ترتوجیہ اس معاشرے کی طرف ہے جس میں تاریخ سرمایہ داری سے اشتراکیت کی طرف آرہی ہے اسے ان تمام معاشروں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس کی پیدائش سے پہلے عالم وجود میں آکر ختم ہوچکے ہیں۔اس لئے ہم اسی ایک معاشرہ کا جائز لینا چاہتے ہیں تاکہ مارکسیت کی صداقت وحقانیت کا صحیح اندازہ ہوسکے۔اس لئے کہ یہ نظریۂ امتحان بھی اسی کا ایجاد کردہ ہے۔
اس مقام پر ہم اشتراکی ممالک کو دوقسموں پر تقسیم کردیتے ہیں۔بعض ممالک وہ ہیں جن میں اشتراکی نظام خونی انقلاب کا ممنون احسان ہے جیسے بولونیا، یوگوسلاویکیا، ہنگری وغیرہ کہ ان مقامات پر انقلاب اشتراکیت کو جدلی قوانین سے کوئی تعلق نہ تھابلکہ اس کا تمام تردارومدار مسلح طاقت او رفوجی قوت پر تھا اور یہی وجہ تھی کہ جرمنی دوحصوں پر تقسیم ہوگیا۔ جہاں تک انقلاب کے شرارے پہنچ گئے اشتراکی ہوگیا اور جہاں یہ آگ نہیں پہنچی وہ سرمایہ داریت پر باقی رہ گیا ورنہ یہ کیسے معقول تھاکہ ایک ہی ملک کے وسائل پیداوار اسے دو حصوں پر تقسیم کر دیتے ایک اشتراکی ہوتااور ایک سرمایہ دار۔
اس کے برخلاف بعض اشتراکی ممالک وہ ہیں جہاں اشتراکیت داخلی انقلابات کی بناپر بروئے کار آئی ہے لیکن جدلی قوانین کے انداز پر نہیں بلکہ دیگر ضرورتوں کے زیر اثر جیسے روس جو آج اشتراکیت کا اعلیٰ نمونہ خیال کیاجاتاہے کہ وہ اقتصادی اعتبار سے یورپ کے تمام ممالک سے پیچھے تھا،صنعتی کمزوری آخری نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی،انقلاب کی مارکسی صلاحیتیں بالکل مفقود تھیں اور فرانس وبرطانیہ ان انقلابی جراثیم سے مالامال تھے لیکن اس کے باوجود ان میں انقلاب کا تصور بھی نہ تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ روس میں انقلاب آگیا، صنعتوں کو فروغ حاصل ہوگیا،اقتصادی حالات سدھر گئے اور فرانس اپنی حالت پر باقی رہ گیا۔ درحقیقت یہ بھی اشتراکیت کی بدنصیبی تھی کہ خوشحال ممالک انقلاب سے محروم رہے اور پس ماندہ ملک اس نعمت سے بہرہ ورہوگیا۔
حقیقت امر یہ ہے کہ جب ہم وسائل پیداوار کو انقلاب کے ساتھ ملاکر روس کے آئینہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں مارکسیت کا نظریہ بالکل الٹا نظرآتاہے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ انقلاب سے وسائل پیداہوتے ہیں نہ کہ وسائل سے انقلاب۔
روس کے انقلاب میں تمام ترموثر ومحرک وہاں کی معاشی حالت کا خراب ہونا اور صنعتی اعتبار سے اس کا پس ماندہ اور دور افتادہ ہونا تھا کہ اگر یہ معاشی بحران نہ ہوتا اور اسے
اس بات کا احساس نہ ہوتاکہ اگر آج اپنی حالت کی اصلاح نہ کی گئی تو کل زورآور ممالک اپنا لقمۂ اجل بنالیں گے اور میری شخصیت فنا کے گھاٹ اتر جائے گی تووہاں اس انقلاب کا تصور بھی نہ ہوتا۔
معلوم ہوتاہے کہ اس معاشی زبوں حالی اور اسی صنعتی کمزوری نے روس کو انقلاب سے آشنا بنایا۔ورنہ اسے مارکسی اصولوں کی بناپر انقلاب سے دورکا بھی لگاؤ نہ تھا۔
مارکسیت میں انقلاب اس وقت ہوتاہے جب جدید وسائل قدیم نظام سے ٹکرا جاتے ہیں اوردونوں میں داخلی تصادم ہوجاتاہے اور ظاہر ہے کہ روس میں جدید وسائل کا سوال ہی نہ تھا۔وہاں تو سارامسئلہ انہیں وسائل کا فقدان تھا جس نے انقلاب کو برپاکر دیا۔
حقیقت یہ ہے کہ تاریخ روس میں ہم نے کوئی بات ایسی نہیں دیکھی ہے جسے مارکسیت کے جدلی قوانین پر منطبق کیاجاسکے اور جس کی بناپر یہ تسلیم کیاجاسکے کہ تاریخ نظام داخلی نزاع پر قائم ہے۔
روس ہی کی طرح کا دوسرااشتراکی ملک چین ہے یہاں کا تغیر وتبدل بھی اگرچہ انقلاب کے زور پر ہواہے اور یہاں بھی اشتراکیت انقلاب کے اثرمیں پھیلی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں بھی مارکسیت تشنہ انطباق ہے اور اس کے اصول محتاج استدلال۔
چین کے بارے میں یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں کے انقلاب میں تصادم و تنازع طبقہ حاکم ومحکوم میں نہ تھا کہ آخرکار محکوم طبقہ کی فتح ہوتی اور قانون جدلیت کی بناپر حکومت قائم ہوجاتی بلکہ یہاں کا انقلاب بھی اسی خارجی حملہ کا نتیجہ ہے جس کی تاب حاکم طبقہ میں نہ تھی اور جس کی بناپر وہ شکست خوردہ ہوگیااور محکوم طبقہ کو اتنا موقع مل گیاکہ وہ حکومت سنبھال سکے بلکہ روس میں بھی قیصریت کی تباہی اسی مسلح حملہ کا نتیجہ تھی اور وہاں بھی کسی داخلی تصادم کا کوئی ذکرنہ تھا۔
خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کسی مقام پر بھی انطباق کے آئینہ میں مارکسی نظریہ کی شکل
نہیں دیکھی ہے۔ہمیں توصرف اتنا نظرآتاہے کہ معاشرہ میں ایک انقلاب آیا۔حاکم طبقہ معزول ہوا۔محکوم نے زمام حکومت سنبھال لی لیکن اس کے اسباب کا تعلق وسائل پیداوار یا داخلی نزاع سے نہ تھا بلکہ اس کے پس منظرمیں خارجی طاقتیں اور مسلح حملے تھے جنہوں نے ملک کی حالت بدل دی اورنئے نظام کی بنیاد پڑگئی۔
آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو انقلاب روس کے ساتھ عالمگیر جنگ کے طفیل میں متعدد انقلابات نظرآئیں گے اور ان سب کا محرک اور موثر ایک ہی احساس ہوگاکہ اگر آج قافلۂ تاریخ سے ملحق نہ ہوگئے تو کل تباہی کا سامنا ہوگا۔عوام کو اس احساس نے ابھارا اور مسلح حملوں نے مزید سہارادیا،ملک کا نظام بدل گیا اور جدید قوانین حکومت کرنے لگے۔
حقیقت یہ ہے کہ اگر نظریہ کی صحت کا دارومدار انطباق پرہے تو مارکسیت آج تک تشنۂ دلیل ہے اس لئے کہ ہم نے تاریخ کے کسی دور میں بھی اس کا انطباق نہیں دیکھاہے بلکہ یہی احساس خودلینن کے دل میں بھی تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نے روس کے انقلاب کے نتائج کا اعلان اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ انقلاب منزل آخر پر نہیں آگیا۔وہ دیکھ رہا تھاکہ مارکسی قوانین ابھی انقلاب کے مقتضی نہیں ہیں ہوسکتاہے کہ انقلاب ناکامیاب ہو جائے۔چنانچہ اس نے سولیراکے نوجوانوں کوخطاب کرتے ہوئے انقلاب فروری سے ایک ماہ اور انقلاب اکتوبرسے دس ماہ قبل یہ کہاتھاکہ:
شاید ہم اس وقت تک زندہ نہ رہیں جب اشتراکی انقلاب اپنے قطعی تنائج کو پیش کرے لیکن آثارکی بناپر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سولیراکے نوجوان اس انقلاب سے بڑافائدہ اٹھائیں گے۔وہ صرف انقلاب میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ اس کے بعد بھی کامیاب رہیں گے۔
عجیب پرلطف بات ہے کہ جہاں لینن نے اعلان کی جرأت نہیں کی وہاں تو دس
مہینہ کے بعدانقلاب آگیااور جن سولیراکے نوجوانوں کو بشارت دی تھی وہ غریب آج تک لینن کے خواب کی تعبیر کا انتظار کررہے ہیں اور ان فوائد کی آس لگائے بیٹھے ہیں جن کی بشارت لینن نے دی ہے۔
کیا مارکسیت پوری تاریخ پر محیط ہے
یہ بات واضح ہوچکی ہے کہ مارکسیت تاریخ کی توجیہ کے سلسلہ میں پیداہونے والے احتمالات میں سے ایک احتمال کانام ہے جس کے ثبوت کے لئے چند مختلف واقعات جمع کرلئے گئے ہیں اور یہ دعویٰ کیاگیاہے کہ مارکسیت ان تمام واقعات پرپوری طرح منطبق ہوتی ہے۔لہٰذا پوری تاریخ کو اقتصادی حالت اور وسائل پیداوار کا نتیجہ قرار دینا چاہئے۔
حقیقت امریہ ہے کہ مارکسیت کی توجیہ میں یہی وہ جاذب نظرنکتہ ہے جس نے تمام توجیہات کو ناقابل اعتنا بنادیاہے۔ہر انسان یہ خیال کرتاہے کہ نظریہ پوری تاریخ کو شامل ہے اس کے قوانین حتمی اور یقینی ہیں اس کی نظرمیں تاریخ میں ایک تسلسل اور اس کے حوادث میں ایک ارتباط ہے جس کی بناپر ہر موجودہ واقعہ اپنے مستقبل کی خبر دے رہاہے۔
جدلی قوانین اس کی پشت پناہی کررہے ہیں اور تاریخ اس کی ہمنوائی میں سرگرم ہے اور سب سے لطیف بات یہ ہے کہ یہ عوامی توہمات کی ترجمانی بھی ہے اسے فقط علماء وفضلاء کی ترجمانی سے ارتباط نہیں ہے۔
مارکسیت کی تاریخ مادیت کی بنیاد ایک تعمیری تسلسل پرہے جس کی پہلی کڑی
وسائل پیداوار دوسری کڑی اقتصادی حالات اور آخری کڑی اجتماعی کیفیات ہیں۔ اقتصادی حالات محرک اور متحرک کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہیں جووسائل کی تاثیر کو معاشرہ تک پہنچا رہے ہیں۔جیساکہ بلخانوفنے اعلان کیاہے:
ہرقوم کے اقتصادی حالات اس کے معاشرہ کو تشکیل دیتے ہیں اور پھر اسی معاشرہ سے سیاسی اور دینی حالات پیداہوتے ہیں۔اب اگر یہ سوال کروکہ اقتصادی حالات کاکیاسبب ہے؟تویادرکھو کہ اس کا بھی ایک سبب ہے اور وہ ہے انسان کا عالم طبیعت سے مقابلہ یعنی پیداوار۔(الفہوم المادی للتاریخ،ص46)
پیداواری حالات لوگوں کے درمیان اجتماعی تعلقات قائم کرتے ہیں اور خودوسائل انتاج کے ذریعہ عالم وجود میں آتے ہیں۔ (کتاب مذکور،ص48)
مارکسیت کے مخالفین عام طور سے اس پردو اعتراض وارد کرتے ہیں:
(1) اگرتاریخ اقتصادی عوامل ومحرکات کا نتیجہ ہے اور وہ فطری طورپر اسے سرمایہ داری سے اشتراکیت کی طرف لے جارہے ہیں توپھر مارکسی اہل نظرانقلاب کی اتنی کوششیں کیوں کر رہے ہیں اور انہیں اشتراکی انقلاب کی اتنی زیادہ فکر کیوں لاحق ہے۔
(2) ہرانسان فطری طور پر اس بات سے واقف ہے کہ اس کے نفس میں اقتصادیات کے علاوہ دیگر جذبات وخواہشات بھی پائے جاتے ہیں جن کی خاطر وہ پوری اقتصادی زندگی کو قربان کردینے پر آمادہ ہوجاتاہے کیا ایسے جذبات کے ہوتے ہوئے تاریخی موثر کا درجہ صرف اقتصادی حالات کو دیاجاسکتاہے؟
ہماری نظرمیں انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ان اعتراضات کے بارے میں بھی اپنا موقف صاف کر دیں اور یہ بات اسی وقت ہوسکتی ہے جب مارکسیت کی نظرمیں انقلاب کا مفہوم واضح ہوجائے۔
پہلے اعتراض کے بارے میں یہ کہاجاسکتاہے کہ مارکسیت پرست حضرات کی نظر
میں انقلاب کی کوششیں تاریخ سے علیحدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی کوششوں سے ایک تاریخی ضرورت کو پورا کررہے ہیں اور ایک آنے والے انقلاب کی فطری راہیں ہموار کررہے ہیں۔
مارکسیت اگرچہ اس جواب پر اکتفا کرلیتی ہے لیکن افسوس کہ وہ اس کے تقاضوں سے صحیح طریقہ سے واقف نہیں ہے چنانچہ خوداسٹالین کا کہناہے:
معاشرہ قوانین کے مقابلہ میں بالکل عاجز نہیں ہوتاہے بلکہ اس کے امکان میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ ان قوانین کے دائرہ کو محدود کرکے انہیں اپنے مصالح سے ہم آہنگ بنالے اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو طبیعی قوانین کے ساتھ کیاجاتاہے۔(دورالافکار المتقدمیہ فی تطویر المجتمع،ص32)
پولتیزرلکھتاہے:
مادی جدلیت اگرچہ اجتماعی قوانین کو بڑی اہمیت دیتی ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ افکار کی اہمیت کی بھی شدت سے قائل ہے۔اس کی نظرمیں افکار ان قوانین کو مقدم وموخر کرسکتے ہیں بلکہ انہیں بے سود بھی بناسکتے ہیں۔
(مادیت ومثالیت فلسفہ،ص22)
ظاہر ہے کہ افکار بشری کی اتنی اہمیت کہ وہ اجتماعی اور جدلی قوانین کو مقدم وموخربناسکیں۔مارکسی نظریہ سے بنیادی اختلاف رکھتی ہے وہ افکار جو بقول مارکسیت تاریخی حادثات کے اجزاء میں شمار ہوتے ہیں اور جن پر جدلیت کے قوانین پوری طرح سے اثرانداز ہوتے ہیں ان میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی کہ وہ ان قوانین میں ردوبدل اور تقدم وتاخر سے کام لے سکیں؟
اوراسٹالین کا انہیں طبیعی قوانین پر قیاس کرنا تواور بھی مضحکہ خیز ہے اس لئے کہ عالم طبیعیات جن قوانین میں تقدم وتاخر اور ردوبدل کرتاہے خود ان قوانین کا محکوم نہیں ہوتاہے اور یہاں مارکسیت نے افکار کوتاریخی قوانین کا محکوم فرض کیاہے تو کیا اس کے بعد
بھی یہ ممکن ہے کہ ان قوانین میں ترمیم وتنسیخ کی جاسکے؟
حقیقت یہ ہے کہ مارکسیت نے پہلے اعتراض سے بچنے کے لئے ایک جواب دے دیاتھا اور افکار کو تاریخ کا ایک جزوقرار دے کر نجات حاصل کرلی تھی لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ ایک دن انہیں افکار کو تاریخ میں موثر بھی قرار دینا ہے جو اپنی بنیاد فکر سے بالکل متضادبات ہوگی۔
دوسرے اعتراض کے بارے میں مارکسیت کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ان جذبات و خواہشات کو تاریخی موثر ومحرک کادرجہ اسی وقت دیا جاسکتاتھا جب یہ اقتصادی عوامل سے الگ کوئی شے ہوتے لیکن مارکسیت نے یہ تو ثابت کردیاہے کہ انسانی شعور بھی اس کے اقتصادی حالات کا باطنی انعکاس ہے لہٰذا اب اس شعور کو مستقل حیثیت دے کر اقتصادی عوامل کے مقابلہ میں پیش کرنا ایک بنیادی غلطی ہوگی۔
مارکسیت کا یہ جواب کسی حدتک سنجیدہ ہوتااگر ہمارے سامنے اس کے وہ ارشادات نہ ہوتے جن میں اس نظریہ کی صریحی مخالفت کی گئی ہے اور اقتصادیات کو وسیلہ ومحرک ہونے سے نکال کر انہیں غرض وغایت کا درجہ دے دیاگیاہے۔چنانچہ انگلز لکھتاہے:
قوت ہر کام کے لئے فقط وسیلہ ہوتی ہے لیکن اقتصادی منفعت تو غرض وغایت بھی ہے اور ظاہر ہے کہ غایت قوت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔لہٰذاتاریخ میں اقتصادیات کو سیاسیات سے بلنددرجہ حاصل ہونا چاہئے اس لئے کہ سیاست توفقط پیٹ بھرنے کا وسیلہ ہے۔
ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ انگلزنے اپنا یہ بیان نہایت لاپروائی کے ساتھ دیاہے ورنہ اس میں یہ جرأت کسی وقت بھی ممکن نہ تھی کہ سیاسی افکار کو اقتصادی حالات سے الگ ایک شے تصور کرے اور پھر سیاست کو محرک بناکر اقتصاد کو غرض وغایت بنادے جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھاہے کہ بعض اوقات پیٹ بھرنے والے بھی اچھے اچھے کام کرجاتے ہیں خواہ
ان کا مقصد کچھ ہی کیوں نہ ہو۔
مارکسیت پر یہ اعتراضات اگرچہ کافی اہمیت رکھتے ہیں لیکن ہم اعتراضات سے قطع نظرکرکے ان مشکلات کو پیش کرنے کی کوشش کررہے ہیں جن کو حل کرنے کی توفیق مارکسیت کو اب تک حاصل نہیں ہوئی اور نہ مادیت تاریخ انہیں تاابدحل کر سکتی ہے۔
ان مشکلات کی تفصیل یہ ہے
پیداواری قوتوں کا ارتقاء اور مارکسیت
مارکسیت کے بارے میں سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ ان پیداواری طاقتوں میں جنہیں پوری تاریخ کا موثر ومحرک قراردیاگیاہے کیونکہ تغیروتبدل ہوتاہے اور پھر ان کے اسباب ارتقاء کو تاریخی محرک کا درجہ کیوں نہیں دیاگیا۔
مارکسیت کے دلدادہ حضرات عام طور پر اس سوال کا جواب یہ دیاکرتے ہیں کہ یہ قوتیں انسان کے ذہن میں تجربات کی وجہ سے جدید افکار تشکیل دیتی ہیں اور پھر انہیں جدید افکار سے نئی قوتیں وجود میں آتی ہیں گویاکہ قوت کی ایجاد جدلی عنوان سے قوت ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔
مارکسیت کا خیال ہے کہ معاشرہ میں جدلی قوانین کے انطباق کا اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اقتصادیات او رافکار کو علت ومعلول کا درجہ دے دیا ہے تاکہ یہ کہاجائے کہ معلول اپنی علت سے ٹکراکرنئے وسائل کی ایجاد کرتاہے۔
ہم نے فلسفی بحث کے موقع پر اپنی پہلی کتاب میں اس مسئلہ کو پوری تفصیل کے
ساتھ بیان کر دیاہے اور یہ ثابت کر دیاہے کہ افکار کو اجتماع کی پیداوار قرار دینا ایک فاش غلطی ہے یہاں بھی اس کی توضیح یوں کی جاسکتی ہے کہ اگر جدید وسائل کو قدیم تجربوں کی پیداوار تسلیم کرلیاجائے تو اس کا مطلب یہ ہوگاکہ تجربہ محسوس حالات کے تصورکے علاوہ کوئی اور شیء ہے۔حالانکہ تجربہ کا مفہوم صرف یہ ہے کہ انسان جس چیز کو سامنے دیکھے اسے ذہن میں محفوظ کرلے۔
ظاہر ہے کہ خارجی حالات کا ذہنی تصور کسی جدید شیء کو اس وقت تک ایجاد نہیں کرسکتا جب تک کہ اس تصور میں کوئی تصرف نہ کیا جائے اور اسے جدید تقاضوںکے مطابق نہ ڈھال لیاجائے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ کام تجربات سے حاصل نہیں ہوسکتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ وسائل انسان کے ذہن میں اپنے تصورات قائم کرتے ہیں اور وہ اپنی نفسیاتی صلاحیتوں کی بناپر ان میں تصرف وتغیر وتبدل کرکے ان سے ایک نئی شکل ایجاد کرتاہے۔جس کے بعدان وسائل کو سابقہ وسائل کا معلول نہیں قرار دیاجاسکتااور نہ انہیں تجربات ہی سے کوئی ربط ہے۔تجربات توصرف فکری کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔انہیں فکرکی ایجادمیں کوئی دخل نہیں ہوتاہے۔
اب تک توہماراسوال یہ تھاکہ ان پیداواری طاقتوں کا ارتقاء کیونکر وجود میں آیا؟ اور آپ نے دیکھاکہ مارکسیت اس کے جواب سے قاصر رہی۔اب ہم اس سوال کو ذرااور بھی دقیق بنائے دیتے ہیں تاکہ مارکسیت کی فکری راہیں اور بھی دشوار گزار ہوجائیں۔ہمارا تازہ سوال یہ ہے کہ پیداوار کی فکر صرف انسان کے ذہن میں کیوں پیداہوئی دیگر حیوانات میں یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے؟
ظاہر ہے کہ مارکسیت اس مقام پر سکوت کرے گی۔اس لئے کہ اس نے تمام عالم کو پیداوار کا نتیجہ قرار دیاہے اور یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ اگر تمام عالم انسان کے دست وبازو پرچل رہاہے تو خودانسانی صلاحیت کا منشا کیاہوگا؟
ہم مارکسیت کی نظرمیں پیداوار کے معنی معلوم کرنے کے بعد اس کا صحیح جواب پیش کریں گے خواہ وہ خود اس جواب سے راضی نہ بھی ہو مارکسیت کا کہنا ہے:
پیداواراس اجتماعی عمل کا نام ہے جس کے ذریعہ عالم طبیعت سے مقابلہ کرکے اپنی ضرورت کی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں اور اس طرح طبیعت کے رخ کو ضرورت کی طرف موڑدیاجاتاہے۔
ظاہر ہے کہ اجتماعی عمل دوچیزوں کا محتاج ہے۔ان کے بغیر اس کا عالم وجود میں آنا محالات میں سے ہے:
(1)فکر:
طبیعت کا موجودہ حال سے دوسری حالت کی طرف موڑدینا مثلاً گندم سے آٹا اور آٹے سے روٹی بنادینا یہ وہ عمل ہے جسے فکر کے بغیر انجام نہیں دیاجاسکتا۔انسان جب تک ذہن میں اس آنے والی صورت کا نقشہ قائم نہیں کرے گا اس وقت تک عالم طبیعت کو مس بھی نہیں کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ حیوانات اس پیداوار سے محروم ہیں اس لئے کہ ان میں اس فکر کا مادہ نہیں ہے۔
(2)زبان:
ایسے اجتماعی اعمال کے لئے ایک ایسی زبان کی ضرورت ہے جس سے تمام لوگ باہمی گفت وشنید کاکام لے سکیںاس لئے کہ جب تک ان کے درمیان باہمی مفاہمت کا کوئی وسیلہ نہیںہوگا وہ کوئی اجتماعی عمل انجام نہیں دے سکتے۔
ہمارے اس بیان سے واضح ہوگیاکہ انسانی معاشرہ میں فکر ولغت دونوں کا درجہ پیداوار سے مقدم ہے اور پیداوار کا عمل ان کے بغیر انجام نہیں پاسکتالہٰذا تاریخی مادیت کا یہ کہنا کہ فکر ولغت اقتصادی حالات اور پیداواری طاقتوں کا نتیجہ ہیں ایک نہایت ہی مہمل اور بے معنی قول ہے۔
ہمارے دعویٰ کی ایک نہایت ہی مستحکم دلیل یہ ہے کہ تاریخ میں زبان کی رفتار پیداوار سے ہمیشہ الگ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بقول مارکسیت روس کے اقتصادی حالات نے وہاں اجتماعی انقلاب توپیداکردیالیکن اب تک وہاں کی زبان میں کوئی فرق نہیں آیا۔اسی طرح بخاری آلات نے انگریز اجتماع میں ایک ہیجان تو برپاکر دیالیکن اس کی بناپر انگریزی زبان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
معلوم ہوتاہے کہ اجتماعی انقلاب کو زبان کے تغیر وتبدل سے کوئی تعلق نہیں ہے ورنہ اس انقلاب کے ساتھ ہی لغت میں بھی ایک انقلاب برپا ہوجاتا۔
اب سوال یہ رہ جاتاہے کہ اگر ان امور کا سبب اقتصادی حالات نہیں ہیں تو پھر کیاہے؟
یہی وہ مسئلہ ہے جس کی گہرائیوں تک پہنچنے سے مارکسیت قاصر ہے اور ہم اسے بیان کرنا چاہتے ہیں۔
فکر اور ماکسیت
مارکسیت کی تاریخ مادیت میں سب سے اہم اور خطرناک موقف وہ ہے جہاں اس نے فکر اور اقتصاد میں رابطہ قائم کرکے یہ فیصلہ کیاہے کہ انسانی فکر کسی قدربلند کیوں نہ ہوجائے۔وہ اپنی بنیادی طاقت سے الگ ہوکر کسی قدرتلون وتنوع کیوں نہ پیداکرلے آخر کار اسے اقتصادی حالات کا نتیجہ ہی کہاجائے گا اور اس کی پیدائش کو انہیں کیفیات کی طرف منسوب کیاجائے گا۔
ظاہر ہے کہ یہ بحث ایک طویل فلسفی اور تجرباتی گفتگوکی طالب ہے اس لئے کہ اس کے اثرات فلسفہ وتاریخ دونوں پر پڑتے ہیں اور ہم نے اسی ضررت کا احساس کرتے ہوئے اپنی سابقہ کتاب''ہمارافلسفہ''میں اس مطلب کوپوری وضاحت کے ساتھ بیان کیاہے اور اب چند قسم کے افکار پر مزید روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ہماری گفتگو کا تعلق صرف دینی، فلسفی، تجربیاتی اور اجتماعی افکار سے ہوگالیکن ان تفصیلات سے پہلے آپ کو انگلز کی ایک عبارت سنادیناچاہتے ہیں کہ جو اس نے فرانز مہرنج کے خط میںلکھی تھی وہ یہ لکھتاہے کہ:
فکری عمل وہ ہے جسے مفکراپنے فکر وشعور کی بناپر انجام دیتاہے اور وہ اس لئے باطل ہوتاہے کہ اسے اس کے صحیح علل واسباب سے واقفیت نہیں ہوتی ورنہ اگرایسا ہوتاتو وہ عمل فکری نہ کہاجاتا۔فکری عمل میں ظاہری اور سطحی اسباب پر نظرکی جاتی ہے اور مادراء فکر حقیقی افکار سے غفلت برتی جاتی ہے۔
(تفسیر اشتراکی تاریخ ،ص122)
انگلز نے اپنے بیان میں تمام مفکرین کو جاہل ثابت کرنا چاہاہے صرف اس لئے کہ ان کا عمل فکری ہوتاہے اور وہ ان اسباب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جہاں تک تاریخی مادیت کی رسائی ہوگئی ہے۔
ہم اس مقام پر انگلز سے صرف یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر عمل کے فکری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسباب نامعلوم ہوں تو جناب کو یہ معجزہ کیسے حاصل ہوگیاکہ آپ کے افکار بھی باقی رہے اور آپ کو صحیح اسباب بھی معلوم ہوگئے؟خیراب آپ ان تفصیلات کی طرف توجہ فرمائیں۔
دین
افکار کی سرزمین پر دین نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں وہ کسی باعقل وشعور انسان سے مخفی نہیں ہیں۔
دین نے انسان کی عقلی زندگی کی تنظیم میں بڑانمایاں حصہ لیاہے اور خود بھی مختلف ادوار تاریخ کے اعتبار سے مختلف رنگ اختیار کرتارہاہے۔
افسوس کہ مارکسیت نے اپنی مادیت کے تحفظ کے لئے اس کے جملہ حقائق وحی، نبوت صانع وغیرہ سب کا انکار کر دیا اور مادی حلقوں میں یہ بات مشہور ہوگئی کہ دین انسان کی کمزوری اور اس کے احساس کمتری کا نتیجہ ہے۔اس کا خیال انسان کے ذہن میں اس وقت پیداہوتاہے جب وہ طبیعی قوتوں کے مقابلہ سے عاجز ہوجاتاہے۔
مارکسیت نے دیکھاکہ یہ شہرت اس کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ نہیں ہے لہٰذا اس نے ایسی توجیہ کی فکر شروع کر دی جو تاریخی مادیت پر منطبق ہوسکے کو نستانیتوف لکھتاہے:
لینن کی مارکسیت ہمیشہ تاریخی مادیت کے افکار کو مسنح کردینے والے عناصر کی مخالف رہی ہے۔یہی وجہ ہے کہ اس نے سیاسی حقوقی، اجتماعی اور دینی افکار کا سرچشمہ اقتصادی حالات کو قرار دیاہے۔ (دور الافکار التقدمیہ،ص40)
مارکسیت نے جب دین کی نشود نما کے بارے میں اپنے نظریات کو منطبق کرنے کی فکر شروع کی تواسے طبقاتی نزاع کا سہارا لینا پڑااور اسی کے بھروسے پر اس نے یہ اعلان کردیاکہ دین معاشرہ کے مظلوم طبقہ کی مایوس ذہنیت کا نتیجہ ہے جس سے وہ اپنادل بہلایا کرتاہے مارکس کا کہنا ہے کہ:
دینی افلاس درحقیقت واقعی افلاس کا آئینہ دار ہے۔دین رنجیدہ محزون انسان کی آہ ہے۔دین عالم بے روح کی روح اور مفکر بے شعور کی فکر ہے،دین اقوام عالم کے لئے ایک افیون ہے،اس آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی وادی کی اصلاح کا پہلا قدم دین کی تنقید ہے۔ (مارل مارکس،ص16،17)
مارکسیت کے بیانات اگرچہ اس نقطہ پر متفق ہیں کہ دین طبقاتی نزاع کا نتیجہ ہوتاہے لیکن اس کے بعد ایک اختلاف بھی شروع ہوتاہے جس میں بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دین وہ افیون ہے جسے حاکم طبقہ محکوم طبقہ کو استعمال کراتاہے تاکہ وہ اپنے مطالبات سے غافل ہوکر اس کے ہر تقاضے پر لبیک کہتارہے گویاکہ یہ محکوم طبقہ کو اپنے اغراض ومصالح میں گرفتار کرنے کا ایک بہترین جال ہے جسے اسی مقصد کے لئے تیار کیاجاتاہے۔
مارکسیت کے ان پرستاروں نے یہ بیان دیتے ہوئے تاریخ سے اس طرح منہ موڑلیاجیسے انہیں اس سے کوئی لگاؤ ہی نہ تھا ورنہ اگر وہ تاریخ کے صفحات کا سرسری مطالعہ بھی کرتے تو انہیں معلوم ہوجاتاکہ دین غالباً فقراء ومساکین اور کمزور طبقہ کے افراد کی آغوش میں پلا ہے۔اس کی شعاعیں کا شانۂ فقر کے دماغوں سے پھوٹی ہیں ۔مسیحیت کے افکار قصررومان تک انہیں مرسلین نے پہنچائے ہیں۔جن کے پاس اس روحانی شعلہ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا جو ان کے سینے میں بھڑک رہاتھا۔صدر اول میں اسلام کی پرورش گاہ مکہ کے فقراء ومساکین کے علاوہ کس کا دل ودماغ تھا؟کیا ان حقائق کے باوجود دین کو حاکم طبقہ کا جال قرار دینا تاریخ سے جہالت نہیں ہے۔
مارکسیت کے دیگر پرستاروں نے دین کو مظلوم ومجبورطبقہ کی آہ قراردیاہے ۔ان کا خیال ہے کہ دین کو مظلوم وعاجز انسان اپنی تسلی کا ایک وسیلہ سمجھ کر اپناتاہے اور پھر اسی سے اپنی فقیرانہ ذہنیت کو تسکین دیتاہے۔
اس نظریہ کا جواب دینے کے لئے پہلے ایک عام بات پر توجہ دینا زیادہ مناسب
ہے او روہ یہ کہ حسن اتفاق سے دین ان معاشروں میں بھی رائج رہاہے جنہیں مارکسیت نے اپنے آنے والے دور کا نمونہ قرار دیاہے اور یہ بتایاہے کہ تاریخ کے یہ ادوار طبقاتی نزاع سے مبراتھے۔سوال یہ پیداہوتاہے کہ اگر ان لاطبقاتی ادوار میں دین کا وجود مختلف اشکال میں ثابت ہوجاتاہے تو پھراسے طبقاتی نزاع کا نتیجہ قرار دینا کہاں تک درست رہتاہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے خیال کے مطابق دین کو ضعیفوں او ر مظلوموں کی تسکین کا سہارا مان لیاجائے تو پھراسے کسی ایسے معاشرہ میں نہ ہونا چاہئے جہاں افلاس وتنگ دستی نہ ہو اور کسی ایسے انسان کو اختیار نہ کرناچاہئے جو مادی ثروت کے اعتبار سے بلندو بالا درجہ پر فائز ہو۔حالانکہ مارکسیت اس حدتک ہمارا ساتھ ضروردے گی کہ یہ دین ان دماغوں میں بھی رہ چکاہے اور رہتاہے جن میں اس کی خاطر ساری ثروت قربان کردینے کا جذبہ ہوتاہے اور ان میں اقتصادی حیثیت سے کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی۔
کیا اس کے بعد آپ یہ تسلیم نہ کریں گے کہ دین ایک زندہ عقیدہ اور محکم نظام ہے جسے ثروتمند عقلیت نے بھی پسند کیاہے اور فقیر ذہنیت نے بھی اور دونوں نے ہی اپنے قلب وجگر میں جگہ دی ہے۔
مارکسیت کی ایک زیادتی یہ بھی ہے کہ اس نے اقتصادیات کو فقط دین کی نشوونما کا منشاء قرار نہیں دیابلکہ دین کے جملہ تغیرات کو اقتصادیات کا ممنون کرم قرار دے دیاہے اس کا خیال یہ ہے کہ تاریخی ادیان میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں ایک قومی خدابنالیتی تھیںاور جب وہ حکومت ترقی کرکے ایک عالمی حکومت میں منضم ہوجاتی تھی تو اس کا خدا بھی عالمی ہو جایاکرتا تھا۔
اس کی واضح مثال مسیحیت کی تحریک ہے کہ وہ رومان میں پیداہوئی لیکن اپنی پیدائش کے 250برس بعد ایک حکومتی مذہب کی شکل اختیار کر گئی پھر اس نے جاگیردارانہ صورت بدلی اور پھر جب سرمایہ داری سے ٹکرائی تو پروٹسٹانٹ ازم تحریک وجود میں آگئی۔
(لارڈفیج فیور باخ،ص103تا105)
ہماراخیال ہے کہ اگر مارکسیت کے نظریہ کے مطابق مسیحیت یاپروٹسٹانیٹ کا تعلق مادی اغراض سے ہوتاتوا س کی نشوونمارومانی حکومت میں ہوتی جو اس وقت عالمی قیادت کی حامل تھی اورپھر اصلاحی تحریک بھی سرمایہ پرست جماعت کے علاوہ کسی اور معاشرہ سے اٹھتی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
مسیحیت رومانی حکومت سے بہت دورایک مشرقی اقلیم میں پیداہوئی جو رومان کا استعماری علاقہ تھا اور پھر اس کی تربیت بھی ایک یہودی اور فقیر قوم میں ہوئی جس کی نظرمیں رومانی قائد( PAMPAY )کی پیدائش سے6 صدی قبل کے استعمار کے بعد سے قومی استقلال کے علاوہ اور کوئی شے نہ تھی۔
اس نے اسی کی خاطر انقلاب برپاکئے تھے اور اسی کے لئے جانیں قربان کی تھیں اور لطف یہ ہے کہ اسی فقیرانہ دین کو آخرکار جابرحکومت نے بھی تسلیم کرلیا۔
یہی حال یورپ کو دینی اصلاحی تحریک کا ہے جسے یورپ میں آزادی کے نمائندوں نے اٹھایاتھا اور اس کا کوئی تعلق سرمایہ پرست افراد سے نہ تھا۔یہ اور بات ہے کہ اس تحریک سے اس طبقہ نے بھی فائدہ اٹھایالیکن اس کا یہ مطلب ہرگزنہیں ہے کہ اس تحریک کا بنیادی تعلق اس طبقہ سے تھاورنہ اگر ایسا ہوتاتو اس تحریک کے لئے یورپ کے تمام شہروں سے بہتر انگلینڈہوتاجہاں کی بورژوادیت دیگر شہروں سے بہتر تھی اس لئے کہ 1215ء کے بعد کے انقلاب کے باعث اس شہر کی حالت بڑی حدتک اچھی ہوگئی تھی لیکن اس کے باوجود لوتھر( M.LUTHEIR ) انگلینڈ سے ظاہر نہیں ہوتابلکہ اس سے بہت دور جرمنی میںاپنی تبلیغ کرتاہے جس طرح کہ کالون( CALWN ) فرانس میں اپنی تحریک چلارہاتھا۔
جس کے نتیجہ میں کیتھولک اور پروٹسٹانیتٹ کی جنگیں ظہور میں آئیں اور آخر کار ولیم ادرنج نے اپنے بہادر لشکر کے ذریعہ اس طوفان کو روکا، یہ درست ہے کہ انگلینڈنے بھی
پروٹسٹنٹ تحریک کو اپنالیاتھالیکن اس کی نشودونما کو انگلینڈ سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ اس کی نشوو نما جاگیردار ممالک میں ہوئی تھی۔
اگرمارکسیت کے اس نظریۂ ارتقاء کو عالم کے تیسرے عظیم المرتبت دین اسلام پر منطبق کیاجائے تو نظریہ وانطباق کااختلاف اور بھی نمایاں طور پر سامنے آجائے گا اس لئے کہ یورپ کی عالمی حکومت اگر ایک عالمی خدا کی طالب ہوسکتی ہے تو جزیرة العرب میں توکوئی عالمی حکومت نہ تھی وہاں تو طوائف الملو کی کادور دورہ تھا وہاں تو ہر قوم ایک جداگانہ خدا کی پرستار تھی۔
آخر اس پس افتادہ ملک میں ایک رب العالمین کا تصور کیسے پیداہوگیا؟اگر خدائی کا تصور قومیت سے ملکیت اور ملکیت سے عالمیت کی طرف منتقل ہوتاہے تو پھرسوال یہ پیداہوتاہے کہ جزیرة العرب میں اس تصورنے قومیت سے عالمیت کارخ کیونکر اختیار کرلیااور مختلف خداؤں کے پرستار توحید کے پلیٹ فارم پر کس طرح جمع ہوگئے۔
ب:فلسفہ
مارکسیت کا خیال ہے کہ فلسفی افکار بھی اپنے اقتصادی اور مادی حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں جیساکہ( CAUSTRNTINOFE )لکھتاہے:
وہ قوانین جو ہر اجتماع کی تنظیم میں شریک ہوتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اشتراکی معاشرہ کے لئے ضروری ہیں۔ان میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اجتماعی ادراک اجتماعی حالات کا تابع ہوتاہے۔چنانچہ انسان کے تمام اجتماعی سیاسی،حقوقی اور فلسفی افکار اس کے مادی حالات کے ذہنی انعکاس اور
پرتوہیں۔(دورالافکار المتقدمیہ فی تطویر المجتمع،ص8)
ہم جس طرح فکر واقتصاد کے ارتباط کے بالکلیہ منکر نہیں ہیں۔اسی طرح ایک فکری نظام کے بھی قائل ہیں جو قانون علیت کی بناپر اپنے خاص اسباب کے سہارے چل رہاہے یہاں( IDEALOGE )عمل اپنے علل واسباب سے اسی طرح مربوط ہوتاہے جیسے کہ ہر معلول اپنی علت کے ساتھ لیکن کلام صرف اس بات میں ہے کہ اس فکری نظام کے علل واسباب کیاہیں؟
مارکسیت کی نظرمیں اس کے اسباب اقتصادیات ہیں اور اس کے علاوہ کسی شے میںعلت بننے کی صلاحیت نہیں ہے اور ہماری رائے اس سے بالکل مختلف ہے۔ہم مارکسیت کے اس خیال کو اس کے قول کے مطابق تاریخ پر منطبق کرکے دیکھتے ہیں تو ہمیں عجیب منظرنظرآتاہے۔یہی مارکسیت کبھی ان افکار کو پیداواری قوتوں کا نتیجہ قرار دیتی ہے اور کبھی طبیعی علوم کا،کبھی اقتصادی حالات کا انعکاس کہتی ہے اور کبھی طبقاتی نزاع کا۔ایک برطانوی فلسفی مورلیس کا نفورث لکھتاہے کہ:
قابل ملاحظہ یہ شیء ہے کہ ٹکنیکل ایجادات اور علمی اکتشافات نے فلسفی افکار کے ظہور میں کس قدر حصہ لیاہے۔ (المادیة الدیا للتکیہ،ص40)
اس فلسفی کا مقصد یہ ہے کہ فلسفی افکار کو پیداوار کا نتیجہ قراردے کر تاریخی اعتبار سے دونوں کے تکامل میں ایک توازن قائم کرے اور یہ ثابت کرے کہ فلسفہ ہمیشہ اقتصادیات کے ساتھ چلتاہے۔چنانچہ وہ خود بیان کرتاہے:
انقلابی مفہوم اور ذاتی تغیر وتطور کا تصوراٹھارہویں صدی کے صنعتی کاروبار کے ساتھ ترقی کررہاتھا اور یہ اتفاقی حادثہ نہ تھا بلکہ ان میں ایک علیت قائم تھی اور وہ اس طرح کہ بورژوایت پروسائل پیداوار کے مسلسل انقلابات نے اجتماع میں تغیر کا مفہوم ظاہر کیا اور اسی سے فلسفہ نے اپنے یہاں ذاتی تغیر کا مفہوم پیداکرلیاگویاکہ یہ فلسفہ کسی عملی انکشاف کا تابع نہ تھا بلکہ پورے معاشرہ
میں تغیر وتبدل کا نتیجہ تھا۔ (المادیة الدیاللتکیہ،ص908)
مقصد یہ ہے کہ وسائل پیداوار ارتقاء وتکامل کی راہیں طے کرتے ہوئے فلاسفہ کے ذہنوں میں تغیر وتطور کے مفاہیم پیداکرتے چلے گئے اور اس طرح وہ قدیم فلسفہ کو برباد کرکے نئے افکار کی بنیادیں ڈالتے رہے لیکن مشکل یہ ہے یہ تمام پیداواری انقلابات تو بقول اس فلسفی کے اٹھارہویں صدی کے آخر میں رونماہوئے ہیں۔جبکہ 1764ء میں بخاری آلات نے ایجاد ہوکر پیداوار میں ایک عظیم تغیر پیداکر دیاتھا حالانکہ ذاتی تغیر کا خیال فلسفہ مادیت کے امام دیدورٹ کے ذہن میں آچکاتھااور یہ اٹھارہویں صدی کے ابتدائی حصہ کا فلسفی ہے۔اس کی ولادت 1713ء میں ہوئی اور وفات 1784ء میں اور اس نے اپنے مادی بیانات 1745ء میں نشر کئے۔
اس کا واضح نظریہ یہ تھاکہ مادہ خود بخود متغیر ہوتاہے۔جاندار پہلے ایک خلیہ کی شکل میں ہوتاہے پھر بقدر ضرورت اعضابنتے ہیں پھر اعضاسے ضرورت پیداہوتی ہے اور اسی طرح ایک مسلسل نظام قائم رہتاہے۔
کیاایسے افکار کو ان پیداواری ترقیوں کا تابع قرار دیاجاسکتاہے جو اس وقت تک عالم وجود میں نہ آئی تھیں؟
یہ صحیح ہے کہ اگریہ مادی انقلابات نہ ہوتے تولوگ اس خالص فلسفی نظریہ کو آسانی سے قبول نہ کرتے اور اس کے ظاہر ہوجانے سے بآسانی قبول کرنے لگے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فکر ان حالات سے پیداہوئی ہے اس لئے کہ اس کا وجود تاریخی اعتبار سے ان انقلابات پر مقدم تھا۔
اس کے علاوہ یونانی فیلسوف انکسمندر(ولادت 610 وفات 547 )کو دیکھ لیجئے کہ وہ ان تغیرات کا اسی طرح قائل تھاجس طرح آج کے مادی پرست لوگ قائل ہیں حالانکہ اس کی تاریخ مسیح سے چھ سو سال قبل کی ہے۔اس کا نظریہ یہ تھاکہ کائنات اول دور
میں بہت پست تھی اس کے بعد اس نے ترقی شروع کی اور اپنے داخلی عوامل کی بناپر اپنے حالات سازگارکرنے لگی۔چنانچہ انسان پہلے ایک دریائی جانور تھا۔جب پانی کم ہواتو وہ خارجی زندگی کا عادی بنااور اس طرح حسب ضرورت اعضا پیداکرے انسان بن گیا۔
ایک دوسرے فلسفی کے حالات ملاحظہ کیجئے جسے مارکسیت مادی کا شارع اعظم تصور کرتی ہے اور وہ ہے ہرقلیطس(2ولادت 540 ق،م وفات475 ق،م)یہ شخص میلادسے پانچ صدی قبل پیداہواتھا اور اس نے اپنے فلسفہ کی پوری عمارت اسی ذاتی تغیر کی بنیاد پر قائم کی تھی۔ اس کی نظرمیں کائنات جدلی قوانین کی تابع ہے۔اس لئے ہر شیء آن واحد میں موجود بھی ہے اور غیر موجود بھی۔
اگرچہ یہ شخص اپنے زمانہ میں نہایت ہی پست طبقہ کا فلسفی تھا اس کا خیال تھاکہ آفتاب کا قطرہ ایک قدم کے برابر ہے اور وہ شام کو پانی میں ڈوب جاتاہے لیکن اس کے باوجود اس کا نظریۂ تغیر مارکسیت کے انطباق کے لئے کافی ہے۔اس لئے کہ اس نے یہ نظریہ اس وقت اختیار کیاتھا جب وسائل پیداوار انتہائی انحطاط کی منزل میں تھے اورآج کے وسائل کا تصور بھی نہ تھا۔
قدیم تاریخ سے قطع نظراگر آپ آج کی قریب العہد تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگاکہ آج سے دو صدی قبل ستر ہویں صدی میں اسلامی فیلسوف حضرت صدرالدین الشیرازی نے بھی نظریہ تطور کو اختیار کرکے حرکت جوہری پر ٹھوس دلائل وبراہین قائم کئے تھے۔حالانکہ ان کے دور میں پیداوار کے آلات اپنی قدیم حالت پر باقی تھے اور اجتماعی زندگی سکون وجمود کی منزل سے گزررہی تھی۔یہ حالات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ان افکار کو ان وسائل وآلات سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا ایک مستقل نظام ہے جن کی بناپر یہ اپناکام کررہے ہیں۔
اس مقام پر ایک یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر مارکسیت اپنے قول میں سچی
ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتاکہ اقتصادیات اور فلسفہ دونوں کی رفتار مساوی ہواور جدید افکار صرف اس ماحول میں پیداہوں جہاں کے اقتصادی حالات اچھے ہوں حالانکہ تاریخ اس کے بالکل برخلاف ہے۔
آپ یورپ ہی کو دیکھ لیجئے کہ جس وقت یورپ کے افق پرفکری انقلاب کی کرنیں پھوٹی تھیں اس وقت انگلینڈ اقتصادی اعتبار سے بہت اچھاجارہاتھا، فرانس وجرمن تک اس سے پیچھے تھے۔سیاسی حالات ترقی یافتہ تھے۔بورژوایت آگے بڑھ رہی تھی۔اجتماعی حالات ہر اعتبار سے بہتر تھے اور انگلینڈ ترقی کے آخری زینہ پر تھا جس کا مارکسی ثبوت یہ ہے کہ وہاں پہلا انقلاب 1215 ء میں ہوااور دوسرا عظیم انقلاب کرمویل کے ہاتھوں 1648ء میں ہوگیاجبکہ فرانس میں انقلاب کی قوت 1789ء میں آئی اور جرمن کو یہ نعمت 1848ء میں نصیب ہوئی۔
کیا یہ حالات مارکسی نظریہ کی بناپر اس بات کے مقتضی نہیں تھے کہ فلسفہ کے تمام جدید افکار انگلینڈ سے ظاہرہوں اس لئے کہ افکار اقتصادیات سے پیداہوتے ہیںاور اقتصادکی ترقی کی محکم دلیل انقلاب ہے۔چنانچہ مارکس نے بھی آنکھ بندکرکے یہ فیصلہ کر دیاکہ مادیت انگلینڈ میں فرانسس بیکون اور اسمین کے ہاتھوں میں پیداہوئی ہے۔
(التفسیر الاشتراکی للتاریخ،ص76)
لیکن صاحبان بصیرت جانتے ہیں کہ بیکون مادی فیلسوف نہ تھا بلکہ وہ مثالیت کا پرستار تھایہ اور بات ہے کہ وہ تجربہ کی اہمیت کا قائل تھا لیکن اسے مادیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہی حال اسمین کا ہے اس لئے کہ اگر اسمیت کو مادیت کی اصل مان لیاجائے تو اس قسم کے ارشادات توچودہویں صدی کے دومفکر (دوران دی سان پورسان)اور(پیرا در یول)کے کلام میں بھی پائے جاتے ہیں بلکہ اس قسم کا مواد اسمیت سے پہلے لاتینی رشویت
میں بھی ملتاہے جو فرانس میں تیرہویں صدی میں ظاہر ہوئی تھی اور اس کا اتباع پیرس یونیورسٹی کے اکثر پروفیسروں نے کیا تھا جس کے نتیجہ میں دین کو فلسفہ سے الگ تصور کرلیا گیاتھا۔
اگرچہ انگلینڈ میں مادیت کی ابتداء ہوبز( HOBBES )جیسے لوگوں سے ہوگئی تھی لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے فلسفہ کے میدان پر قابو نہ پایاتھا اور یہی وجہ تھی کہ جب فرانس ولٹیر( YOLTAIR )اور''دیدورڈ''جیسے مادی فلاسفہ کی تخلیق کررہاتھا اس وقت انگلینڈ برکلے اور دویڈہیوم ( DHUME ) جیسے مثالیت پرست فلاسفہ پیداکررہاتھا اور اس طرح نتائج مارکسیت کی توقع کے خلاف برآمد ہورہے تھے جو معاشرہ اقتصادیات میں آگے تھا اس میں مثالیت کا دوردورہ تھا اور جومعاشرہ معاشیات کی پست منزلوں میں تھا اس میں مادیت کی ترقی یافتہ فکر رینگ رہی تھی بلکہ اس سلسلے میں تو یہاں تک کہا جاسکتاہے کہ خود جدلیت کا مفہوم جرمنی میں انگلینڈ سے پہلے پیداہوچکا تھا حالانکہ اقتصادیات میں وہ انگلینڈ سے کافی پیچھے تھا۔کیا ان حالات کے باوجود مارکسیت کے نظریہ کی تائید کی جاسکتی ہے۔
بہت ممکن ہے کہ مارکسیت ان حالات کو استثنائی حیثیت دے دے اور پھر اپنے قاعدہ کے استحکام کا دعویٰ کرے لیکن اس وقت اتنا توضرور ہی کہاجائے گا کہ استثناء قانون کے ثابت ہونے کے بعد کی منزل ہے اور یہاںقانون کا ثابت ہوجانا ہی محل کلام ہے اس لئے کہ اس سلسلہ میں تاریخ نے کسی منزل پر مکمل تائیدوتصدیق نہیں کی۔
فلسفہ اور طبیعی علوم
یہ واضح کیاجاچکاہے کہ مارکسیت نے فلسفی افکار کی پیدائش کے بارے میں مختلف توجہیں کی ہیں۔ کبھی انہیں اقتصادیات کا نتیجہ قرار دیاہے اور کبھی طبیعی علوم کا، اقتصادیات کے بارے میں مفصل بحث ابھی ابھی تمام ہوچکی ہے، طبیعی علوم سے ارتباط کی مکمل گفتگو ''حصہ فلسفہ''میں کی جاچکی ہے لیکن اس کتاب میں بھی بطور اشارہ اتنا کہاجاسکتا ہے کہ فلسفہ اور طبیعی علوم میں کوئی ضروری ارتباط نہیں ہے۔اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی تاریخی رفتار میں تفاوت پیداہوجاتاہے۔کبھی فلسفہ آگے بڑھ جاتاہے اور کبھی طبیعات۔
اس سلسلہ میں ایک واضح مثال ذرہ کی تشریح ہے کہ اس نظریہ کو دیمقراطیس(یہ فیلسوف 470 ق، میں ابدایرا میں پیدا ہوا۔اپنی نظرمیں بہت بڑاسیاح مہندس اور صاحب نظرتھا۔ اجسام ونفوس کو ذرات سے مرکب سمجھتاتھا۔یہ ذرات اس کی نظرمیں قدیم بالذات تھے اور چونکہ خلامحال تھا اس لئے ان کے لئے حرکت بھی محال تھی۔اس لئے حرکت ایک خالی مکان کی محتاج ہے۔351 ق،م میں اس دنیا سے رخصت ہوگیا۔) نے ایجاد کیا اور اکثر مکاتیب خیال نے قبول بھی کیالیکن اس کی حیثیت صرف فلسفی تھی۔اس پر تجرباتی استدلال نہ ہوسکا تھا یہاں تک کہ 1805ء میں ڈالٹن( DALTAN ) نے کیمیا کے سلسلہ میںاس کی تحقیق کی اور یہ نظریہ فلسفی حیثیت سے نکل کر تجرباتی حدود میں آگیا۔
فلسفہ اور طبقاتی نزاع
فلسفی افکار کی پیدائش کے سلسلہ میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ افکار طبقاتی نزاع کا نتیجہ ہوتے ہیں۔چنانچہ ہر فلسفی ایک خاص طبقہ کی حمایت کرتاہے اور اسی کے مصالح کا تحفظ کرتاہے مدرس کا نفورس کا کہنا ہے کہ:
فلسفہ ہمیشہ طبقاتی انداز کو بیان کرتاہے۔یہی وجہ ہے کہ ہر فلسفی خاص طبقہ کے مقاصد کی تعبیر کرتاہے۔وہ یاتوممتاز طبقہ کا ترجمان ہوتاہے یا کسی طبقہ کو ممتاز بنانے کا خواہاں۔ (مادیت دیالکٹیک،ص32)
مارکسیت اس مسئلہ کو اسی طرح مجمل نہیں چھوڑنا چاہتی بلکہ اس کی توضیح یوں کرتی ہے کہ:
مثالیت یعنی غیرمادی فلسفہ حاکم طبقہ کی حمایت کرکے اس کی بقاکے اسباب مہیاکرتاہے اور مادی فلسفہ اس کے خلاف مظلوم طبقہ کی حمایت کرکے ڈیموکریسی اور قومی حکومت کی امداد کرتاہے۔(دراسات فی المجمتع،ص81)
مارکسیت نے اس مقام پر انسانی علم ومعرفت کے دوشعبوں کو اس طرح مخلوط و مشتبہ بنادیاہے کہ اب ان کے درمیان امتیاز قائم کرنا انتہائی دشوار گذار مسئلہ ہوگیاہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ عالم وجود میں مطلق اور غیر متغیر قسم کے حقائق کا قائل ہوجانا اس بات کا مقتضی ہے کہ اجتماعیات میں بھی ایسے ہی نظریات کی پابندی کی جائے اور چونکہ مثالیت عالم وجود میں ایسے مطلق افکار کی قائل ہے۔لہٰذا اجتماعیات میں بھی وہ حاکم نظام کو مطلق اور غیر متغیر سمجھ کر ہمیشہ اس کی حمایت کرے گی۔
حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ارسطوجو الہیات کا رئیس اول ہے۔ وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ صحیح حکومت حالات کے اعتبار سے ہمیشہ بدلتی رہے گی۔یعنی
خدا کا مطلق مفہوم اس بات کا متقضی ہے کہ حکومت کا مفہوم بھی مطلق ہو۔
ہم نے اس بحث کی تفصیل کو''حصہ فلسفہ''سے متعلق کر دیاہے اور وہاں اس بات کا جائزہ لیاہے کہ فلسفہ کی یہ طبقاتی توجیہ تاریخی حیثیت سے کہاں تک صحیح ہے یہاں تو صرف دومادی فلسفیوں کے افکار کا تجربہ کرنا ہے تاکہ اس کی روشنی میں مارکسیت کی صداقت کا اندازہ ہو سکے اور وہ دونوں فلسفی ہیں۔ہر قلیطس(یہ شخص 540 ق،م میں پیدا ہوا اور 475 ق،م میں چل بسا اور مختصر تعارف اس کتاب میں موجود ہے۔) اور ہوبز۔
ہر قلیطس اس قومی روح سے بہت دور تھا جسے مارکسیت اس کے لئے لازم قرار دیتی ہے وہ شہر کے حکمران اور شریف خاندان سے تھا اور آخر امر میں قسمت سے خودبھی حاکم شہر ہوگیا تھا وہ اپنی فطرت سے مجبور ہوکر حاکمانہ تصرفات کیاکرتاتھا۔قوم کی توہین اس کا خاس مشغلہ تھاوہ یہ کہاکرتاتھاکہ عوام ان جانوروں کا نام ہے جو گھاس کو سونے پر مقدم کرتے ہیں یایہ وہ کتے ہیں جو ہر ایک کو دیکھ بھونکنے لگتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ اس جدلی مادیت کی ہر توجیہ ممکن ہے لیکن اسے ڈیموکریسی اور قومیت کا آئینہ دار قرار دینا بالکل غلط اور مہمل ہے۔
اس کے برخلاف یونان میں مثالیت پرست مفکرافلاطون ایسے فکری انقلابات برپا کررہاتھا جس کی شکل بالکل اشتراکی تھی۔وہ شخصی ملکیت کی بھی شدت سے مخالفت کیاکرتا تھا۔ تو کیا ان حالات میں اشتراکیت کو مثالیت کا متضاد عنصر قرار دیا جاسکتاہے۔
بالکل یہی حال ہوبز کا تھا۔یہ ڈیکارٹ کے مقابلہ میں مادیت کا علمبردار تھا۔ ابتداء میں انگلینڈ کے ایک امیر کا استاد تھا جس کو 1660ء میں چارلس دوم کا لقب ملا اور اس نے اپنے خاندانی تعلق کی بناپر کرومویل کے اس قومی انقلاب کا شدید مقابلہ کیاجو اس نے انگریز فوج کے زوربازو پر کیاتھایہاں تک کہ جب ملوکیت کی بنیادیں ہل گئیں اور کرو مویل کے زیر اثر جمہوریت قائم ہوگئی تو ہمارے مادی فلاسفر کو جلاوطن ہوکر فرانس چلاجانا پڑا اور اس
نے وہاں پہنچ کر آزاد ملکیت کی تائید میں کتاب(تنین)تالیف کی جس میں اپنے سیاسی فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے اس امر پر بڑازور دیا کہ قوم سے اس کی آزادی کو سلب کرکے اسے شدید استبداد میں گرفتار کیاجائے۔
حالانکہ اسی ماحول میں الٰہیاتی فلسفہ بالکل اس کا مخالف تھا او رہوبز کا معاصر فلسفی باروخ اسپینوازا( B.SPENOTHA )حکومت کے خلاف قوم کے حقوق کی حمایت کرکے ڈیموکریسی کی دعوت دے رہاتھا اور اس کا نعرہ تھاکہ جس قدر حکومت میں عوام کا ہاتھ ہوگا اسی قدر محبت واتحاد کی فراوانی ہوگی۔
اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ کون سافلسفی قوم کی حمایت کرہاتھااو رکون حاکم وقت طبقہ کا ہم آواز تھا، کون مادی تھا اور کون مثالی۔
اس مقام پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ مارکسیت نے فلسفی افکار کو طبقاتی نزاع کا نتیجہ قرار دے کر اس بات کااعتراف کرلیاہے کہ اب کوئی بحث جذبات ونفسیات سے پاکیزہ نہیں ہوسکتی۔
لہٰذا یہ کیونکر ممکن نہیں کہ ہم مارکسیت کے اس خیال کو بھی کسی طبقہ کی ترجمانی کا نتیجہ قرار دے دیں جب کہ وہ خود بھی پاکیزہ بحث کی شدید مخالف ہے اور اسے بورژدازی مزعومہ خیال کرتی ہے جیساکہ چاغین نے بیان کیاہے:
لینن نے نہایت پامردی کے ساتھ افکار کی پاکیزگی اور بورژائی قسم کی غیرجانب داری کا مقابلہ کیا چنانچہ 1890 ء میں لینن نے مارکسی لوگوں کے اس خیال کا سدباب کر دیا کہ فلسفہ کو پارٹی بندی سے آزادہونا چاہئے اور اس نے اعلان کردیاکہ مارکسی نظریہ کے لئے مزدوروں کی حمایت انتہائی ضروری ہے۔ ہم اگر کسی حادثہ کی صحیح نوعیت معلوم کرنا چاہیں تو ہمارا فرض ہوگاکہ اس پر مزدور طبقہ کے مصالح کے زاویہ سے نظرکریں اس لئے کہ جماعتی روح ہی مزدور طبقہ سے پرولٹیریر یاڈکٹیٹر شپ قائم کراسکتی ہے۔
(الروح الخربیہ فی الفلسفة والعلوم،ص71،72)
خودلینن نے بھی یہی اعلان کیاتھاکہ:
مادیت جماعتی موقف کو فریضہ سمجھتی ہے اس لئے کہ وہ ہر حادثہ میں ایک خاص پارٹی بندی پر مجبور کرتی ہے۔ (حول تاریخ تطور الفلسفہ،ص21)
یہی وجہ تھی کہ جدانوف نے کسندروف کی کتاب پر شدید تنقید کی ہے کہ اس کے مصنف نے غیر جماعتی پہلو پر زور دیاہے۔چنانچہ جدانوف کا کہناہے کہ:
میری نظرمیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولف ''تشرنیشفکی'' کے کلام سے استدلال کرکے یہ ثابت کرنا چاہتاہے کہ فلسفی نظام کے بانیوں پرتساہلی واجب ہے اور چونکہ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کا ہم خیال ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت بندی کا انکار کرتاہے حالانکہ یہی لینن کی مارکسیت کی روح وجان ہے۔
(حول تاریخ تطور الفلسفہ،ص18)
ہم ان عبارتوں کی روشنی میں یہ سوال کرسکتے ہیں کہ مارکسیت کی جماعتی افکار سے کیا مراد ہے؟اور کسی ایک طبقہ کی حمایت کا کیا مقصد ہے؟
اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ فلسفہ کو مزدور طبقہ کے مصالح کامعیار ومقیاس قرار دینا چاہئے خواہ اس کے خلاف ہزارہا دلائل وبراہین کیوں نہ قائم ہوجائیں تو پھر ہمیں مارکس کے جملہ افکار میں شک کرنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ مارکس کا یہ پورا فلسفہ مزدور طبقہ کی حمایت میں تھا اور اسے حقیقت واقع سے کوئی تعلق نہ تھا۔
اگر جماعت بندی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص ایک خاص طبقہ کی طرف منسوب ہوتاہے اور وہ اپنے افکار میں ان ذاتی رجحانات سے جدا نہیں ہوسکتاتو اس کا مطلب یہ ہوگاکہ مارکس اشیاء کی حقیقت کے بارے میں نسبیت کا قائل ہے حالانکہ یہی وہ نکتہ ہے جس کی مارکس نے بارہامخالفت کی ہے۔
شاید آپ کو یاد ہوکہ ہم نے حصۂ فلسفہ میں اس ذاتی نسبیت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے یہ بتایاہے کہ نسبیت کسی واقعہ کی حقیقت کو اس کے خیال سے مطابق ہونے کے معنی میں قرار دیتی ہے۔اس کی نظرمیں واقعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ تمام تراہمیت انسان کے داخلی کیفیات کی ہے لہٰذا ہوسکتاہے کہ ایک ہی چیزکے لئے مختلف افراد کے اذہان کے اعتبار سے مختلف حقیقتیں ہوں۔
مارکس نے اس ذاتی نسبیت کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بیان کیاہے کہ ہر شے کی ایک واقعیت ہوتی ہے اور اسی سے مطابقت کا نام ہے حقیقت۔یہ اور بات ہے کہ عالم کی ہر شے متغیر اور متطور ہے اس لئے حقیقت کبھی ثابت وجامد نہیں رہ سکتی بلکہ حالات کے اعتبار سے بدلتی رہے گی۔
گویاکہ اشیاء عالم میں نسبیت محفوظ ہے لیکن واقعہ کے اعتبار سے نہ کہ افراد واشخاص کے لحاظ سے۔اب اگر مارکس کے اس قول کی تصدیق کردی جائے کہ انسانی ذہن طبقاتی مصالح سے الگ نہیں ہوسکتاتو اس کا کھلاہوا مقصد یہ ہوگاکہ حقیقت''انسانی ذہن '' کے اعتبار سے بدل جائے گی اور واقعہ کا صحیح ادراک غیر ممکن ہوگا۔ہر شخص اپنے مخصوص زاویۂ نگاہ سے دیکھے گا اور اپنے مخصوص نقطۂ نظرسے سوچنے کی کوشش کرے گا اور اس وقت یہ بدگمانی قائم ہوجائے گی کہ مارکسیت حقیقت کا سراغ لگانے سے قاصر ہے۔وہ صرف مزدور طبقہ کے مصالح کی نشاندہی کرسکتی ہے۔
اتنا ضرورہوگاکہ مارکس کی یہ نسبیت اس ذاتی نسبیت سے قدرے مختلف ہوگی جس کاتذکرہ فلسفہ میں کیاگیاہے اس لئے کہ اس نسبیت کا تعلق انسان کے ذاتی کیفیات سے تھا اور اس کا تعلق اس کے طبقاتی رجحانات سے ہے۔
تجربیاتی علوم
ہمارے خیال میں اس مقام پر زیادہ توقف اس لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم نے مارکسیت کی زبانی اب تک ایک ہی نغمہ سناہے جسے وہ تاریخ کے ہر موڑپر گایاکرتی ہے۔
علوم کے بارے میں بھی اس کا یہی خیال ہے کہ یہ مادی اور اقتصادی حالات کا نتیجہ ہیں ان کا تنوع اور ارتقاء بھی ذرائع پیداوار کے رنگارنگ کیفیات کا اثر ہیں۔
اس کا نظریہ یہ ہے کہ اٹھارہویں صدی کے بخاری آلات اس وقت کی سرمایہ دارانہ ضرورتوں کا نتیجہ ہیں۔چنانچہ روجیہ غارودی نے اس مطلب کی صراحت بھی کردی ہے کہ:
ذرائع پیداوار کی ترقی طبیعی علوم کے سامنے مسائل پیش کرتی ہے تاکہ وہ ان میں بحث وفکر کرکے ترقی کریں اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی خیال مختلف علماء کے ذہن میں پیداہوتاہے جیساکہ عمل اور حرارت کے توازن کا نظریہ ہے کہ وہ فرانس میں کارنو، انگلینڈ میں گول اور جرمنی میں مایر کے ذہن میں ایک ہی وقت پیداہواتھا،یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ یہ ذرائع جس طرح مسائل کا اضافہ کرتے ہیں اسی طرح آلات ووسائل مہیاکرکے ان کے حل کرنے کی صورتیں بہم پہنچاتے ہیں گویا کہ یہی ذرائع اول وآخر تجربہ کی بنیاد ہیں۔ (الروح الخربیہ فی العلوم،ص11تا13)
مارکسیت کے اس بیان پر ہمارے ملاحظات درج ذیل ہیں:
الف: دور حاضر کو الگ کرلیاجائے تویہ کہاجاسکتاہے کہ آج سے پہلے دنیا کے تمام معاشرے ذرائع پیداوار کے اعتبار سے ایک ہی منزل میں تھے۔ہر مقام پر معمولی زراعت اور دستکاری کا دور دورہ تھا۔مختلف شکلوں میں کوئی جوہری اور واقعی فرق نہ تھا۔ایسے
حالات میں مارکسی نظریہ کی بناپر تمام ممالک کی علمی رفتار بھی متساوی اور متوازن ہونی چاہئے تھی حالانکہ ایسا ہرگزنہ تھا۔
قرون وسطیٰ میں اندلس، عراق،مصر یورپ سے بالکل مختلف تھے۔ اسلامی ممالک علمی شعاعوں سے منور تھے اور یورپ میں ان کی کوئی کرن نہ تھی۔چین نے طباعت کا کام ایجاد کیاتھا۔ دیگر ممالک محروم تھے مسلمانوںنے آٹھویں صدی عیسوی میں اس فن کو چین سے حاصل کیااور تیر ہویں صدی میں یورپ کے حوالہ کیا۔علوم کی یہ مختلف رفتار اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ذرائع پیداوار سے اس کا کوئی قانونی ارتباط نہیں ہے۔
ب: اس میں شکل نہیں ہے کہ عام طور سے علمی کوششیں مادی ضرورتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ضرورت ہی ایجاد کی ماں ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ضرورت کو تاریخی بنیاد کا درجہ دے دیا جائے اس لئے کہ ہمارے سامنے بہت سی ضرورتیں ایسی ہیں جنہیں ایک مدت درازتک علوم وفنون کی زیارت نہیں ہوسکی اور ایک عرصہ کے بعد ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوسکا۔چنانچہ اس کی ایک واضح مثال ہے عینک۔ انسان نہ جانے کس زمانے سے ضعف بصارت کا شکار تھا اور اسے ایسے آلات کی ضرورت تھی جو اس کمی کو پورا کر سکیں لیکن علم نے اس کا ساتھ نہ دیاتھایہاں تک کہ تیرہویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے روشنی کے الغکاس کا نظریہ ایجاد کرکے ہزاروں قسم کے چشمے بناڈالے ۔ظاہرہے کہ یہ ایجاد وقتی ضرورت کا نتیجہ نہ تھی بلکہ ان علمی ترقیوں کا نتیجہ تھی جو اپنی خاص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھیں۔
اگر ہم یہ تسلیم کرلیں کہ علمی انکشافات کی بنیاد اقتصادی حالات ہی پر قائم ہوتی ہے تو ہمیں یہ سوچناپڑے گا کہ یورپ نے کشتیوں کے واسطے متفاطیسی سوئی کی ایجاد تیرہویں صدی میں کیوں کی جبکہ کشتیوں کے ذریعہ تجارت کا کاروبار مدتوں سے چل
رہاتھا بلکہ رومان کی توپوری تجارت اسی ایک نکتہ پر چل رہی تھی۔
کیا اس کی بناپر یہ نہیں کہا جاسکتاکہ علم کی رفتار اقتصاد سے الگ ہوتی ہے؟جب کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چین نے اس سوئی کا انکشاف یورپ سے دوہزار سال پہلے کرلیا تھا۔
بلکہ اس سے بہتر مثال خود بخاری قوت کی ہے کہ اسے تیرہویں صدی عیسوی میں کشف کرلیاگیاتھا۔یہ اور بات ہے کہ آج کے جیسے آلات ایجاد نہ ہوسکے تھے لیکن ظاہر ہے کہ ہماری بحث صرف علمی انکشاف سے ہے اختراع وایجاد سے ہماراکوئی تعلق نہیں ہے۔
ج: مارکسیت کا یہ دعویٰ کہ طبیعی علوم کے مسائل ذرائع پیداوار کے ذریعہ ہمارے سامنے آتے ہیں ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا مکمل ثبوت بہم پہچاناغیر ممکن ہے اس لئے کہ ان علوم سے متعلق دوچیزیں ہیں:
ایک فنکاری علوم تو ظاہر ہے کہ انہیں ذرائع پیداوار کا تابع کہاجاسکتاہے اس لئے کہ فن ان ذرائع سے پیداہونے والی مشکلات کا علاج کرتاہے۔
دوسرے نظریاتی تجربات! تو ظاہر ہے کہ ان علوم کو پیداوار کے مشاکل سے کوئی ربط نہیں ہے کہ نظریات اور فن کے راستے بالکل مختلف ہیں۔سولہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک نظریات پیداہوتے رہے لیکن ان سے استفادہ کرنے سے قاصر رہا۔یہاں تک کہ 1870ء میں برقی صنعت ایجاد ہوئی اور فنکاری کو نظریات سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔
آپ دیکھیں کہ کیمیا کے بارے میں لافوازیہ نے اٹھارہویں صدی میں کتنے انقلابات برپاکئے اور انہیں کسی نے قبول نہ کیا۔''فنکاری''لوہے اور فولاد کی صنعتیں بھی ایجاد کرتی رہی لیکن سخت ونرم لوہے کے کیمیاوی فرق کے نہ سمجھنے اور کاربون کی
مقدار سے ناواقفیت کی بناپر ان سے مکمل استفادہ نہ کرسکی۔
رہ گیاغارودی کا یہ دعویٰ کہ اگر علمی انکشافات وقتی تقاضوں کے تابع نہ ہوتے تووقت واحد میں ایک نظریہ چند آدمیوں کے ذہن میں نہ پیدا ہوتاتو اس کے بار ے میں صاف سی بات یہ ہے کہ تاریخ اس دعویٰ کی صریحی مخالف ہے۔
اس نے ہمیں یہی بتایاہے کہ نظریات میں اتحاد یا اختلاف انسان کی فکری اور ذہنی صلاحیتوں کے قرب وبعد سے پیداہوتاہے ۔ٹکنیکل حالات سے ان باتوں کا کوئی ربط نہیں ہے۔چنانچہ اس کاواضح ثبوت یہ ہے کہ قیمت کے بارے میں محدودمنافع کے معیار بننے کا نظریہ وقت واحد میں تین افراد نے تین ممالک میں ایجاد کیا۔ حالانکہ یہ قدیم اقتصادیات کے معیار قیمت سے متعلق تھا۔اسے پیداواری مشاکل سے کوئی ربط نہ تھا۔
آپ ملاحظہ کریں 1871ء میں انگلستان میں جیفونر،نمسامیں کارل سنجر اور 1874ء میں سولیرامیں فاراس نے ایک ہی نظریہ ایجاد کرلیاحالانکہ اس کا کوئی ربط ذرائع پیداوار سے نہ تھا۔
معلوم ہوتاہے کہ علم کے گوناگوں انکشافات انسانی صلاحیتوں کے تابع ہیں۔دنیا کے حالات سے ان کا کوئی قانونی ربط نہیں ہے۔
د: طبیعی علوم کا ذرائع پیداوار کے لئے اس طرح تابع ہوناکہ یہی ذرائع علمی مشکلات کے حل تلاش کریں ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی حمایت سے عقل وتاریخ دونوں عاجز ہیں۔
عقل کا کھالا ہوا فیصلہ ہے کہ علوم اگرچہ اپنے ارتقاء وتکامل میں ان آلات کے تابع ہوتے ہیں جن سے علمی مشکلات حل کی جاتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ آلات بھی اسی علم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
یہ صحیح ہے کہ اگر آج خوردبین،دور بین اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہ ہوتے تو بہت سی علمی ترقیاں رک جاتیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف بھی ضروری ہے کہ یہ تام چیزیں بھی علمی ارتقاء کا نتیجہ ہیں اور اسی علمی ترقی نے سترہویں صدی میں روشنی اور اس کے انعکاس سے بحث کرکے خوردبین ایجاد کردی جس پر آج کی ترقی کا تمام تر دارومدار ہے اور ایک نئی دنیا کا وجود وظہور نظر آرہاہے۔
یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ علم کی ساری داستان انہیں ذرائع وآلات ہی میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ بہت سے حقائق ایسے بھی ہیں جن کا انکشاف فکر بشری نے اس وقت کر لیاتھا جب اس انکشاف کے وسائل موجودہ نہ تھے۔انہیں حقائق میں سے ایک خلائی دباؤ ہے جس سے آج سیکڑوں اختراعات عالم وجود میں آگئے ہیں اور اس کا پتہ سترہویں صدی میں تورتشیلی نے اس طرح لگایاتھاکہ پمپ 34 قدم تک پانی کو بلند کرتاہے اور جب پانی اس سے اوپر نہیں جاسکتاتو پارہ کی بلندی تو اور بھی کم ہوگی اس لئے کہ اس کا وزن زیادہ ہوتاہے اور اس طرح رفتہ رفتہ یہ ثابت کردیاکہ خلاء میں ایک دباؤ اور فضامیں ایک تنگی پائی جاتی ہے۔ سوال یہ پیداہوتاہے کہ اس انکشاف میں دیگر علماء نے حصہ کیوں نہیں لیا۔گلیلو نے تو اس موضوع پر گفتگو بھی کی تھی پھر سترہویں صدی سے پہلے اس نے یہ راز کیوں نہ منکشف کر لیا۔کیا انسان کو اس تحقیق ضرورت نہ تھی؟کیا ان چیزوں کا استعمال پہلے نہ تھا؟کیا اس قسم کا تجربہ دیگر علماء کے لئے ممکن نہ تھا۔
حقیقتاً یہ سب کچھ تھا لیکن اسے کیاکیاجائے کہ علم وفکر کی ایک مستقل تاریخ ہے جس کی رفتار انسان کے نفسیاتی اور داخلی کیفیات کے ساتھ رہتی ہے۔اسے نہ ذرائع پیداوار سے کوئی ربط ہے نہ اقتصادی حالات سے۔
مارکسیت میں اس قسم کی بے شمار کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور انہیں میں سے ایک اہم موضوع تھا''اجتماعیت کا اقتصادی حالات سے پیداہونا''لیکن ہم سردست اس نکتہ سے
قطع نظر کرتے ہیں اس لئے کہ اس موضوع پر ہمیں مکمل کتاب تالیف کرنی ہے۔
مارکسی طبقیت
مارکسیت کے افکار میں طبقات کو ایک مرکزی جگہ حاصل ہے اور مارکس نے اسے بھی اجتماعیت سے الگ کرکے اقتصادی رنگ دینے کی فکر کی ہے۔چنانچہ اس کا کہنا ہے کہ طبقات اگرچہ معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں اوربظاہر اقتصادیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتالیکن در حقیقت ان کی پشت پر بھی اقتصادیات ہی کام کرتے ہیں جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ معاشرہ کے بعض افرادذرائع پیداوار کے مالک ہوتے ہیں اور بعض نہیں۔اس طرح مالک طبقہ حاکم کی جگہ لے لیتاہے اور فقیر طبقہ محکوم کی۔اب چاہے اس حکومت کی شکل نوکری کی ہویا غلامی کی۔
ظاہرہے کہ جب مارکسیت نے طبقات کی تشریح ہی اقتصادیات کے نام پر کی ہے تو اب اس سے کسی قسم کی بحث کرنا بیکار ہے لیکن ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے انسانی معاشرہ میں جوطبقات پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد صرف اقتصاد پر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی عوامل رہے ہیں جن کے زیر اثریہ طبقات عالم وجود میں آئے ہیں۔
منطقی اعتبار سے تویہ بھی کہاجاسکتاہے کہ اگر طبقات کا وجود اقتصادیات کی بنیاد پر ہے اور اقتصادیات کا قیام عمل کی سرگرمی پرتو اس نظریہ کے اعتبار سے ہونا یہ چاہئے تھاکہ معاشرہ میں حکومت اسی طبقہ کا حق ہوجو ہمیشہ سرگرم عمل رہے اور عملی نشاط کی منزل میں انتہائی عروج پر ہو۔حالانکہ تاریخ اس کا ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے۔
سرمایہ داری کے بارے میں تو اتنا کہا جاسکتاہے کہ سرمایہ داروں نے اپنا اجتماعی مقام عمل کی سرگرمی اور سعی پیہم سے حاصل کیاتھالیکن اس کے علاوہ دیگر ادوار تاریخ میں یہ تصور انتہائی مہمل ہے۔وہاں تویہ دیکھاگیاہے کہ حکومت کی بناپر طبقات پیداہوگئے ہیں اور طبقات کو معلول کا درجہ دیاگیاہے۔
چنانچہ آپ رومان کو ملاحظہ کریں یہاں اشراف کا طبقہ عوام سے اجتماعی اور سیاسی ہر اعتبار سے ممتاز تھا حالانکہ سرگرمی عمل عوام کا حصہ تھا اور اکثر لوگ تو دولت میں بھی ان اشراف کے ہم پایہ تھے۔
اسی طرح سے جاپان کا سامرائی طبقہ تھا جس کی عظمت جاگیراروں سے کم نہ تھی حالانکہ اس کے پاس سوائے شمشیرزنی اور شہسواری کے کچھ نہ تھا۔
خود ہندوستان کی دو ہزار سال قبل کی تاریخ میں آریوں کے طبقاتی نظام میں رنگ ونسل کے امتیاز کے سوااور کیا تھا۔
پھراسی بلند طبقہ کے دو حصہ ہوئے کشٹریہ اور برہمن، کشٹریہ کے پاس طاقت قوت،فوج واسلحہ اور برہمن کے پاس دین ومذہب،دیانت وعبادت کے علاوہ اور کیا تھا؟
ذرائع پیداوار عوام کے ہاتھوں میں تھے اور حکومت ان مجاہدین یا دینداروں کے ہاتھ میں۔کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جاسکتاہے کہ معاشرہ میں طبقات کی بنیاد اقتصادیات پر قائم ہے۔
اگر آپ یورپ کا جائزہ لیں گے تووہاں بھی جرمانی فتح کے زیر اثر جاگیردارطبقہ کا قیام سیاست وطاقت کے علاوہ کسی اور بنیاد پر نہ ملے گا جیساکہ انگلز نے کہاہے کہ جاگیردار طبقہ پہلے صرف فاتح تھا بعدمیں اسے یہ حیثیت بھی حاصل ہوگئی۔
یعنی انگلز کے اس اعتراف کے مطابق دولت وقوت طبقہ سے حاصل ہوئی ہے نہ کہ طبقہ دولت سے۔
مارکسیت نے اس مقام پر اپنی بات زندہ رکھنے کے لئے ایک نیا شگوفہ چھوڑاہے کہ ذرائع پیداوار اگرچہ طبقاتی نظام کی روح رواں ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتاہے کہ معاشرہ کے دیگر عوامل بھی طبقات کی تشکیل میں حصہ لے لیتے ہیں۔یہ اور بات ہے کہ بنیادی حیثیت صرف ذرائع پیداوار کی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مارکسیت نے اس بات سے اپنا سارا بھرم کھودیاہے اور اس تاویل کی بناپر دیگر نظریات کی ہم رنگ ہوگئی ہے۔یہ اور بات ہے کہ اس نے پیداوار پرزیادہ زوردیاہے ورنہ دوسرے عوامل کی اثراندازی کا بھی اعتراف کر لیاہے۔
اور جب ہم نے یہ واضح کردیاہے کہ مارکسیت کی توجیہ طبقات کے بارے میں خلاف قانون تاریخ ہے تو یہ بھی واضح ہوجاتاہے کہ طبقات کی تشریح اقتصادیات کی بنیاد پر بھی غلط ہے۔ورنہ اس نظریہ کا ایک بھونڈاسا نتیجہ یہ ہوگاکہ تمام کام کرنے والے ایک طبقہ میں شمار ہوں اور تمام ذرائع پیداوار سے استفادہ کرنے والے دوسرے طبقہ میں۔
اور اس کامنظر یہ ہوگاکہ بڑے بڑے ڈاکٹر،انجینئر اور تجار، مزدرو اور کاشتکار سب برابر ہوں اس لئے کہ سب کام کرتے ہیں اور سب کی زندگی اپنے عمل سے بسر ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ بات انتہائی مہمل ہے اور ہمارا اجتماعی فرض ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر اور تجار جیسے افراد کو مزدوروں اور کاشتکاروں سے الگ درجہ میں رکھیں۔
دوسرا بھیانک منظریہ بھی ہے کہ مارکسیت طبقاتی نزاع کو بھی لازم قرار دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگاکہ ایک دن کارخانوں کے مالک، جاگیردار افراد چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں سے مقابلہ کریں گے اور اسی طرح بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر معمولی معمولی کارکن لوگوں سے معارضہ کریں گے تاکہ اس طبقاتی نزاع سے کوئی معقول نتیجہ برآمد ہوسکے اور یہی وہ انقلاب ہوگاجو اجتماعیت کو اقتصادیات سے محفوظ کردینے کے نتیجہ میں پیداہوگا ورنہ اگر دونوں کا حساب الگ رکھاجائے تو اس قسم کی کوئی بات پیدا نہ ہوگی۔
مارکسیت کے اس اختلاط سے دواہم نتائج برآمد ہوتے ہیں:
(1) وہ شخصی ملکیت جس کے خاتمہ کی مارکسیت کوشش کررہی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کے خاتمہ کے بعد طبقاتی نظام ختم ہوجائے گا اور پورا معاشرہ ایک طبقہ کی شکل میں آجائے گا۔اگر ختم بھی ہوجائے گا تو طبقات کا خاتمہ نہ ہوگا اس لئے کہ طبقات کا مسئلہ اقتصادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی اور معاشرتی ہے۔ اس کے اسباب وعوامل کچھ اور ہیں جن کا انفرادی ملکیت کے ساتھ ختم ہوجاناکوئی ضروری امر نہیں ہے۔
(2) معاشرہ میں اگر کبھی طبقاتی نزاع قائم بھی ہوجائے تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد اقتصادیات پر ہواور یہ طے کر لیاجائے کہ طبقاتی نزاع کا سرچشمہ مزدور اور منفعت کے خواہاں افراد کے جذبات کا اختلاف ہے بلکہ اس کے علل واسباب اور بھی ہوسکتے ہیں جنہیں اقتصادی حالات سے کوئی ربط نہ ہوگا۔
مارکسیت اور طبیعی عوامل
مارکسیت کا سب سے بڑاقصور یہ ہے کہ اس نے انسان کے نفسیاتی،حیاتی اور تشریحی خصوصیات کو بالکل نظرانداز کردیاہے اور تاریخی حرکت میں اسے کوئی درجہ نہیں دیاحالانکہ تاریخ خود ہی شاہد ہے کہ اس کے گوناگوں اور رنگارنگ انقلابات میں ذاتی اور طبیعی عوامل وموثرات کو بڑادخل رہاہے۔بھلا کون نہیں جانتاکہ یورپ کی تاریخ میں نپولین کی بہادری کے کارناموں کا بہت بڑاہاتھ ہے؟
کون اس امر سے واقف نہیں ہے کہ پندرہویں لویس کی نرم مزاجی ہی نے
فرانس کو نمسا کا ہم آہنگ بنادیاجب کہ مادام لمبارڈر نے شاہی عزائم پر تسلط حاصل کرکے اسے نمسا کی حمایت پر مجبور کر دیا اور اس کے غیر متوازن نتائج برآمد ہوئے۔
کسے اس بات سے انکار ہے کہ ہنری کے عشق ہی نے انگلینڈ سے کیتھولک مذہب کا خاتمہ کرادیا۔
کسے نہیں معلوم کہ پدری محبت ہی نے معاویہ بن ابی سفیان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ یزید کو عالم اسلام پر مسلط کر دے اور اس طرح اسلامی تاریخ کا رخ مڑ جائے۔
کیاکوئی شخص یہ کہہ سکتاہے کہ اگر نپولین کی بہادی،لویس کی نرم مزاجی، ہنری کا عشق اور معاویہ کی محبت نہ ہوتی تو تاریخ کا یہی رخ ہوتا جس رخ پر اب تک چلی آرہی ہے اور جس دھارے پر ان باطنی حالات نے اسے لگادیاہے۔
آپ تاریخ دیکھیں تومعلوم ہوگاکہ اگر رومان کے طبیعی حالات عین وقت پر ایک وباکاباعث نہ بن گئے ہوتے،اگر ایک مقدونی سپاہی نے اسکندر کو بچانہ لیاہوتا اور اس کے ہاتھ قطع ہوگئے ہوتے تو آج تاریخ کا یہ عالم ہرگز نہ ہوتاجو ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔
اور جب یہ بات مسلم ہے کہ انسان کے داخلی کیفیات بھی عالمی تاریخی پر اثرانداز رہے ہیں تو مارکسیت کو کیاحق پہنچتاہے کہ وہ تمام عوامل وموثرات کا انکار کرکے ساراشرف اقتصادی حالات کے حوالے کر دے اور کاروان تاریخ کی قیادت کا سہرا انہیں کے سر باندھ دے۔
پھر یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ ان داخلی کیفیات کی کوئی تفسیر اقتصادی بنیادوںپر نہیں ہوسکتی اور نہ مارکسیت کو یہ حق ہے کہ وہ ان تمام داخلیات کو اقتصاد کے حوالے کر دے اس لئے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ اگرلویس پانزدہم کے پاس وہ عزم محکم ہوتاجو لویس چہاردہم کے پاس تھا یا اس کے دل میں وہی ارادہ ہوتاجو نپولین کے سینے میں تھا تو تاریخ منقلب ہوجاتی ۔اقتصادیات کیاتھے اور کیاہوتے اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔
مارکسیت عاجزآکر یہ کہہ دیاکرتی ہے کہ:
فرانس کے اقتصادی حالات ہی نے یہ قانون بنادیاتھاکہ شاہی ''وراثت''کے طور پر چلے ورنہ اگر یہ اقتصاد زدہ قانون نہ ہوتاتو لویس اس ریاست سے محروم رہتااور اس کی نرم مزاجی سے تاریخ متاثر نہ ہوسکتی۔معلوم ہوتاہے کہ یہ تمام تر اثر اس قانون کا ہے جس سے وہ حاکم بنا اور جس کی پیداوار اقتصادیات کے زیر اثرہوئی ہے۔ (دورالفرد فی التاریخ،ص68)
لیکن سوال یہ پیداہوتاہے کہ ہم نے یہ بحث اب تک نہیں اٹھائی کہ لویس کو تاریخ پر اثرانداز ہونے کے امکانات کب فراہم ہوئے۔ہم تو اس بات پر گفتگو کررہے ہیں کہ یہی وارث تخت وتاج اگر اپنے پہلے بادشاہ کی طرح قوی الارادہ اور عظیم القلب ہوتاتو آج تاریخ کا کیارخ ہوتااور فرانس کے سیاسی حالات کیا ہوتے؟
واضح الفاظ میں یہ کہاجائے کہ لویس کی حکومت کے سلسلہ میں فرانس میں تین احتمالات تھے ایک یہ کہ موروثی ختم ہوجاتی اور ایک جمہوری نظام تشکیل پاتا۔
دوسرے یہ کہ شاہی نظام باقی رہتااور یہ لویس اپنے سابق لوگوں کی طرح ایک مضبوط دل اور محکم ارادہ کا انسان ہوتا۔
تیسرے یہ کہ لویس ویساہی ہوتاجیساکہ تھا۔
مارکسیت کے بیان سے اتنا تومعلوم ہوگیاکہ اگر اقتصادی حالات خراب نہ ہوتے تو بجائے شاہی کے جموریت ہوتی لیکن یہ سوال رہ جاتاہے کہ علم الاقتصاد کا وہ کون سا قانون ہے جو تخت وتاج کے وارث بادشاہوں کے دلوں میں نرمی وسختی اور ارادوں میں ضعف وقوت پیداکرتاہے،اور اگرایسی کوئی بات نہیں ہے تویہ کہاجاسکتاہے کہ اس پوری تاریخ فرانس کا موثر انسان کا داخل وباطن تھا اقتصادیات سے اس کا کوئی ربط نہ تھا۔
یہیں سے یہ بھی معلوم ہوجاتاہے کہ بلخانوف کا افراد کی کارکردگی کو تاریخی تغیرات
میں ثانوی حیثیت دے دینا ایک ظالم صریح سے کم نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے پوری پوری تاریخ افراد کے داخلی کیفیات پر رقص کرتے دیکھی ہے۔
بلخانوف کہتاہے کہ:
تاریخی افراد کے ذاتی خصوصیات نے حوادث کا رخ تومعین کیاہے لیکن ان کا یہ اثر ایک جزئی حیثیت رکھتاہے،حقیقی رخ واقعی اسباب یعنی اقتصادی حالات سے معین ہوتاہے۔ (دور الفرد فی التاریخ)
ہمارادل یہ چاہتاہے کہ بلخانوف کی اس تحقیق کے بارے میں ایک مثال پیش کردیںجہاں تاریخی اثراندازی کا تمام ترحصہ افراد ہی کے ہاتھ رہاہو۔
آپ فرمائیں کہ اگر جرمنی نے ایٹم کا راز اپنے وقت انکشاف سے چند سال پہلے معلوم کرلیاہوتاتو آج تاریخ کا کیاعالم ہوتا۔
کیا ہٹلر یورپ سے اشتراکیت کا جنازہ نہ نکال دیتا یقینا ایسا ہی ہوتا ایسا نہ ہوسکانہ اس لئے کہ اقتصادی حالات سازگار نہ تھے بلکہ صرف اس لئے کہ علماء کے داخلی کیفیات نے ساتھ نہ دیا اور وہ علم کی اس منزل پر نہ پہنچ سکے جس پر چند مہینہ کے اندر ہی فائز ہوگئے۔
بلکہ یہاں یہ بھی کہاجاسکتاہے کہ اگرروس کے علماء اس راز سے ناواقف ہوتے تو سرمایہ داری اس کا خاتمہ کر دیتی اور اشتراکیت کا نام ونشان بھی نہ ہوتا،کیا ان حالات کے باوجود یہ دعویٰ کیاجاسکتاہے کہ تاریخ اقتصادیات کے دم قدم سے چل رہی ہے اور انسانی خصوصیات کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے؟
مارکسیت اور فنون لطیفہ
فنون لطیفہ کا ذوق انسان کا وہ فطری جذبہ ہے جس میں دنیا کے ہر معاشرہ نے حصہ لیاہے خواہ اقتصادی اعتبار سے وہ کتنا ہی پست وبلند کیوں نہ رہاہو لیکن تاریخی مادیت نے اس ہمہ گیرذوق کے سامنے بھی اپنے کو حیران وسرگردان بنالیاہے۔
ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مصور نے کسی سیاسی لیڈر کی تصویر بنائی ہے یا ایک نقاش نے کسی میدان جنگ کا نقشہ کھینچا ہے تو ہمارے سامنے تین قسم کے سوالات ابھرتے ہیں۔یہ نقشہ کن آلات کے ذریعہ بنایاگیاہے؟اس کے بنانے کی کیاغرض تھی؟اسے دیکھ کر ہمیں ایک باطنی کیف اور نفسیاتی لطف کیوں حاصل ہوا؟
مارکسیت کے سامنے جب یہ سوالات پیش کئے گئے تو اس نے پہلے کا یہ جواب دیا کہ اقتصادی حالات کی ترقی نے انسان کو ایسے آلات بخش دیئے ہیں جن سے وہ یہ نقوش تیار کر سکے لہٰذا یہ تو اقتصاد کا طفیل اور صدقہ ہے۔
دوسرے سوال کے بارے میں یہ کہہ دیاہے کہ نقاش نے خوشامدکے طور پر یہ نقشہ تیار کیاہے اور اس سے مادی فوائد حاصل کرنا چاہتاہے۔
تیسرے سوال کے جواب میں وہ سربگر یباں ہوگئی ہے اس لئے کہ اس داخلی ذوق کو اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مارکسیت اقتصادیات کے علاوہ کسی شے پر ایمان نہیں رکھتی۔
ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام کیف ولطف اقتصادیات یا طبقات کا نتیجہ ہوتے تو اسی معاشرہ کے ساتھ فنا ہوجاتے جس کا نقش تھاحالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے فن قدیم کی لطافت انسان کی جمالیاتی حس کو آج بھی دعوت نظردے رہی ہے۔
سرمایہ دار معاشرہ جاگیردار یا غلام معاشرہ کی فنکاریوں سے آج بھی لطف اندوز ہورہاہے۔
معلوم ہوتاہے کہ ذوق کوئی ایسا داخلی جذبہ ہے جو مادیت کے پنجوں میں گرفتار نہیں ہوسکا اور وہ ہر معاشرہ پر مسلط ہوگیاہے۔
مارکس نے تاریخ کے ان ادوار کو فنی ذوق کے ساتھ اس طرح جمع کیاہے کہ:
انسان قدیم فن سے صرف اس لئے دلچسپی لیتاہے کہ وہ انسانیت کے بچپن کا دور تھا اور ہر شخص کو اپنے بچپن سے محبت ہوتی ہے۔(راس المال،ص243)
افسوس کہ مارکس نے یہ نہ بتایاکہ اقتصادی اعتبار سے انسان کو اپنے بچپن سے کیوں محبت ہوتی ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لئے کیوں بے چین رہتاہے؟
پھر یہ بھی نہ بتایا کہ اپنے بچپن کے بنائے ہوئے گھروندوں سے اتنی دلچسپی کیوں نہیں ہوتی جس قدردلچسپی یونان کے ذوق نقش ونگار سے ہوتی ہے جبکہ دونوں ہی بچپن کے آئینہ دار ہیں۔
پھراگر بات بچپن اور جوانی ہی کی ہوتی تو انسان کو قدیم طبیعی مناظردیکھ کر حظ حاصل نہ ہوتاحالانکہ وہ بہرنوع حاصل ہوتاہے اور وہ نہ کسی بچپن کا شاہکار ہے اور نہ کسی جوانی کا فن۔
کیا اس کے بعد بھی یہ کہنے میں تامل ہے کہ ان ہزار سالہ مناظر قدرت سے لطف وکیف کا حاصل ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ مارکس کا افسانہ غلط ہے اور انسانی ذوق ہمہ گیر حیثیت کا مالک ہے۔
خیراب ہم اپنی اس بحث کو ختم کرتے ہیں اور خاتمۂ کلام میں انگلز کے اس کلام کو نقل کرنے کا شرف حاصل کررہے ہیں جس کا انتظار ابتدائے بحث سے کررہے تھے۔یعنی علمی میدان میں اس کا اعتراف شکست۔چنانچہ اس نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیاہے
کہ ہماری یہ زبردستی اور اقتصادیات پر یہ پرزور ایمان کسی علمی سند کا نتیجہ نہیں ہے اس نے 1980ء میں یوسف بلاخ کو لکھاتھاکہ:
جدید قلمکاروں کا اقتصادیات پر ضرورت سے زیادہ زوردینا ایک ایسا امر ہے جس کی تمام تر ملامت میری اور مارکس کی گردن پر ہے، ہم لوگوں کا فرض تھاکہ ہم اقتصادیات کی صحیح جگہ معین کرتے اور اس کے اثرات کو سند کے ساتھ پیش کرتے ۔ہم نے ایسا ضرور کیالیکن ہمیں اس بات کا وقت،موقع یامحل نہ مل سکا کہ ہم ان دیگر عناصر وعوامل کے اثرات کی تحدید کرتے جو اقتصادیات کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ (التفسیر الاشتراکی للتاریخ،ص116)
مارکسی نظریہ کے تفصیلات
اب ہم تاریخی مادیت کے تفصیلات کی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔
اس سلسلہ کے لئے ہم نے تاریخی ادوارمیں سب سے پہلے دور کا انتخاب کیاہے جس کے متعلق مارکسیت کا خیال ہے کہ وہ معاشرہ اشتراکی تھایہ اور بات ہے کہ جد لیاتی قوانین کی بناپر اپنے اندر مخالف جراثیم بھی رکھتاتھا۔وہ جراثیم جنہوں نے بڑھتے بڑھتے اس اشتراکی معاشرہ کو غلامی اور بندگی کا رنگ دے دیا۔
س: کیاکوئی معاشرہ اشتراکی بھی تھا؟
اس بحث کی تفصیلات میںجانے سے پہلے یہ طے کرنا ہوگاکہ تاریخ کے پہلے دور کے اشتراکی ہونے کی دلیل کیاہے ؟بلکہ ماقبل تاریخ کے ادوار کے بارے میں استدلال ہی کیونکر کیاجاسکتاہے؟
مارکسیت کا کہناہے کہ ماقبل تاریخ کے ادوار پر استدلال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کے دن پست معاشروں کا مطالعہ کیاجائے جو ابھی ثقافت اور تمدن کی ابتدائی منزلوں میں ہیں اور پھر انہیں کے ذریعہ تاریخ بشریت کے بچپن کا اندازہ کیاجائے اور چونکہ ان پست معاشروں میں اشتراکی نظام رائج ہے۔لہٰذا یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ تاریخ کا ابتدائی دور اشتراکی تھا۔
مارکسیت نے بزعم خود اپنے مطلب کو ثابت کردیاہے لیکن یہ واضح رہے کہ اس
نے ان پست معاشروں کا بھی مطالعہ از خود نہیں کیاہے بلکہ ان کے سلسلہ میں بھی ان سیاحوں کی روایات پر اعتماد کیاہے جنہوں نے ان معاشروں کو دیکھ کر ان کے حالات قلم بند کئے ہیں اور پھر ان بیانات میں سے بھی صرف ان اجزاء پر اعتماد کیاہے جو اس کے لئے مفید مطلب تھے۔باقی اجزاء کو تحریف شدہ قرار دے کر نظرانداز کر دیاہے اور اس طرح اپنے نظریہ کو تاریخ کی صحت کا معیار بنادیاہے اور تاریخ کو نظریات کے جانچنے کا موقع نہیں دیا جیساکہ اس کا اعتراف خود ایک مارکسی قلمکار نے کیاہے کہ:
ہم ماضی کے متعلق اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی اجتماعی تھی پھر ان کے اجتماع کی کیفیت آج کے ابتدائی معاشروں سے معلوم کرلیتے ہیں یہ معاشرے افریقہ، بولونیزہ، مالنیزہ، آسٹریلیا، اسکیمو، لاجون او رقبل انکشاف امریکہ کے ہنود کے تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ معلومات بھی دوسروں سے حاصل شدہ ہیں۔اور ان لوگوں نے ان میں شعوری یاغیر شعوری طور پر تحریف کردی ہے۔ (القوانین الاساسیڈلااقتصادالرسمالی،ص10)
ہم اگریہ تسلیم بھی کرلیں کہ مارکسیت کی معلومات ان معاشروں کے بارے میں بالکل حتمی اور یقینی ہیں تو یہ سوال بہرحال رہ جائے گا کہ خود ان معاشروں کے ابتدائی ہونے کی کیا دلیل ہے۔
مارکسیت کے پاس اس سوال کا کوئی منطقی جواب نہیں ہے سوااس کے کہ قانون جدلیت ہمیں یہ بتاتاہے کہ معاشرہ بدلتے بدلتے آج پھر اصلی حالت پر آگیاہے۔
لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں قانون کی صحت ہی میں کلام ہے جبکہ ہم ایک ہی معاشرہ کو ہزارسال سے قائم دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی تغیر نہیں پاتے۔
س: ابتدائی اشتراکیت کے معنی کیاہیں؟
دیکھنا یہ ہے کہ مارکسیت تاریخ کے اس ابتدائی دور کو اشتراکی ثابت کرنے کا
کیاطریقہ اختیار کرتی ہے اور اس کے اشتراکی ہونے کا کیامفہوم قرار دیتی ہے؟مارکسیت کا کہنا ہے کہ:
چونکہ ابتدائی ادوار میں ذرائع پیداوار ترقی یافتہ نہ تھے اس لئے ہرشیء کی پیداوار ایک جماعتی عمل کی محتاج تھی اور ظاہر ہے کہ جب پیداوار میں سب شریک ہوں گے تو تقسیم بھی برابر کی ہوگی اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہوگاتو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک کی زیادتی دوسرے کی موت کا باعث بن جائے۔
(تطور الملکیتہ الفردیة،ص14)
یادرکئے مارکسیت کا یہ انداز بیان مورجان کے ان بیانات سے ماخوذ ہے جو اس نے شمالی امریکہ کے صحراؤں کو دیکھ کر قلم بندکئے تھے اور اس میں یہ ذکر کیاگیاتھا کہ وہ لوگ گوشت کو برابر سے تقسیم کرتے تھے۔
لیکن افسوس ہے کہ مارکسیت نے اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کو اس انداز سے بیان کیاہے جس سے اس کی پوری عمارت منہدم ہوجاتی ہے اور اس کے استدلال کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی چنانچہ جمیس آرڈریز کے حوالہ سے قدیم امریکہ کے ہنود کے حالات یوں نقل کرتی ہے کہ:
وہ لوگ ضرورتمندکی ضرورت کوپورانہ کرناایک جرم عظیم خیال کرتے تھے۔
پھرکانٹیا کے حوالہ سے بیان کرتی ہے کہ:
ہندی دیہاتیوں کے ہر مردوعورت کمسن ومسن کو یہ حق تھا کہ وہ جس گھر میں چاہے داخل ہوجائے اور جو چاہے کھالے بلکہ اس طرح عاجز اور کام چور قسم کے لوگ بھی حصہ لگالیاکرتے تھے جس کا نتیجہ یہ تھاکہ کھانے کی طرف سے ہر شخص مطمئن تھا چاہے وہ کوئی کام کرے یانہ کرے اتنا ضرور تھاکہ کام چور لوگوں کو اپنی ہیبت کے فقدان کا احساس تھا۔
(تطور الملکیتہ الفردیہ،ص18)
مارکسیت کے اس بیان سے معلوم ہوجاتاہے کہ ان لوگوں کی پیداواری حالت اتنی سقیم نہ تھی کہ ایک کی زیادتی دوسرے کے لئے موت کا سبب بن جاتی بلکہ پیداوار کی اس قدر فراوانی تھی کہ عاجز وضعیف وغیرہ بھی استفادہ کرلیاکرتے تھے اور ظاہر ہے کہ جب معاشرہ اتنا مطمئن ہوتو پھر اس کے اشتراکی ہونے پر کیا دلیل رہ جاتی ہے؟
پھر یہ سوال بھی پیداہوتاہے کہ جب سامان معیشت اتنا فراواں تھاتو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے چھین جھپٹ کیوں نہیںکی معلوم ہوتاہے کہ ان تمام باتوں کا سرچشمہ ان ابتدائی انسانوں کا شعور تھاجو انہیں اس قسم کے حرکات سے روک رہاتھا۔
اگر مارکسیت کا خیال یہ ہے کہ تقسیم میں مساوات پیداوار کی قلت کی بناپر تھی تو پھر ان کام چور لوگوں کے متعلق کیاکہاجائے گاجو گھر بیٹھے کھارہے تھے اور انہیں بھوک کا احساس بھی نہ ہوتاتھا، کیا اشتراکی پیداوار کام چور لوگوں کا پیٹ بھی بھر سکتی ہے؟
اگر یہ کہاجائے کہ وہ ایسے افراد کو صرف اس لئے کھلاتے تھے کہ کاریگروں میں کمی نہ ہونے پائے تو پھر سوال یہ پیداہوگاکہ ان افراد کو کیوں کھلاتے تھے جن کے مرجانے سے پیداوار پر کوئی برااثر نہ پڑتا؟
س: اشتراکی معاشرہ کی نقیض کیاہے؟
مارکسیت اپنے نظریہ کی بناپر یہ کہہ سکتی ہے کہ ابتدائی اشتراکیت اپنے سینے کے اندرکچھ مخالف جراثیم چھپائے ہوئے تھی۔جنہوں نے آگے چل کر اس کا خاتمہ کر دیاتھا۔
ظاہر ہے کہ ان جراثیم کا سرچشمہ طبقاتی نزاع نہ تھا اس لئے کہ اشتراکی نظام میں طبقات کاوجود نہیں ہوتابلکہ اس کا حقیقی منشا یہ تھا کہ قدیم پیداوار کی بناپر ملکیت کے تعلقات جدید ذرائع پیداوار سے ہم آہنگ نہ ہوپاتے تھے۔اب انسان اپنے وسائل کی بناپر اس قابل ہوگیاتھاکہ جانوروں کی تربیت یامعمولی زراعت کرکے اپنا پیٹ پال لیتالہٰذااب اسے کوئی ضرورت اس امر کی نہ تھی کہ اپنا پورا وقت ان باتوں میں صرف کرتااور اپنی پوری
جانفشانی سے پیداوار کاکام کرتاحالانکہ اسی کے مقابلہ میں ترقی یافتہ ذرائع پیداوار زیادہ سے زیادہ وقت اور محنت کے طالب تھے نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نے ان سہل انگار لوگوں کو مجبورکرکے ان سے کام لینے کی طرف متوجہ کیا اور اس طرح ایک ایسا نظام عالم وجود میں آگیاجو لوگوں سے زبردستی کام لے تاکہ اس طرح .......وسائل پیداوار کی مانگ پوری کی جاسکے اور ترقی کی راہیں بندنہ ہوسکیں اسی جابرانہ نظام کانام تھا نظام عبودیت یاغلام معاشرہ۔
اس نظام کا آغاز اس طرح ہواکہ لوگ میدان جنگ سے گرفتار شدہ مخالفوں کو قتل کرنے کے بجائے اپنا غلام بنالیا کرتے تھے تاکہ ان سے حسب ضرورت کام لیاجاسکے ظاہرہے کہ ان غلاموں کی خوراک ان کی پیداوار سے کم ہوگی تو اس طرح مالک کا ایک متعدبہ فائدہ بھی ہوجائے گا لیکن جب یہ سلسلہ کچھ آگے بڑھ گیاتو لوگوں نے اپنے ہی قبیلے کے زیردست افراد کو غلامی کا بھیس دینا شروع کردیااور نتیجہ یہ ہواکہ سارا معاشرہ غلام اور آقا کی شکل میں تبدیل ہوگیا۔
ہمیں اس مقام پر مارکسیت سے صرف اتنا پوچھناہے کہ ان تفصیلات کے بعد غلام معاشرہ اقتصادیات کی پیداوار رہایا اسے انسان کے دیگر جذبات سے ربط حاصل ہوگیا؟ ہمیں تو اس بیان سے ایسا معلوم ہوتاہے کہ اس معاشرہ کو اقتصادیات سے کوئی ربط نہ تھابلکہ اس کی بنیاد انسان کے داخلی جذبات پر تھی۔
بڑھتے ہوئے ذرائع پیداوار انسان سے صرف اس بات کا مطالبہ کررہے تھے کہ وہ ان پر زیادہ سے زیادہ وقت اور محنت صرف کرے۔ان کا یہ مطالبہ ہرگزنہ تھا کہ یہ محنت غلاموں کی ہو۔ان کا مطالبہ تو اس وقت بھی پورا ہوسکتاتھا جب غلاموں کی جگہ آزاد مزدور اجرت لے کر کام کرتے بلکہ اس وقت پیداوار زیادہ ہوتی اس لئے کہ غلاموں کے کام مایوسانہ ذہنیت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور آزاد کے کام میں حریت کا نشہ ونشاط ہوتاہے۔
ظاہرہے کہ عمل کے لئے نشاط ایک انتہائی ضروری عنصر ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ
اس دور کے انسان نے اس طریقۂ کار کو ترک کرکے غلامی کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟
ظاہر ہے کہ اس کا جواب ذرائع پیداوار کے پاس کچھ نہیں ہے اس لئے کہ یہ مسئلہ اقتصاد کا نہیں رہابلکہ انسانیت کا ہوگیا۔
حقیقت امریہ ہے کہ انسان اپنی داخلی کمزوری کی بناپر ہمیشہ کم کام اور زیادہ فائدہ کا طالب رہتاہے وہ ہرشیء کے لئے آسان سے آسان طریقہ اختیار کرتاہے اور یہ اقتصادیات کا اثر نہیں ہے بلکہ اس کی افتاد طبع کا اثر ہے اور یہی وجہ ہے کہ متعدد معاشروں کے بدل جانے کے بعدبھی آج یہ فطرت انسان میں باقی ہے اور وہ اس کے تقاضوںپر عمل درآمد کررہاہے۔
اب چونکہ آزاد مزدور کے ذریعہ کام لینے سے وہ منافع اور سہولتیں بہم نہیں پہنچ سکتی تھیں جو غلاموں کے ذریعہ ممکن تھیں اس لئے انسان نے اس طریقہ کوترک کرکے غلام معاشرہ کی بنیاد ڈال دی۔
وسائل پیداوار کی مثال اس تلوار کی ہے جسے کسی کے حوالے کرکے دوسرے شخص کے قتل کی دعوت دی جائے۔ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں قتل کی نسبت تلوار کی طرف نہ ہوگی بلکہ اس انسان کی طرف ہوگی جس نے اپنے طبیعی تقاضوں سے مجبور ہوکر کسی شخص کو قتل کیا ہے۔ ذرائع پیداوار اگرچہ جدید محنت کا تقاضہ کرتے ہیں لیکن محنت کا غلامانہ انداز صرف انسانی فطرت کا نتیجہ ہے اسے ان وسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
حقیقت امریہ ہے کہ غلام معاشرہ کی ایجاد کا ایک اہم بنیادی سبب تھا جس کا اظہار مارکسیت کے لئے مناسب نہ تھا اسی لئے اس نے اس قسم کی تاویلوں سے کام لیاہے۔
وہ بنیادی سبب یہ تھاکہ اس دور کے انسان اشتراکی نظام کی وجہ سے کام سے جان چرانے لگے تھے اور اس طرح ذرائع پیداوار کی مانگ پوری نہ ہورہی تھی اور وہ انسان کو مجبور کرنے پر آمادہ کررہے تھے۔جیساکہ لوسکی نے ہندی قبائل کے بارے میں لکھاہے کہ:
وہ لوگ سستی کے مارے کام نہ کرتے تھے بلکہ اس امید پر گھرمیں بیٹھے
رہتے تھے کہ دیگر کاشتکار ہمیں ہمارے حق سے محروم نہ کریں گے اور چونکہ کاریگر اور بیکار سب کا حصہ برابر ہوتاتھا اس لئے نتیجہ یہ ہوگیاکہ سب نے کام سے غفلت برتنا شروع کر دی اور اس طرح پیداوار سال بسال کم ہوتی چلی گئی۔
اشتراکیت کی یہی وہ بنیادی کمزوری ہے جس کے اظہار کی طاقت مارکسیت کے دل میں نہیں ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس طرح اس کے تمام منصوبے ناکام ہو جائیں گے اور لوگ ایسے نظام سے متنفرہو جائیں گے۔
ہمارے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روس میں اشتراکی نظام کے انطباق میں جو زحمتیں اور دشواریاں پیش آئی ہیں ان کا کوئی تعلق سرمایہ دارانہ طبقاتی افکار سے نہ تھا بلکہ اس کا تمام تر تعلق انسان کی اس فطرت اور ذہنیت سے تھا جسے وہ اپنے ہمراہ لے کر عالم وجود میں قدم رکھتا ہے یعنی '' سہولت سے کھانا مل جائے تو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟''
غلام معاشرہ
ابتدائی اشتراکیت کے مادیت تاریخ کا دوسرا مرحلہ غلام معاشرہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اوریہیں سے طبقات کی بنیاد پڑتی ہے اور پھر جدلیاتی قانون کے اعتبار سے وہ طبقاتی نزاع شروع ہوتی ہے جو تا ابد ختم نہیں ہو سکتی ۔
ہمارے سامنے جب طبقاتی نظام کا تذکرہ آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس نظام میں یہ طبقات کس طرح پیدا ہوئے ایک جماعت کو غلام اور ایک کو آقا کس نے بنایا، غلام آقا اور آقا غلام کیوں نہ بنا؟
مارکسیت اس مسئلہ کو اس طرح حل کرتی ہے کہ یہ اقتصادی حالات کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ ثروت مند تھے وہ آقا بن گئے اور جو لوگ فقیر ومفلس تھے انکی قسمت میں غلامی آ گئی۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا نظر نہیں آتا بلکہ سوال اس شکل میں ابھرتا ہے کہ آخر ایک طبقہ کے پاس ثروت کہاں سے آئی اور دوسرا اس نعمت سے کیونکر محروم رہا جب کہ دونوں اشتراکیت کی آغوش میں پل رہے تھے اور دولت آسمان سے نہیں برس رہی تھی ؟
مارکسیت اس معمہ کو بھی اس طرح حل کرتی ہے کہ اس کی دو وجہیں ہو سکیں ہیں:
(1) وہ لوگ جو فوجی عہدہ رکھتے تھے انہوں نے اشتراکیت کے دور میں بھی آہستہ آہستہ دولت جمع کرنا شروع کی اور آخرکار اپنی قوت کے زور پر اپنی مرکزیت قائم کرکے
الگ طبقہ کی شکل میں آگئے باقی افراد چونکہ ان امتیازات سے محروم تھے اس لئے وہ ناکام رہے اور ان کی قسمت میں غلامی لکھ گئی۔ (تطورالملکیتہ الفردیہ،ص32)
(2) بعض لوگوں نے جنگ سے گرفتار شدہ لوگوں کو غلام بنالیاتھا اور ان کے ذریعہ پیداوار کی فراوانی پرقادر ہوگئے تھے اور چونکہ یہ پیداواران کی ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی اس لئے رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے افراد قوم کو بھی غلام بنالیا صرف اس لئے کہ وہ لوگ ان کے مقروض تھے اور قرض کی ادائیگی پر قادرنہ تھے۔ (تطور الملکیتہ الفردیہ)
حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں جوابات مارکسیت کے لئے شایان شان نہ تھے ان لئے کہ ان میں اقتصادیات کے علاوہ دیگر عوامل کو بنیادی مقام دے دیا گیاہے۔
پہلے جواب میں یہ کہاگیاہے کہ قوم کے لیڈراور رئیس افراد نے اپنا سیاسی رنگ جمالیاتھا اور اس کے ذریعہ بڑی بڑی املاک پر قابض ہوگئے تھے جس کے نتیجہ میں ان کا شمار بڑے طبقہ میں ہونے لگاتھا۔جس کے بعد مسئلہ سیاست سے متعلق ہوگیا۔اقتصادیات سے متعلق نہیں رہا۔اقتصادیات کی حیثیت تو صرف ثانوی رہ گئی۔
دوسرے جواب میں فقط یہ بتایاگیاہے کہ غلامی کے اعتبار سے جنگ کے اسیر خاندان کے مقروض لوگوں پر مقدم تھے لیکن یہ نہیں بتایا گیاکہ اسیروں کو غلام بنانے کا موقع صرف اس جماعت کو کیسے ملا اور دوسری جماعت اس شرف سے کیونکر محروم رہی جبکہ اشتراکی دور میں دونوں برابر تھے۔
مارکسیت پیداوار کی بنیاد پر ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہے اس لئے کہ اس معاشرہ کی پیداوار میں اقتصادیات سے کہیں زیادہ انسان کی بدنی،فکری ،عسکری، نفسیاتی،حیاتی،تشریحی صلاحیتوں کا دخل ہے۔
جاگیردار معاشرہ
غلام معاشرہ کے بعد داخلی نزاعات نے جاگیردار معاشرہ پیداکیا اس معاشرہ کی بنیاد اس داخلی نزاع پر قائم تھی جو غلام معاشرہ اور ترقی یافتہ ذرائع پیداوار کے درمیان جاری ہوئی تھی اور اس طرح یہ معاشرہ جدید ذرائع کی راہ میں دودجہوں سے حائل ہوگیا:
(1) غلامی نے آقاؤں کو ایسی وحشت وبربریت پر آمادہ کر دیا جس کے نتیجہ میں کام کی زیادتی سے ہزاروں غلام تلف ہوئے اور ترقی یافتہ ذرائع پیداوار کو بقدر ضرورت طاقت نہ مل سکی۔
(2) غلام معاشرہ نے اکثرآزاد مزدوروں اور کاشتکاروں کو غلامی کا رنگ دے دیا اور عالم یہ ہواکہ قوم اس لشکر جرار سے محروم ہوگئی جس کی بنیاد پرمید ان جنگ سے غلام لائے جاتے تھے اور دوسری طرف ذرائع پیداوار کونئی طاقتوں کی ضرورت درپیش تھی جس کا نتیجہ یہ ہواکہ جاگیردارنظام عالم وجود میں آگیا۔
مارکسیت نے اپنے اس بیان میں جس غفلت سے کام لیا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا انتہائی ضروری ہے اس لئے کہ اس کے نظریہ کے مطابق نظام میں تبدیلی بغیر انقلاب کے غیر ممکن ہے۔اور رومان میں غلامی کے بعد جاگیرداری بغیر کسی انقلاب کے پیداہوئی ہے۔
دوسری بات یہ بھی ہے کہ انقلاب کے لئے ذرائع پیداوار کی ترقی ضروری تھی
حالانکہ اس دور میں ایسا کچھ نہ ہواتھا۔
تیسری بات یہ تھی کہ اس تغیر وتبدل سے معاشرہ کی کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی حالانکہ انقلاب کے لئے ترقی ضروری تھی اور قانون جدلیت کا آگے کی طرف بڑھناناگزیر تھا۔
یہ وہ بنیادی نکات تھے جن کی طرف اشارہ کیاگیااب ان کے تفصیلات بیان کئے جاتے ہیں تاکہ اس غفلت کا صحیح اندازہ ہوسکے۔
تغیر کی پشت پرکوئی انقلاب نہ تھا
اگرچہ جدلیاتی منطق کی رو سے تاریخ کے ہرتغیر کی پشت پر ایک انقلاب کا ہونا ضروری ہے اس لئے کہ اس کی نظرمیں معاشرہ میں مقدار کے اعتبار سے تغیر ہوتارہتاہے یہاں تک کہ مخالف عناصر بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد کیفیت میں انقلاب آجاتاہے اور معاشرہ کا رنگ بدل جاتاہے۔
لیکن اس کے باوجود رومان میں جاگیردارانہ نظام کے قیام کے لئے کوئی انقلاب رونما نہیں ہواجیساکہ خودمارکسیت نے بھی اعتراف کیاہے کہ:
رومان کا تغیر خودآقاؤں کی طرف سے برپاہواتھا اس میں غلاموں کا کوئی ہاتھ نہ تھا اور اس تغیر کا سبب یہ تھا کہ غلامی سے ان کے مقاصد پوری طرح حاصل نہیں ہورہے تھے اس لئے ان لوگوں نے چاہاکہ غلاموں کو آزاد کرکے ان سے کام لیاجائے۔ (تطورالملکیتہ الفردیہ،ص53)
اس بیان سے صاف واضح ہوجاتاہے کہ اس تغیر میں بنیادی حصہ مالک طبقہ کا تھا اور جرمان کی جنگ نے اس کی مزید تائید کی تھی۔
تعجب خیز بات تویہ ہے کہ جس انقلاب کی مارکسیت کو ضرورت تھی وہ جاگیردار نظام کی پیدائش سے صدیوں قبل رونما ہوچکا تھا۔چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اسپرطہ کی 4 صدی قبل میلاد کی تحریک میں غلاموں نے بڑاحصہ لیاتھا او رہزاروں افراد نے جمع ہوکر شہر پر حملہ کر دینے کا قصد کرلیاتھاجس کے بعد رئیس طبقہ کو ہمسایہ ممالک سے مددطلب کرناپڑی تھی اور چند سال کے بعد حالات پر قابو حاصل ہواتھا۔
اسی طرح رومان میں سترسال قبل میلاد کی تحریک تھی جس میں سپرتاکوس کی قیادت میں ہزاروں غلاموں نے مل کر شہنشاہی کی بنیادیں ہلادی تھیں۔
ظاہر ہے کہ یہ حالات جاگیردار نظام کی پیدائش سے بہت پہلے رونما ہوچکے تھے انہوں نے نہ تومارکسیت کی لاج رکھنے کی فکر کی تھی اور نہ ذرائع پیداوار کی ترقی کا انتظار کیا تھا نتیجہ یہ ہواکہ مارکسیت کا نظریہ باطل ہوتانظرآیا اور تاریخ اپنے مخصوص انداز سے رواں دواں دکھائی دی۔
ہماری اس تحقیق کی روشنی میں انگلز کے اس بیان کو بھی دیکھ لیجئے کہ:
جب تک پیداوار کے طریقے تکامل اور ترقی کی راہ پر لگے ہیں اس وقت تک ہراس نظام کا استقبال کیاجائے گا جس میں طریقۂ تقسیم پیداوار سے ہم آہنگ ہوخواہ کسی خاص شخص کی حالت بدتر ہی کیوںنہ ہوجائے۔
انگلز کا یہ کلام صریحی طور سے اس بات پردلالت کرتاہے کہ ذرائع پیداوار طریقۂ تقسیم سے ہم آہنگ ہوں تو نظام کا استقبال کیاجائے گااس میں انقلاب کا کوئی سوال پیدانہ ہوگاحالانکہ تاریخ صاف صاف بیان کرتی ہے کہ غلاموں نے جاگیرداری کے رونما ہونے سے چھ سوسال قبل بھی بڑے بڑے انقلابات پر پاکئے تھے۔
اب اگر مارکسیت کا دعویٰ یہ ہے کہ مظلومین کے جذبات طریقۂ پیداوار کی ترقی سے ابھرتے ہیں اور ان میں انسان کے نفسیات کو کوئی دخل نہیں ہوتاہے تو سوال یہ ہے کہ
طریقۂ پیداوارکی ترقی سے پہلے غلاموں میں یہ احساس کیسے پیداہوگیا اور ان کے جذبات اس طرح کیونکر برانگیختہ ہوگئے کہ انہوں نے رومان کا تختہ الٹنے کا ارادہ کر لیا؟
وقت انقلاب پیداوار میں ترقی نہ ہوئی تھی
کھلی ہوئی بات ہے کہ مارکسیت کے نزدیک معاشرہ کے تمام تر تعلقات پیداواری حالات کے تابع ہوتے ہیں لہٰذا کسی اجتماعی تعلق اور معاشرتی نظام میں اس وقت تک تغیر نہیں ہوسکتا جب تک کہ پیداوار کے حالات نہ بدل جائیں اور ذرائع پیداوار مزید ترقی یافتہ نہ ہوجائیں چنانچہ مارکس کا کہنا ہے کہ:
کوئی اجتماعی نظام اس وقت تک مردہ نہیں ہوسکتاجب تک کہ ذرائع پیداوار اتنی ترقی نہ کر جائیں جن سے اس نظام کی موت حتمی ہوجائے۔
(فلسفة التاریخ،ص47)
لیکن اس کے باوجود تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جاگیر دار نظام کی پیدائش کے وقت ذرائع پیداوار میں کوئی تغیر نہ ہوا تھا وہی زراعت اور دستکاری جو غلام معاشرہ میں تھی اسی کا دور دورہ جاگیردار معاشرہ میں بھی تھا یہ او ربات ہے کہ اجتماعی نظام بدل گیاتھا۔
مزید لطف یہ ہے کہ اسی کے مقابلہ میں ایسے معاشرہ بھی نظرآتے ہیں جہاں ذرائع پیداوار نے سیکڑوں کروٹیںبدل ڈالیں لیکن اجتماعی نظام پر کوئی حرف نہ آیا۔
چنانچہ خودمارکسیت اعتراف کرتی ہے کہ ابتداء تاریخ میں انسان نے پتھروں سے کام لینا شروع کیا اس کے بعد انہیں پتھروں سے آلات بنائے اور آگے بڑھاتو آگ کا انکشاف کرکے اس سے تیغ وتیربنائے،مزید ترقی کی تومعد نیات کا پتہ لگایا اوراس طرح تیر
وکمان وجود میں آئے پھر زراعت کا سلسلہ شرو ہوا، پھر حیوانات سے کام لیاگیا لیکن ان تمام تغیرات کے باوجود پوری تاریخ کو ابتدائی اشتراکیت کا دور کہاجائے گا۔
سوال صرف یہ ہے کہ اگر ذرائع پیداوار میں ان تغیرات کے بعدبھی ایک ہی نظام باقی رہ سکتاہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ نظام میں تبدیلی ہوجائے اور ذرائع پیداوار اپنی اصلی حالت پرباقی رہیں؟اور اگرایسا ہے تو پھر مارکسیت کے قوانین کا کیا حشر ہوگا؟
مارکسیت کو اس سلسلہ میں یہ بیان دینا چاہئے تھاکہ اجتماعی نظام ان عملی افکار کا نتیجہ ہوتاہے جو معاشروں کے تجربات سے حاصل ہوتے ہیں اور ذرائع پیداوار ان عملی فکروں کا اثر ہیں جو طبیعی تجربات سے انسانی ذہن میں نشوونماپاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ معاشرہ کا تجربہ طبیعات کے تجربہ سے کہیں زیادہ وقت کا طالب ہوتاہے اس لئے کہ طبیعات کا تجربہ ایک وقت کا طالب ہوتاہے اور معاشرہ کا تجربہ ایک تاریخ کے مطالعہ کا۔
لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگاکہ ذرائع پیداوار کی رفتار اجتماعی نظاموں سے کہیں زیادہ تیز ہوگی۔نظام دیر میں بدلیں گے اور ذرائع جلدی ترقی کرجائیں گے۔یہ اور بات ہے کہ اس طرح مارکسیت کا وہ دعویٰ غلط ہوجائے گا جس میں دونوں کو برابر سے لازم وملزوم کی حیثیت دی گئی ہے۔
اقتصادی حالات نے ترقی نہیں کی
سابق بیان میں کہاگیاہے کہ مارکسیت نے غلام معاشرہ کے زوال کو اس انداز سے بیان کیاہے کہ بڑھتے ہوئے ذرائع پیداوار جدید تقاضے کررہے تھے اور اس معاشرہ
کے پاس ان تقاضوں کے پوراکرنے کے اسباب موجود نہ تھے اس لئے اسے تباہ ہوجانا پڑا اور ایک نئے نظام کو عرصۂ وجود میں قدم رکھنے کا موقع مل گیا۔
دیکھنایہ ہے کہ تاریخ اس بیان کی کہاں تک تائید کرتی ہے اور وہ کون سے ترقی یافتہ ذرائع تھے جن کے تقاضے غلامی سے نہ پورے ہوسکے اور جاگیرداری کی ضرورت محسوس ہوئی کیا جاگیردار نظام ان جدید وسائل کے لئے زیادہ سازگار تھے؟کیا تاریخ اس نظام کے قیام سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی جیساکہ مارکسیت کا قانون ہے کہ تاریخ ہمیشہ ترقی کی راہوں پرگامزان رہتی ہے؟
حقیقت تویہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔آپ رومان کی اقتصادی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگاکہ وہاں بعض اطراف کی اقتصادی حالت اتنی بلند ہوگئی تھی جوایک بڑے بلند اقتصادی ملک کی ہوتی ہے۔تجارتی سرمایہ داری کا فروغ تھا۔غیر ممالک کے ساتھ ہموار راستوں اور کشتیوں کے ذریعہ بڑے زوروں پر تجارت ہورہی تھی۔داخلی تجارت نے اور بھی چارچاند لگادیئے تھے۔
اٹلی کے مٹی کے برتنوں نے عالمی بازار پر قبضہ کر لیاتھا اور ان کی مانگ شمال میں برطانیہ سے لے کر مشرق کے ساحل بحراسودتک ہوگئی تھی ادکسیاکی پن تمام شہروں میں چل رہی تھی۔بحراسود کے ساحل تک اس کا رواج بڑھ گیا تھا۔اٹلی کے گراں قدر چراغ پورے ملک میں رائج ہوگئے تھے۔
یعنی تمام حالات وہ تھے جو ایک ترقی یافتہ مملکت کے لئے ہونے چائیں لیکن اسے مارکسیت کی بدقسمتی کے علاوہ اور کیا کہاجائے کہ تجارتی سرمایہ داری صنعتی سرمایہ داری تک نہ پہنچ سکی اور اس کے لئے اٹھارہویں صدی کے نصف کا انتظار کیاجانے لگا۔حالانکہ تجار کے پاس سرمایہ کی فراوانی تھی اور غریب طبقہ کام کرنے کے لئے تیار تھا۔
آپ خود ہی سوچیں کہ اگر مادی حالات تن تنہانظام کے بدل دینے کے لئے کافی
ہوتے اور ان میں انسان کے نفسیاتی اور حیاتی اعمال کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر اس نظام میں ترقی کیوں نہیں ہوئی اور تجارتی سرمایہ داری نے صنعتی سرمایہ داری کی شکل کیوں اختیار نہیں کی؟
ہمیں تو اس جاگیرداری سے ایک عجیب تلخ تجربہ حاصل ہواہے اور وہ یہ کہ اس نے تاریخ کو آگے بڑھانے کے بجائے مارکسیت کے اعلیٰ الرغم اور پیچھے ہٹادیا۔اس لئے کہ جاگیرداروں کے پاس زمینوں کی فراوانی ہوگئی اور انہوں نے اسی سے اپنے معاشیات کا انتظام شروع کردیا۔تجارت سے دلچسپی کم ہوتی گئی اور وہ وقت بھی آگیا جب معاشرہ اسی گھریلوزندگی کی طرف پلٹ آیا جس پر اس ترقی سے پہلے قائم تھا۔
کیا جرمان کے داخلہ کے بعد رومان کے یہ اقتصادی حالات ترقی یافتہ کہے جاسکتے ہیں؟
کیاانہیں حالات کی بنیاد پرمارکسیت کی اس جدلیت کی تصدیق کردی جائے جس میں کاروان تاریخ ہمیشہ آگے کی طرف چلتاہے۔
آخرکار سرمایہ دار معاشرہ پیداہوگیا
جب تاریخی مشکلات اور پیداواری دشواریوں نے نئے حل کا مطالبہ کیاتو سرمایہ داری جدید حل کی صورت میں اجتماعی میدان میں آکھڑی ہوئی اس لئے کہ یہی وہ نقیض تھی جس کے ہاتھوں جاگیرداری کی موت مقدر ہوتی تھی۔مارکس نے سرمایہ داری کی تاریخ کو اس انداز سے بیان کیاہے کہ:
''سرمایہ دار نظام'' جاگیرداری کے شکم سے متولد ہواہے اس طرح کہ ایک کی تباہی دوسرے کی آبادی کا سبب بن گئی۔
(راس المال ،ق2،ج3،ص1053)
مارکس نے جب بھی سرمایہ داری کا جائزہ لینا شروع کیاہے توپہلے سرمایہ کی فراوانی کے موضوع کو اہمیت دے کر اس کا تجزیہ کیاہے۔اس کی نظرمیں اس پورے نظام کی بنیاد اسی ایک نکتہ پر قائم ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس نظام کے تجزیہ کے لئے سرمایہ کے موضوع پر بحث کرنا انتہائی ضروری ہے۔اس لئے کہ جب بھی تاریخ میں یہ دیکھاجائے گاکہ ایک طبقہ نے کثیر سرمایہ اور پھر اس کو مزید ترقی دینے کے لئے مزدوروں کی محنت کو مہیاکر لیاہے تو فوراً یہ سوال پیداہوگاکہ یہ سرمایہ اور یہ عملی طاقتیں کن عوامل واسباب کی بناپر ایک طبقہ کے ساتھ لگ گئیں۔یعنی سرمایہ کی فراوانی اور مزدوروں کی زیادتی کا حقیقی راز کیاہے؟
مارکس نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پہلے اس تقلیدی نظریہ کو بیان کیاہے جو سلف سے چلا آرہاتھا اور جس میں اس فراوانی اور ارزانی کا راز ایک جماعت کی ہوش مندی اور حسن تدبیر کو قرار دیاگیاتھا اور پھر اس کے بعد حسب عادت اس نظریہ کا استہزا کرکے اپنے طورپر اس کا تجزیہ کیاہے اس کا کہناہے کہ:
سرمایہ دار نظام ایک ایسے دستور کا مظہر ہے جس میں ایک طرف سرمایہ دار ہوتاہے جو تمام ذرائع پیداوار کا مالک ہوتاہے اور دوسری طرف وہ مزدور ہوتاہے جو ملکیت کے تمام حقوق سے عاری ہوتاہے اس کے پاس عمل کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہوتا۔نتیجہ یہ ہوتاہے کہ مالک تمام وسائل وآلات سے استفادہ کرتاہے اور مزدور اپنی مجبوری کی بناپر اس کا اجیر ہوجاتاہے واضح الفاظ میں یہ کہاجائے کہ سرمایہ داری مزدور اور اس کی پیداوار کے درمیان جدائی کانام ہے لہٰذا اس نظام میں اس جدائی کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور یہ نظام اسی وقت تک
قائم رہے گا جب تک کہ یہ جدائی باقی رہے گی اور ان کے تمام وسائل کو غصب کرکے مالکوں کے پاس جمع کردیاجائے گا نتیجہ یہ ہے کہ سرمایہ کی فراوانی کا راز ان عوامل واسباب مین منحصر ہے جو مزدور کو اس کی پیداوار سے جداکردیں اور سرمایہ دار کے گھران ثروتوں کو جمع کریںاور وہ عوامل تاریخی اعتبار سے غصب وسلب، لوٹ مارکے علاوہ کچھ نہیں ہیں ہوش مندی اور تدبر کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ (راس المال،ج3،ص1050تا1055)
سوال یہ رہ جاتاہے کہ کیا مارکس سرمایہ کی فراہمی کے اسباب بیان کرنے میں کامیاب ہوگیا۔
اس مسئلہ کو حل کرنے سے پہلے یہ بتادینا انتہائی ضروری ہے کہ مارکس اس مقام پر سرمایہ داری کو لوٹ مارکا نتیجہ قرار دے کر اس کی توہین وتحقیر نہیں کرناچاہتاہے اس لئے کہ اس کی نظرمیں اشتراکیت تک پہنچنے کے لئے سرمایہ داری ایک تاریخی ضرورت تھی اور اخلاقیات کا معیار بھی یہی ہے کہ جو وقتی ضرورت سے ہم آہنگ ہووہ اخلاقی امر ہوتاہے۔چنانچہ انگلز کہتاہے کہ:
اگرمارکس سرمایہ داری کے بڑے پہلوؤں کو ظاہر کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتاہے کہ معاشرہ کو ان چیزوں کی ضرورت تھی تاکہ یہ ذرائع پیداوار کو ترقی دے کر اس منزل سے ہمکنار کردیں جہاں اخلاقی اقدار بھی ترقی یافتہ ہوں۔
(راس المال ملحقات،ص1168)
مارکس کا واقعی مقصد یہ ہے کہ اپنے تجزیہ کو تاریخ پر منطبق کرکے اس کی صحیح تشریح کرے تو اب پھر وہی سوال پیداہوگاکہ کیا وہ اپنے مقصدمیں کامیاب ہوگیا؟
مارکس نے واضح طور پر اس بات کو ملاحظہ کیاکہ سرمایہ داری میں ایک طبقہ ثروتمند ہوتاہے اور ایک ایسا محتاج ہوتاہے کہ وہ اپنی پیداوار کو سرمایہ دار کے حوالے کرنے پر مجبور ہوجاتاہے اور اسی سے یہ نتیجہ اجذ کر لیاکہ سرمایہ دار نظام مزدور کے پاس ذرائع پیداوار کے نہ
ہونے پر موقوف ہے اور اس کی صرف یہی صورت ہے کہ ثروت مند مزدور کے جملہ وسائل کو بزور اس سے سلب کرلے۔
اس نے یہ بھی خیال نہیں کیاکہ میں نے ابتداء امر میں صرف اتنا بیان کیاتھاکہ سرمایہ داری ایک طبقہ کے پاس وسائل معیشت کے نہ ہونے کا نام ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیاکہ یہ وسائل کیونکر مفقود ہوجاتے ہیں اور آخرکلام میں اس کو بھی بڑھادیااور اس طرح اپنا مطلب حاصل کرلیا۔حالانکہ یہ بات عقل ومنطق کے خلاف تھی۔
شایدمارکسیت یہ کہے کہ اگرچہ سرمایہ داری کا راز ایک طبقہ کی ثروت مندی اور دوسرے کی تہی دستی ہی میں مضمر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس تہی دستی کی کوئی توجیہ سوائے اس لوٹ مارکے اور کیاکرسکتے ہیں؟اس بناپر ہم مجبور ہیں کہ اس ٹکڑے کا اضافہ کریں۔
لیکن یادرکھئے کہ اگر مارکسیت اس اضافہ کا حق رکھتی ہے تو پھر ہمارے بھی چند اعتراضات سنناپڑیں گے۔
(1) مارکس کا بیان جرمنی جیسے ممالک پر منطبق نہیں ہوتا جہاں سرمایہ داری جاگیردوری کے بل بوتے پرپروان چڑھی ہے اس وقت جب کہ خود جاگیرداروں نے اپنی دولت کے سہارے بڑے برے کارخانے کھول دیئے اور ان کو ترقی دینا شروع کر دی یہاں تک کہ ان کا شمار سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ظاہر ہے کہ اس طریق کارمیں نہ غصب کا سوال تھا نہ لوٹ مار کا۔بلکہ جاگیرداروں کی اپنی مرضی کا سوداتھا جسے انہوں نے اپنے قوت بازو سے تمام کیا۔
بعینہ یہی اعتراض اس صنعتی سرمایہ داری پر بھی ہوگاجس کا قیام تجارتی سرمایہ داری کی بنیاد پر ہواہے جیساکہ اٹلی کے ممالک بند قیہ، جنیوا،فلورنسہ وغیرہ میں تھا کہ یہاں تاجروں کا طبقہ اس وقت بھی موجود تھا جب اصطلاحی طور پر مارکسی صنعت کار مزدور نہ پیداہوئے تھے۔ لوگ اپنے گزربسر کے لئے کام کرتے تھے اور اس طرح اپناپیٹ
پالتے تھے لیکن تاجروں نے صلیبی جنگ کے نتیجہ میں ترقی یافتہ مشرق سے تجارت کرکے مصر وشام کے بادشاہوں سے تعلقات کی بناپر اتنا سرمایہ جمع کرلیا کہ اپنے کو جاگیرداری سے آزاد کرکے بڑے بڑے کارخانے کھولنے لگے اور نتیجۂ کار میں دستکاری کا خاتمہ ہونے لگا اور اس طرح صنعتی سرمایہ داری عالم وجود میںآگئی۔ظاہر ہے کہ ان حالات میں مزدوروں سے ان کے ذرائع معیشت کو غصب نہیں کیا گیاتھا بلکہ ایسے حالات پیداہوگئے تھے کہ وہ خود بخود میدان سے ہٹ گئے اور سرمایہ دارانہ نظام وجود میں آگیا۔
(2) مارکسیت کے ان بیانات کو تسلیم بھی کرلیاجائے تو اصل مشکل حل ہوتی نظرنہیں آتی اس لئے کہ سرمایہ داری کا ایک طبقہ کے رئیس اور دوسرے کے محتاج ہونے کی بناپر موقوف ہونا صحیح ہے۔لیکن سوال یہ ہے کہ اس طبقہ کے پاس سرمایہ کیسے آیااور اس طبقہ کو ان تمام نعمتوں سے کس نے محروم کردیا؟
(3) مارکس نے سرمایہ دار کی ثروت کے سلسلہ میں جس غصب وسلب اور قوت وطاقت کا حوالہ دیاہے وہ اس کی شان کے لئے قطعاً سزاوار نہیں ہے۔قوت وطاقت کو اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مارکسیت کی نظرمیں پوری تاریخ کو اقتصادی ہونا چاہئے۔
ہماراخیال یہ ہے کہ مارکس اسی تقلیدی نظریہ کو قبول کرلیتاجو سابق سے چلا آرہاتھا تو زیادہ بہتر تھا اس لئے کہ وہ نظریہ اقتصادیات سے زیادہ قریب تر تھا لیکن افسوس کہ ایسانہ ہوا اور مارکسیت کے گھرکو گھر ہی کے چراغ سے آگ لگ گئی۔
یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ مارکس نے اس مقام پر لوٹ مارکے جتنے واقعات بھی نقل کئے ہیں وہ سب انگلستان کے ہیں اور اس وقت کے جب جاگیرداروں نے کاشتکاروں کو زمینوں سے نکال کر ان اراضیات کو چراگاہ کی شکل میں تبدیل کردیاتھا اور ان
غریبوں کو بورژوابازاروںکے حوالے کر دیاتھا۔
ظاہر ہے کہ یہ اعمال جاگیردار اپنے جاگیردارانہ معاملات کے لئے کرہے تھے۔ انہیں تجارت سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ انہیں کو سرمایہ دارانہ تجارت کی تمہیدقرار دے دیاجائے۔
یہ بھی نظراندازنہ ہوناچاہئے کہ مارکس نے اس لوٹ مارکو سرمایہ داری کی تمہید ثابت کرنے کے لئے متعدد صفحے سیاہ کرڈالے ہیںلیکن اس کے علاوہ کچھ نہ لکھاکہ لوگوں نے کاشتکاروں کی زمینوں کو چراگاہ توبنالیالیکن کاشتکاروں کے ایک عظیم لشکر کی کوئی پروانہ کی۔
سوال یہ پیداہوتاہے کہ جاگیردار وں کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی اور انہوں نے زمینوں کو چراگاہ بنانے کی فکرہی کیوں کی؟مارکس کے پاس اس سوال کا جواب یہ ہے کہ :
چونکہ فلاندروغیرہ میں ادن کے کارخانے ترقی کررہے تھے اور اس طرح اس کا بازار ترقی پر تھا اس لئے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیداہوئی کہ اب ادن کی پیداوارزیادہ کی جائے تاکہ دولت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو سکے۔ (راس المال ،ق2،ج3،ص1059)
حقیقت یہ ہے کہ مارکس کے اس جواب میں ایک ایسا تاریخی نکتہ پایاجاتاہے جسے اس نے درخور اعتناء نہیں قرار دیاحالانکہ اس کو بقدر ضرورت اہمیت دینی چاہئے تھی۔ نکتہ یہ ہے کہ:
فلمنکی شہروں اور بالخصوص بلجیک کے جنوبی علاقوں میں صنعتی ترقی اور ادن کی سرمایہ دارانہ پیداوارنے جاگیرداروں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ کیااور انہوں نے کھیتوں کو چراگاہوں کی شکل میں بدل دیاتاکہ ان شہروں تک ادن سپلائی کرکے ان کے بازاروں پر قبضہ جمایاجائے اس لئے کہ اس وقت انگریزی ادن کی قدر وقیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔
(تاریخ انگلستان،ص56)
اس بیان کی کیفیت ہی یہ بتاتی ہے کہ مارکس اپنے تاریخی استنتاج میں ناکام رہاہے اور اس طرح اس نے جس شیء کو واقعی سبب قراردیاہے وہ سبب نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے عوامل ہیں جو اس وقت کارفرماتھے جب سرمایہ داری وجود میں آرہی تھی اور جاگیرداری کا خاتمہ ہورہاتھا۔
وہ عوامل کیاتھے؟
خارجی تجارت کا فروغ اور انگلستان ادن کی ترقی۔
ظاہر ہے کہ بیرون ملک تجارت کے فروغ کو ملک کی داخلی نقیض نہیں قرار دیاجا سکتاجبکہ جدلیت کا اصرار ہے کہ ہر انقلاب کو داخلی تضادوتناقض کی بناپر پیداہوناچاہئے۔
مارکس کا اعتراف
آخرکار مارکس نے یہ محسوس کرلیاکہ ہمارے یہ تمام بیانات صرف اس بات کو واضح کرسکتے ہیں کہ کاشتکار افراد مزدوروں کی طرح کام کرنے پر کیونکر آمادہ ہوگئے لیکن سرمایہ کی فراوانی جس کے متعلق بحث ہورہی ہے اس کی کوئی توجیہ اس لوٹ مارکی بنیادپر نہیں ہوسکتی ہے۔
چنانچہ اکتیسویں فصل سے اس نے ایک نئے استدلال کا آغاز کیا۔اور یہ بیان کیاکہ:
امریکہ میں سونے چاندی کی کانوں کا برآمد ہوجانا،مقامی لوگوں کا غلامانہ زندگی بسرکرنا اور پھر ان کانوں میں دفن ہوجانا،مشرقی ہند کے جزیروں
میں لوٹ مار،افرایقہ سے حبشیوں کی بے ڈھب گرفتاری وہ حسین اسباب ہیں جنہوں نے سرمایہ داری کی بشارت دی تھی اور جن کے زیر اثر یہ نظام وجود میں آیاتھا۔ (راس المال،ص1116)
عجیب بات یہ ہے کہ مارکس نے اپنے اس اقدام میں بھی طاقت وقوت،غصب وسلب کے علاوہ کسی اور شیء کی نشان دہی نہیں کی ہے جبکہ ہم باربارواضح کرچکے ہیں کہ ان امور کو اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
شاید یہی وجہ تھی کہ مارکس نے اپنے بیان کی اس کمزوری کا بھی احساس کیااور پھر یہ بیان دیاکہ:
قدیم معاشرے قوت ہی کے زور پر عالم وجود میں آئے ہیں اور قوت بھی ایک اقتصادی ہی عامل وموثر ہے۔
اس مقام پر مارکس نے اقتصاد کے مفہوم کو اتنا وسیع کر دیاہے کہ اس میں دنیا کے ہر موثر کو شامل کرلیاہے۔ورنہ ظاہر ہے کہ قوت کو اقتصاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ انگلز نے اپنے بیان میں اس نکتہ کی شدید مخالفت کی ہے۔وہ کہتا ہے کہ:
ہم ان تمام حالات کی خالص اقتصادی توجیہ کر سکتے ہیں جہاں قوت اور سیاست کا نام تک نہ آنے پائے۔رہ گئی حکومت کی دخل اندازی تو اس کی بناپر ملکیت کو قوت کا نتیجہ نہیں قرار دیاجاسکتا،قوت کا تذکرہ وہی شخص کرے گا جو حقائق کے سمجھنے سے محروم ہویا ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتاہو۔
(صنددو ہرنگ،ج2،ص32)
جب ہم سرمایہ داری کے مارکسی تجزیہ کے سلسلہ میں انگریزی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیںاور مارکس کے بتائے ہوئے نکات پر نظرڈالتے ہیں تو ہمیں اس تاریخ سے نہ کوئی ہمدردی پیداہوتی ہے اور نہ نفرت۔اس لئے کہ ہمارا موضوع یورپ کی تاریخ سے سیاہ
اوراق کو صاف کرنانہیں ہے اور نہ ہی ہم سرمایہ داری کے زیر اثرپیداہونے والے نتائج کو طشت ازبام کرنا چاہتے ہیں ہماری تمام تردلچسپی اس تاریخ سے صرف اس ضرورت کے تحت ہے جس کا مارکسیت نے دعویٰ کیاہے کہ قانون جدلیت کی رو سے بغیر ان ہنگامہ آرائیوں کے سرمایہ دار نظام صفحۂ وجود پر نہیں آسکتاتھا۔
ہمیں اس سلسلہ میں انگلستان کے ساتھ دیگر ممالک کی تاریخ کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ہم صرف انگلستان کی تاریخ پر اکتفا نہیں کرسکتے اس لئے کہ مسئلہ انگلستان کا نہیں ہے بلکہ تاریخ بشریت کا ہے۔اور اس کے حدود چاردانگ عالم تک پھیلے ہوئے ہیں۔
اس سلسلہ میں ہماری نظرسب سے پہلے فلاندرز اور اٹلی پر پڑتی ہے جہاں سرمایہ دار نظام تیرہویں صدی میں عالم وجود میں آیا۔بڑے بڑے کارخانے قائم کئے گئے۔ ہزاروں مزدوروں نے کام کیااور اتنی جنس پیداکردی کہ عالمی بازار پر قبضہ کرلیالیکن اس کے باوجود وہ تمام حالات پیش نہیں آئے جنہیں مارکس نے انگلستان کے سلسلہ میں بیان کیاہے۔
ظاہرہے کہ اگر یہ حالات سرمایہ داری کے لئے ضروری ہوتے تو ان ممالک میں یہ نظام کامیاب نہ ہوسکتا حالانکہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ نظام قائم ہوااور اس طرح مارکسیت کو کھلی ہوئی نظریاتی شکست سے دوچار ہوناپڑا۔
ہمارے سامنے دوسری مثال جاپان کی ہے جہاں انیسویں صدی میں جاگیردار نظام سرمایہ دارکی شکل میں مبدل ہواجیساکہ خود مارکس نے بھی اشارةً بیان کیاہے کہ:
جاپان خالص جاگیردارانہ نظام ہونے کے باعث یورپ کی درمیانی صدیوں کے بارے میں مختلف جہتوں سے ایسی شکل پیش کرتاہے جو بورژوا تاریخ کی کتابوں سے کہیں زیادہ معتبر ہے۔ (راس المال،ج3،ص1058)
دیکھنا یہ ہے کہ مارکس کے اعتراف کے مطابق وہ صحیح شکل کیاہے جسے جاپان نے
اپنی تاریخ کے سلسلہ میں پیش کیاہے؟اور آیایہ شکل مارکسی نظریات سے ہم آہنگ ہے یا نہیں؟
تاریخ کہتی ہے کہ جاپان جاگیرداری کے خواب میں محواستراحت تھا کہ ایک مرتبہ خارجی خطرات کے جرس نے اسے اس عالم میں بیدار کیاکہ وہ انتہائی خوفزدہ تھا۔وقت وہ تھا جب 1853ء مین امریکی اسطول نے خلیچ اور اجاپر حملہ کر دیا تھا اور لشکری حاکم نے اس سے ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیاتھا۔جاپان نے اس وقت یہ طے کر لیاکہ در حقیقت یہ ایک اقتصادی جنگ ہے جس کے نتیجہ میں اسے بربادی کا شکار ہوجاناپڑے گا اور اب نجات کی فقط یہ صورت ہے کہ کاروبار شروع کرکے جاپان کو دیگر ترقی تافتہ ممالک کا ہمدوش بنادیاجائے۔ چنانچہ جاگیرداروں نے خودہی اس فکر کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی فکر کی اور لشکری حاکم کو نکال باہر کرکے 1868ء میں شہنشاہی قائم کر دی تازہ حکومت نے صنعتی انقلاب پر پوراپورا زور دیا۔بڑے طبقہ نے اس کی مکمل حمایت کی،تاجر اورکاریگر طبقہ جو معاشرہ کا پست ترین طبقہ تھا بلندی کی سطح پر آگیا اور اس طرح دیکھتے دیکھتے جاپان یورپ ممالک کا ہم دوش ہونے لگا۔ 1871ء میں جاگیرداروں نے اپنے تمام خصوصیات اورامتیازات سے دست برداری اختیار کرلی اور حکومت نے بھی انہیں املاک کی بجائے کا غذات دے دیئے اور اس طرح نہایت ہی صلح و آتشی اور صبراور سکون کے ساتھ صنعتی سرمایہ داری عالم وجود میں آگئی۔جاپان کو اچھی خاصی مرکزیت بھی حاصل ہوگئی اور کوئی داخلی یا خارجی نزاع بھی سامنے نہیں آئی۔
آب آپ ہی غور فرمائیں کہ کیایہ نتائج وحالات تاریخی مادیت پر منطبق ہوتے ہیں :
(1) مارکسیت کا خیال ہے کہ معاشرہ کا تغیر انقلاب کے بغیر ناممکن ہے اس لئے کہ معاشرہ میں تدریجی طور پر مقداری تغیر ہوتاہے اور پھر یہ مقدار بڑھتے بڑھتے دفعتاً نظامی تغیر کی شکل اختیار کرلیتی ہے۔
حالانکہ جاپان میں ایسا کچھ نہیں ہوابلکہ سرمایہ داری سکون و صبر کی فضامیں عالم وجود میں آئی۔انقلاب کا تونام بھی نہیں آسکااور نہ جاپان کا1871ء فرانس کا 1789ء ہی
بن سکا۔
(ب) مارکسیت کا کہنا ہے کہ معاشرہ میں کوئی ترقی بغیر طبقاتی نزاع کے غیر ممکن ہے۔
حالانکہ جاپان یہ کہتاہے کہ ترقی تمام طبقات کے اتحاد سے پیداہوتی ہے باہمی نزاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ہمارے یہاں جاگیرداروں نے خود بھی جدید نظام کی تشکیل میں حصہ لیاہے۔
(ج) مارکسیت کا اصرار ہے کہ سرمایہ کی فراوانی سنجیدگی کے ساتھ ناممکن ہے اس کے لئے غصب وسلب لوٹ مار لازمی اشیاء ہیں۔
جاپان کی تاریخ بآواز بلند پکاررہی ہے کہ اس کے لئے کسی جنگ وجدل کی ضرورت نہیں ہے کوئی لوٹ مارلازم نہیں ہے۔یہ کام نہایت آسانی سے ہوسکتاہے بشرطیکہ پورا ملک متوجہ ہوا ور مقصد کی کامیابی کے لئے خاطرخواہ قربانی پیش کرے۔
آخرہمارے ملک میں یہی تو ہواکہ تمام طبقات بروقت متوجہ ہوگئے اور انہیں کے سیاسی افکار کے نتیجہ میں ہم نے ترقی کی اور ہمارے اقتصادیات سدھر کرسرمایہ داری کی شکل میں آگئے۔
ہمارے یہاں ایسا کبھی نہیں ہواکہ اقتصادیات کے زیر اثرسیاسیات پیداہوں۔ہم نے سیاسیات ہی سے اپنی اصلاح کی ہے اور اپنے کودیگر ترقی یافتہ ممالک کے دوش بدوش چلایاہے۔
سرمایہ دار نظام کے قوانین
اگر سرمایہ دار نظام کے قوانین کو تاریخی مادیت کی رو سے دیکھنا چاہیں تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہوگی کہ اس کے اقتصادی رخ کوو اضح کریں اس لئے کہ مارکسیت کی نظرمیں یہی سب سے اہم نکتہ ہے اور اس نے اسی نظام کے بارے میں اپنے نظریہ کو واضح طور پر بیان کیاہے مارکسیت کا خیال ہے کہ اس نظام کے داخل میں بھی ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو ایک دن اسے موت کے گھاٹ اتاردیں گے اور اس طرح مارکس کا خواب اشتراکیت کی شکل میں شرمندۂ تعبیر ہوجائے گا۔
قیمت کی بنیاد عمل
مارکس نے سرمایہ داری کے تجزیہ کی ابتدااس بات سے کی ہے کہ پہلے جنس کی بازاری قیمت کا معیارمعلوم کیاجائے اور یہ صحیح بھی ہے جیساکہ تمام اقتصادی مفکرین کا وطیرہ رہاہے کہ وہ حضرات اس موضوع پر سب سے پہلے اسی نکتہ سے بحث کرتے ہیں۔
مارکس نے اس میدان میں کسی جدید نظریہ کی بنیاد نہیں ڈالی بلکہ ریکارڈوکے اسی تقلیدی نظریہ کو اپنا لیاہے جس میں عمل کو قیمت کا معیار قرار دیتے ہوئے یہ بتایاگیاہے کہ ایک گھنٹے کے کام کی پیداوار کی قیمت اس شیء کی آدھی ہوگی جس کی پیداوار میں دو گھنٹے کا وقت صرف ہواہے۔
ریکارڈو نے اس نظریہ کو عملی حیثیت ضرور دی ہے لیکن اس سے پہلے اس کی طرف جان لاک نے بھی اشارہ کیاتھا جس پر آدم سمتھ نے یہ تبصرہ کیاتھاکہ یہ نظریہ صرف ابتدائی معاشروں کے لئے ہے اس کے علاوہ دیگر سماجوں کا نظام اور معیار کچھ اور ہونا چاہئے۔ ریکارڈونے آدم سمتھ کی اس رائے سے اختلاف کرکے اسی معیار کو تمام معاشروں کے لئے صحیح وصائب قرار دیاہے۔
مارکس نے بھی اسی نظریہ کو قبول کیاہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس نے اس میدان میں کچھ نہیں کیابلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اس نے اس میں بہت سے اضافے کئے ہیں اور اس کے علاوہ پورے نظریہ کو ایک خاص رنگ دیاہے جو اس کی فکر سے ہم رنگ تھا۔
ریکارڈو کا خیال تھاکہ یہ نظریہ ان حالات پر منطبق نہیں ہوسکتاجن میں لوگ احتکار(ذخیرہ اندوزی)پر آمادہ ہوجائیں اس طرح کہ رسدکم ہواور مانگ زیادہ۔اس لئے کہ ایسے حالات میں جنس پر عمل کی زیادتی نہ ہوگی لیکن قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہوجائے گا۔ مارکس نے اس استثنائی صورت کو بھی قبول کیاہے اور احتکار کو اپنے قانون سے خارج کردیاہے۔
ریکارڈونے یہ بھی دیکھاکہ اعمال کی حیثیت میں کام کرنے والوں سے بھی فرق ہوجاتاہے ایک ہوش مند نوجوان کا ایک گھنٹہ ایک بیوقوف لاغرکے ایک گھنٹے سے کہیں زیادہ قیمت رکھتاہے اس لئے اس نے اس بات کی فکر کی کہ عمل کا ایک معیار بنالیاجائے تاکہ اسی اعتبار سے چیزوں کی قیمت لگائی جاسکے۔چنانچہ اس نے اس قسم کے عمل کا نام''معیاری ضروری محنت''رکھااور یہ اعلان کر دیاکہ''ہر عمل کی مناسب قیمت معیاری ضروری محنت کے معیار پر لگائی جائے۔''
ریکارڈونے ایک مزید فکر یہ کی کہ قیمت کے معیار سے زمین،آلات،سرمایہ وغیرہ کو خارج کردیاجائے اس لئے کہ ان چیزوں کو قیمت کی پیداوار میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس نے زمین کے متعلق یہ فیصلہ کردیاکہ زمین کی خوبی احتکار کا نتیجہ ہے۔جن لوگوں کے پاس اچھی زمین ہوتی ہے وہ اس کی خوبی کی وجہ سے زیادہ منفعت حاصل کرلیتے ہیں اور اس طرح دوسرے افراد کو معمولی آراضی میں کاشت کرنا پڑتی ہے لہٰذا اس کو احتکار میں داخل کرکے معیار سے الگ کردیاجائے حالانکہ اس سے قبل علماء اقتصاد کا خیال تھا کہ زمین کی صلاحیت اللہ کا ایک عطیہ ہے جو انسانی محنت کے بعد عطاہوتاہے۔
سرمایہ کے متعلق اس نے یہ رائے قائم کی کہ سرمایہ بہت سے اعمال کے مجموعہ کا نام ہوتاہے۔اس کی مستقل کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔آپ جب یہ دیکھیں کہ کوئی ایک ساعت کا پیداکردہ سرمایہ کسی ایک ساعت کے کام میں لگادیاگیاتو یہ خیال نہ کریں کہ اس
مقام پر ایک سرمایہ ہے اور ایک ایک ساعت کا عمل بلکہ یہ دیکھیں کہ ایک ساعت کے عمل پر ایک ساعت کے نتیجۂ عمل کا اضافہ کردیاگیاہے اور ظاہرہے کہ اس طرح جنس کی قیمت میں اضافہ ہوجائے گا حالانکہ معیار اپنے مقام پر محفوظ رہے گا۔
ریکارڈوکے ان نظریات سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ سرمایہ دارانہ منافع کی مذمت کرے گا اس لئے کہ اس صورت میں سرمایہ دار قیمت زیادہ لگاتاہے اور عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتالیکن ایسا کچھ نہیں ہوابلکہ اس نے ان منافع کو جائز قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیاکہ ہر شخص کو اپنے مال کے بارے میں اختیارہے۔وہ جس قدرقیمت چاہے وصول کرسکتا ہے یہ اور بات ہے کہ یہ صرف اسی وقت ہوگاجب کہ جنس بازار تک نہ پہنچ سکی ہو۔
ریکارڈو نے اس ایک جزو کا اضافہ کرکے اپنی پوری عمارت کو مہندم کردیااور اپنے اس بیان سے زمانہ کو بھی قیمت کا معیار بنادیاکہ ایک زمانہ میں قیمت کم ہوگی جب جنس زیادہ ہو اور دوسرے زمانہ میں زیادہ ہوگی جب جنس کم ہوحالانکہ وہ شروع سے عمل کے علاوہ کسی شیء کو بھی معیاری حیثیت دینے کے لئے تیار نہ تھا۔
مارکس نے ریکارڈو کے ان تمام نظریات کو دیکھتے ہوئے ان میں بعض مقامات پر اصلاح کی ہے اور بعض مقامات پر جدید اضافے کئے ہیں۔اصلاح کے سلسلہ میں یہ بتایا ہے کہ ریکارڈونے زمین کی صلاحیتوں کو پوری طرح احتکار میں حساب کر لیاہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ صلاحیت کی دو قسمیں ہیں ایک صلاحیت زمینوں کے اعتبار سے ہے اور ایک صلاحیت خودذاتی کمزوری کی بناپر ہوتی ہے اس لئے کہ زمین پیمائش کے اعتبار سے بھی تو ایک محدود حیثیت ہی رکھتی ہے۔ (راس المال،ص1186)
مارکس نے اقتصادی بنیادکس طرح قائم کی؟
مارکس نے عمل کے معیار قیمت ہونے پر اس طرح استدلال کیاہے کہ ہر شیء میں دو قسم کی قیمتیں ہوتی ہیں،استعمالی قیمت، تبادلہ کی قیمت۔
استعمالی قیمت سے مراد وہ منافع ہیں جو عالم کی تمام اشیاء سے مختلف صورتوں میں حاصل ہوتے ہیں۔آپ کے پاس ایک تخت ہے،ایک چمچہ ہے، ایک روٹی ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کے منافع مختلف ہوں گے۔اس لئے کہاجائے گا کہ ان کی استعمالی قیمت مختلف ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان ایک تخت کو ایک ریشمی کپڑے کے عوض دے دیتاہے تو سوال یہ پیداہوتاہے کہ اس تخت کو اس کپڑے کے برابرکس شیء نے کردیا اور وہ کون سی مشترک شیء ہے جو ان دونوں کی مساوات کا باعث بنی۔ ظاہرہے کہ وہ نہ تخت ہے اور نہ لباس۔ اس لئے کہ یہ دونوں ذاتی اعتبار سے مختلف ہیں۔ان کومشترک نہیں قرار دیا جاسکتا۔
اسی طریقہ سے وہ شیء مشترک استعمالی فائدہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ استفادہ بھی تخت سے اور ہوتاہے اور لبا س سے اور۔
معلوم ہوتاہے کہ ان کے درمیان کوئی اور شیء ہے جس نے دونوں کو تبادلہ کے مقام پر برابر بنادیاہے اور ظاہرہے کہ وہ شیء عمل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یعنی چونکہ دونوں کی ایجاد میں برابر کا وقت صرف ہواہے اس لئے دونوں کی قیمت بھی برابر ہے اور یہ تبادلہ صحیح ہے۔ (راس المال،ج1،ص44تا49)
جب یہ واضح ہو گیا کہ جنس کی قیمت عمل کے ذریعہ معین ہوتی ہے تو یہ بھی یادرکھنا چاہئے کہ بازاری قیمت کبھی کبھی اس واقعی قیمت سے مختلف ہوجایاکرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنس کی کمی کے موقع پر اس کی قیمت میں اضافہ ہوجاتاہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی قیمت ختم ہوگئی۔ایسا ہرگز نہیں ہواوہ اپنی جگہ باقی ہے اور یہی وجہ ہے کہ قیمت اپنے حدود سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی۔رومال کی قیمت ترقی کرسکتی ہے لیکن ایک موٹر کے برابر نہیں ہوسکتی جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اصلی قیمت کا معیار محفوظ ہے۔
مارکس اور یکارڈو دونوں نے اس بات کا احساس کیاہے کہ ان کا بنایاہواقانون احتکاری حالات پر منطبق نہیں ہوتاہے اس لئے کہ وہاں جنس سامنے نہیں آتی ہے اور مانگ بڑھ جاتی ہے جس کا فطری نتیجہ یہ ہوتاہے کہ قیمت ضرورت سے زیادہ ہوجاتی ہے۔
اسی طرح اس قانون کا انطباق''آثار خطوط''پر بھی نہیں ہوتا۔آپ زمانہ قدیم کے کسی نقاش کے نقشہ کو لے لیجئے وہ آج کی کتاب سے زیادہ قیمتی ہوگاحالانکہ اس پر عمل زیادہ صرف نہیں ہواہے۔
اسی لئے دونوں نے اس بات کا اعلان کردیاکہ ہمارا قانونِ قیمت دو باتوں پر موقوف ہے:
(1) جنس ذخیرہ اندوزی کا شکارنہ ہو، جتنی مانگ ہواسی مقدار میں جنس یازمین موجود ہو۔
(2) متاع اجتماعی عمل کی پیداوار ہو، شخصی فنکار یوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔
عجیب بات یہ ہے کہ جو مارکس مادی فلسفی ہونے کی حیثیت سے مقام پر پر تاریخی
حوادث سے استدلال کرتاتھا اس مقام پر پہنچ کر ایسا ارسطو نما الہٰیاتی فیلسوف بن گیا جیسے اسے آفاق سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور وہ کسی دوسرے عالم کے بارے میں گفتگو کررہا ہو۔ اس نے اپنے مطلوب پر عقلی حیثیت سے استدلال کرنا شروع کر دیا اور اس بات پر نظربھی نہیں کی کہ تاریخ اس استدلال کے خلاف شہادت دے رہی ہے۔
اس استدلال کا نتیجہ تویہ ہے کہ دوکارخانوں کی نکلی ہوئی مصنوعات میں قیمت کے اعتبار سے کوئی فرق اس وقت تک نہ ہوجب تک کہ اس پر صرف ہونے والی محنت میں اختلاف نہ ہوچاہے دونوں کے آلات اور پرزے برابر ہوں یا ان آلات ووسائل میں کوئی فرق ہو حالانکہ تاریخ اقتصاد اس بات کی شاہد ہے کہ کارخانے کی ضرورت کے مطابق جس قدر آلات زیادہ ہوں گے اسی قدر اس سے استفادہ بھی زیادہ ہوگا۔
یہی وہ بات تھی جس کے پیش نظرمارکس نے تاریخ کونظرانداز کر دیا اور عقلی حیثیت سے استدلال کرکے اپنے مطلب کوثابت کرنا چاہاتاکہ بعد میں تاریخی آثار اس کے خلاف پائے جائیں توانہیں سرمایہ داری کے سرڈال دیاجائے اور اس کی نحوست وبدبختی پر محمول کردیاجائے۔ (راس المال،ص1185)
مارکسی بنیاد پرنقدونظر
اب ہم مارکس کے قانون کا اسی کی دلیل کی روشنی میں جائزہ لینا چاہتے ہیں، مارکس نے تخت اور لباس کے تبادلہ کو دیکھ کر یہ سوال اٹھایاہے کہ تبادلہ کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں تو اس مساوات کا راز کیاہے؟اس کے بعد جواب میں عمل کو پیش کرکے اسی کو معیار
قرار دیاہے حالانکہ یہی سوال ہم اجتماعی اور انفرادی کاموں کے بارے میں بھی اٹھاسکتے ہیں او ریہ کہہ سکتے ہیں کہ ان قدیم خطی آثار کی کوئی تبادلی قیمت ہے یا نہیں؟اور اگر ہے اور اسے ایک جلد تاریخ کا مل سے بدل سکتے ہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان بھی ایک مشترک امر ہونا چاہئے جس طرح کہ تخت ولباس کے درمیا ن ایک مشترک امر تھا اگر یہ کہاجائے کہ وہ مشترک شیء عمل ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات خلاف واقع ہوگی اس لئے کہ ایک خط یا ایک رسالہ کا عمل ایک جلد کتاب سے یقیناکم ہوگااور اگریہ کہاجائے کہ وہ عمل نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہوگاکہ وہ کیاشیء ہے؟
شاید اسی ناواقفیت کا انجام تھا کہ مارکس نے اس قسم کے آثار کو اپنے قانون سے مستثنیٰ کردیا۔
ہم مارکس سے اس استثنا کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ہمارا سوال توصرف یہ ہے کہ اگریہ تبادلہ صحیح ہے تو پھر آپ کے قول کے مطابق دونوں کے درمیان ایک مشترک شیء ہونی چاہئے اور اگروہ عمل نہیں ہے تو جو شیء بھی ہے آپ اس کی نشاندہی کریں؟
اگر آپ اس کا تعین نہیں کرسکتے تو اتنا بہرحال تسلیم کریں کہ کوئی امر مشترک ایسا بھی جو انفرادی اور اجتماعی اعمال کے درمیان بھی پایاجاتاہے جس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ اسی شیء کو اصلی معیار کیوں نہیں قرار دیتے کہ قانون کی عمومیت اور شمولیت محفوظ رہے؟
ہماری اس تحقیق کا ایک واضح سا نتیجہ یہ ہے کہ عمل کے علاوہ بھی کوئی مشترک شیء ہے جو تخت ولباس اور آثار ومطبوعات کے درمیان پائی جاتی ہے لہٰذا اگر اس کا سراغ مل جائے تو اسی کو معیار قرار دینا چاہئے اور عمل کی معیاری حیثیت ساقط کر دینی چاہئے۔
قانون قیمت کے سلسلہ میں مارکس کے سامنے ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کا حل کرنا دشوار ہے اس لئے کہ اس کا یہ قانون تاریخ سے مطابقت نہیں کرتااور ظاہرہے کہ جو شیء تاریخ کے خلاف ہوتاریخ اس کی توجیہ سے معذور ہے۔
مارکسیت کی اس دشواری کو واضح کرنے کے لئے زمین کو مثال میں پیش کرتے ہیں ظاہرہے کہ تمام زمینیں ایک جیسی نہیں ہوتیں بلکہ صلاحیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں تو ہر زمین میں اتنی صلاحیت ضرورہوتی ہے کہ اس میں گندم،جو، چاول جیسی اجناس کی زراعت کرلی جائے لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض رمینیں بعض اجناس کے لئے زیادہ مناسب ہوتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عمل کی ایک ہی مقدار اگر مناسب جنس پر صرف کر دی جائے تو اس سے کہیں زیادہ غلہ پیدا ہوجائے گا جب یہی عمل غیر مناسب جنس پر صرف کیاجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھیت کے تمام غلہ کو دوسرے کھیت کے غلہ سے تبدیل کرلیں خواہ ان کی مقدار میںکسی قدرتفاوت کیوں نہ ہو صرف اس لئے کہ دونوں پر صرف ہونے والے عمل کی مقدار ایک ہے۔ظاہرہے کہ یہ کبھی نہیں ہوسکتا اور نہ سودیت دیس ہی اسے اپنے لئے پسند کر سکتاہے اس لئے کہ اس کے نتائج عالمی اقتصاد کے لئے انتہائی خطرناک ہیں۔
اور جب یہ معاملہ صحیح نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا معیار ہے جس کی بنیاد پر ان جنسوں کاتبادلہ کیاجائے جبکہ دونوں کا عمل برابر ہے۔
میرے خیال میں مارکس کا یہ بھی فریضہ تھاکہ جس طرح مختلف اعمال والے نتائج کا معیار معین کیاتھا۔مختلف صلاحیتوں کے نتائج کا معیار بھی مقرر کرتالیکن اس نے اس موضوع کو تشنہ چھوڑدیا۔
ممکن ہے کہ مارکسیت اپنے قانون کی توجیہ میں یہ کہے کہ ایک سیرروٹی اگر ایک مقام پر ایک گھنٹہ کی محنت سے پیداہوتی ہے اور دوسرے مقام پر دو گھنٹہ کی محنت سے تو ہمیں اس کا اوسط نکال کر ایک سیر کو 11/2 گھنٹہ کا نتیجہ قرار دینا چاہئے اور اسی اعتبار سے اجناس کی قیمت مقرر کرناچاہئے۔
یہیں سے زمین کی صلاحیت کا راز بھی واضح ہوجائے گا۔اچھے کھیت میں آپ کا
عمل بظاہر ایک گھنٹہ ہوگالیکن واقع کے اعتبار سے اس کی اہمیت11/2گھنٹہ کی ہوگی اسی طرح سے خراب زمینوں کا گھنٹہ 4 / 3 کے برابر ہوگا اور معاملہ کی تمام دشواریاں دور ہوجائیں گی۔
لیکن ہمارا سوال پھر یہ ہوگاکہ اچھی زمین کے ایک گھنٹہ کو11/2 گھنٹہ کس نے بنایا؟ یہ انسان کا کام تو نہیں تھا اس لئے کہ وہ معجزہ سے قاصر ہے اور طاقت کاکام بھی نہیں تھا اس لئے کہ وہ ایک گھنٹہ سے زیادہ صرف نہیں ہوئی تھی۔اس آدھے گھنٹہ کوسوائے زمین کی صلاحیت کے اور کسی طرف کی منسوب نہیں کرسکتے لہٰذا اگر اس آدھے گھنٹے کو قیمت پر اثرانداز قراردیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگاکہ زمین بھی قیمت کی تحدید میں دخیل ہے حالانکہ حساب سے خارج کرچکے ہیں اور اگر اس آدھے گھنٹہ کا قیمت پر کوئی اثرتسلیم نہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگاکہ اچھی زمین کی ایک سیرروٹی خراب زمین کی 11/2سیرروٹی سے تبدیل کرلیں اور مارکس کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔
مارکسیت کے لئے تیسرا دشوار گذار مرحلہ وہ حادثہ ہے جو ہر ملک میں پیش آتارہتا ہے اورجس سے قیمت کی کمی وزیادتی پر ایک نمایاں اثرپڑتاہے یعنی رغبت کی کمی اور زیادتی، ہم روزانہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اجتماعی رغبت جنس کی قیمت کو دوبالا کردیتی ہے اور جمہور کاا عراض جنس کو بے ارزش بنادیتاہے۔
معلوم یہ ہوتاہے کہ جنس کی قیمت میں عمل کے ساتھ ساتھ اجتماعی ضرورت کو بھی دخل ہوتاہے۔
لیکن مارکسیت اس مسئلہ سے نظربچاکراسے رسدوطلب پر محمول کرنا چاہتی ہے اس کا خیال ہے کہ قیمت کا تعلق صرف عمل سے ہوتاہے۔یہ اور بات ہے کہ جب پیداواری حالات خراب ہوجاتے ہیں اور جنس پر دوہری محنت صرف ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی دوگنی ہوجاتی ہے جس طرح کہ پیداواری حالات سازگاری کی صورت میں محنت کی کمی سے قیمت میں تخفیف ہوجاتی ہے۔
ہمیں مارکس کے اس بیان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے کہ ایسا ہوتابھی ہے اور ہوبھی سکتاہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس حادثہ کی توجیہ صرف عمل کی نیاد پر کیوں کی جاتی ہے جبکہ اس کے لئے رغبت ،ضرورت وغیرہ جیسے احتمالات بھی موجود ہیں۔اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ احتمالات باقی رہیں گے اس وقت تک کسی ایک رخ کو حتمی نہیں قرار دیاجاسکتا۔
اس مقام پر ایک بڑااہم نکتہ ہے جس سے مارکسیت نے اعراض کر لیاہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے۔بعض اعمال اچھی خاصی مہارت کے محتاج ہوتے ہیں۔اور بعض کے لئے کسی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی، مزدور کا ایک گھنٹہ انجینئر کے ایک گھنٹہ سے الگ حساب رکھتاہے۔نہر کھودنے والے کا کام بجلی کے کاریگر سے جداگانہ نوعیت رکھتاہے اس لئے کہ ایک مہارت ومشق کا طالب ہے اور دوسرا صرف مشقت کا۔
اس کے علاوہ چند مزدور کے ذاتی اوصاف بھی عمل کی نوعیت کو بدل دیاکرتے ہیں ایک انسان کو عمل سے دلچسپی ہے اور وہ کام کا ذوق رکھتاہے توا س کا گھنٹہ اور ہوگا اور اگر بددلی سے کام کرتاہے تو اس کا گھنٹہ اور ہوگا۔پھر حالات کی خوشگواری اور ناخوشگواری کی اثر اندازی بھی ناقابل انکار ہے۔
ایسے حالات میں صرف عمل کی مقدار کا حساب کرلینا اور اس کی نوعیت،کیفیت عامل کے خصوصیات واوصاف سے قطع نظرکرلینا ایک ایسی واضح غلطی ہے جس کا تدارک غیر ممکن ہے۔
یہ ضرور ہے کہ ان امور کو قیمت کی پیداوار میں دخیل مان لینے کے بعد ایک دشواری یہ پیش آئے گی کہ مقدار کو معلوم کرنے کے لئے توعمدہ سے عمدہ گھڑی ایجاد ہوجائے گی لیکن کیفیت ونوعیت وہ باطنی اور غیبی امور ہیں جن کے امتحانات کے لئے کوئی گھڑی ایجاد نہیں ہوئی اور اس کا معیار معلوم کرنا انتہائی دشوار گذار مرحلہ ہے۔
دیکھنا یہ ہے کہ مارکسیت کے پاس ان دونوں مشکلات کا کیاحل ہے اس نے
فنکاری اور سادگی میں کیا فرق کیاہے ذاتی اوصاف وکیفیات کے معلوم کرنے کے لئے کون سا آلہ ایجاد کیاہے؟
پہلی مشکل کے سلسلہ میں مارکسیت کا بیان یہ ہے کہ عمل کی دو قسمیں ہیں: بسیط اور مرکب۔
بسیط اس عمل کو کہتے ہیں جس میں صرف جسمانی ظاقت کی ضرورت ہو۔اس کے علاوہ کسی قسم کی ذہنی او رفکری صلاحیت درکار نہ ہو،جیسے مزدوری،حمالی وغیرہ۔
مرکب اس عمل کانام ہے جس کے لئے معلومات اور مہارت کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ڈاکٹری، انجینئرنگ وغیرہ۔
ظاہرہے کہ قیمت کا معیار بسیط عمل ہی کو قرار دیاجائے گا اس لئے کہ مرکب عمل بسیط سے زیادہ ہوتاہے اس کی پشت پر وہ زحمتیں بھی ہوتی ہیں جو اس کی تحصیل میں صرف ہوتی ہیں مزدور کا ایک ہفتہ انجینئر کے ایک ہفتہ کے برابر نہیں ہوسکتااس لئے کہ انجینئر کے ایک ہفتہ کے ساتھ وہ مدت بھی ضمیمہ کی جائے گی۔جو اس نے ٹریننگ کے دوران گنوائی ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ کیا اس تفرقہ سے اصل مشکل کا علاج ہوجائے گا؟ ہمارے خیال میںتو ایسا نہیں ہوگا۔
اس لئے کہ اس بیان کا لازمہ تو صرف یہ ہے کہ اگر کوئی انجینئر بیس سال تک ٹریننگ حاصل کرے اور اس کے بعد 20 سال کام کرے تو اس کی مزدوری 40 سال مزدور کے کام کے برابر ہونی چاہئے۔حالانکہ ایسا ہرگزنہیں ہے۔
واضح لفظوں میں یہ کہاجائے کہ مارکسی قانون کے لحاظ سے انجینئر کا ایک دن مزدور کے دو دن کے برابر ہوگا۔لہٰذا اس کی اجرت دو روز کے برابر ہونی چاہئے۔
آپ انصاف سے بتائیں کیادنیا کے کسی معاشرہ میں ایسا ہوتاہے،کیا کوئی صاحب عقل اسے قبول کرسکتاہے؟
حسن اتفاق کی بات ہے کہ سودیت دیس نے بھی اپنے یہاں اس قانون کو نافذ نہیں کیا ورنہ اب تک تباہی کے گھاٹ اترگیاہوتا۔
آپ روس کے حالات کاجائزہ لیں وہاں بھی انجینئر کی تنخواہ مزدور سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔حالانکہ وقت کے اعتبارسے وہ اتنا زیادہ وقت نہیں صرف کرتا۔
وہاں انجینئروں کی قلت بھی نہیں ہے کہ اسے احتکاری حالات میں داخل کرکے اس کی قیمت بڑھادی جائے۔
حقیقت امر یہ ہے کہ مارکس کا معیار قیمت کے بارے میں اتنا غلط ہے کہ اس کا انطباق ان تمام صورتوں پر ذراناممکن سا نظرآتاہے۔
دوسری مشکل یعنی مزدور کے ذاتی اوصاف کے بارے میں مارکسیت نے یہ حل پیش کیاہے کہ اوسط درجہ کے مزدور کے اعمال کو معیار قرار دیاجائے۔جیساکہ خود مارکس نے لکھاہے:
کسی شیء کی پیداوار کے لئے ضروری وقت وہی ہے جو اس عمل کے لئے ضروری ہواور اوسط درجہ کی قوت ومہارت پر ہورہاہو۔ بنابریں ہر معاشرہ میں قیمت کا تعین عمل کے وقت یا اس کے مقدار سے ہوگابلکہ اسی طرح ہر خاص چیز اپنی نوع کے اوسط درجہ سے شمار ہوگی۔ (راس المال،ج1،ص49،50)
اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ عامل کے ذاتی اوصاف اگر اسے اوسط درجہ کے افراد سے بلند کردیں تو اس کی پیداکردہ قیمت بھی زیادہ ہوجائے گی۔اس لئے کہ معیار اوسط درجہ کاعمل ہے اور اس کا عمل اپنی خصوصیات کے ا عتبار سے اوسط درجہ سے بلند ہے۔
مارکسیت کی سب سے بڑی کوتاہی یہی ہے کہ وہ انسانی عمل پر صرف مقدار کی حیثیت سے نظرڈالتی ہے اس کے علاوہ اس کی نظرمیں کوئی شیء اور نہیں سماتی اس کا خیال یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کے ذاتی حالات بھی صرف عمل کی مقدار پر اثرانداز ہوسکتے ہیں اس کے
علاوہ ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہے۔
اوسط درجہ کا آدمی ایک گھنٹہ میں ایک گز کپڑا بنے گا تو اعلیٰ درجہ کا مزدور دو گزبن دے گا۔اس کے علاوہ اس کے ان صفات کا کوئی اثر نہیں ہے۔
حالانکہ یہ بات انتہائی مہمل ہے اس لئے کہ اکثر اوقات تو ایسا ہوتاہے کہ اعلیٰ درجہ کا باذوق انسان اوسط درجہ کے انسان کے وقت کے برابر ہی کام کرتاہے اور پیداوار کی مقدار بھی برابر ہی ہوتی ہے لیکن یہ اپنے ذاتی ذوق کی بناپر اس میں ایسی خصوصیات پیدا کردیتاہے کہ اس کی قیمت بازار کے لحاظ سے کہیں زیادہ ہوجاتی ہے۔
ظاہرہے کہ ایسے وقت میں نہ عمل میں کوئی تفاوت ہے اور نہ نتیجہ میں لیکن اس کے باوجود قیمت میں تفاوت پیداہوگیاہے۔
آپ نے ملاحظہ کیاہوگاکہ اگر دونقاش ایک ہی گھنٹہ کے اندر ایک ایک نقش تیار کریں تو زیادہ باذوق نقاش کا نقش کہیں زیادہ قیمتی ہوگاحالانکہ وقت بھی ایک ہی ہے اور نقشہ بھی ایک اور بڑے نقاش کے ذوق نے مقدار میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیاہے اور یہی وجہ ہے کہ چاربدذوق مل کر بھی ویسا نقش تیار کرنے سے عاجز ہیں۔
معلوم یہ ہواکہ معیار کے موقع پر صرف عمل کی مقدار پر نظر رکھنا اور دیگر خصوصیات سے قطع نظرکرلینا ایک فاش غلطی ہے جس کا ارتکاب ذوق سلیم کے لئے غیر ممکن ہے۔
اس بیان سے یہ بھی واضح ہوگیاکہ عمل کو معیار قرار دیناہمیشہ اس دشواری سے دوچار رہے گا کہ اس کی مقدار اچھی گھڑی سے معلوم ہوجائے گی۔
لیکن اس کی باقی خصوصیات کے لئے کوئی پیمانہ نہ ہوگا۔جس کا نتیجہ یہ ہوگاکہ اس کی واقعی قیمت ہمیشہ مجہول اور نامعلوم رہے گی۔
یہی وہ مشکلات ہیں جو مارکس کے معیار کو مہملات کا درجہ دے دیتے ہیں لیکن میں اسے اس بیان میں معذور خیال کرتاہوں اس لئے کہ اس نے شروع ہی سے ایسا طریقۂ
استدلال اختیار کیاہے جس کا یہ نتیجہ ناگزیر تھا۔اس نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ تخت ولباس کے تبادلہ سے بحث کرتے ہوئے دونوں کی استعمالی قدر وقیمت کوبالکل نظراندازکر دیا۔حالانکہ قیمت کی تشکیل میں اس کو بہت زیادہ دخل ہوتاہے۔
ضرورت ہے کہ ایک ایسا امر مشترک تلاش کیاجائے جس کی بنیاد پر عمل کو معیار قرار دینے کے مفاسد بھی رفع ہوجائیں اور استعمالی منفعت کی قدر وقیمت بھی محفوظ ہوجائے۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ کہ تخت اور لباس اگرچہ اپنے استعمالی فائدوں کے اعتبار سے مختلف ہیں لیکن ان دونوں فائدوں کے درمیان ایک نفسیاتی اثرپایاجاتاہے جو واقعی حیثیت سے ان کے تبادلہ کا باعث بنتاہے اور وہ ہے اجتماعی رغبت۔
رغبت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں اس لئے تبادلہ صحیح ہے۔استعمالی فائدے کس قدر مختلف کیوں نہ ہوں ان کا کوئی اثر قیمت پر نہیں پڑتا۔
سماجی رغبت ہی وہ واقعی معیار ہے جس کی بناپر مارکسیت سے پیداہونے والے تمام مشکلات حل ہوجاتے ہیں اور نتیجہ تاریخ کے موافق برآمد ہوتاہے۔
اسی معیار کے پیش نظر کہاجاسکتاہے کہ ایک آثاری خط کا تبادلہ ایک جلد کتاب سے صرف اس لئے صحیح ہوجاتاہے کہ اجتماعی حیثیت سے قدیم خطاطی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے اور جدید مطبوعات کی طرف کم۔ورنہ عمل اور وقت کے اعتبار سے کتاب پر زیادہ وقت صرف ہوتاہے۔
استعمالی فائدے کو پیش نظررکھنے کی ضرورت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی عمل پر کئی گھنٹے کا وقت صرف کردیاجائے لیکن ایسا فائدہ نہ حاصل ہوسکے جس سے اجتماعی رغبت پیداہوتو کوئی شخص اس کی خریداری کے لئے تیار نہ ہوگا۔اگرچہ عمل کی کافی مقدار صرف ہوگئی ہے۔
مارکس ا س مشکل کا احساس رکھتاہے لیکن اپنے بنائے ہوئے قانون کی بناپر اسے حل کرنے سے معذور ہے۔وہ استعمالی فائدے کو پہلے ہی نظرانداز کر چکاہے۔
ہمارے قانون کی بناپر اس مشکل کا حل بھی واضح ہوجاتاہے کہ اجتماعی رغبت کا منشا استعمالی فائدہ ہے اور جب یہ فائدہ ہی نہیں ہوگا تو رغبت کیا ہوگی اور جب رغبت نہ ہوگی تو قیمت بھی نہیں لگ سکے گی۔اس لئے کہ قیمت کا معیار رغبت ہے عمل نہیں ہے۔
یہ بھی یادرکھنے کی ضروت ہے کہ رغبت کی بنیاد استعمالی فائدہ پر ضرورہے لیکن اس میں جمود نہیں ہے بلکہ اپنے مخصوص اسباب کی بناپر کمی زیادتی رہتی ہے جتنا زیادہ فائدہ ہوگا اتنی زیادہ رغبت ہوگی۔جتنی قلیل جنس ہوگی اتنی زیادہ رغبت ہوگی۔ اور ظاہرہے کہ جس قدر رغبت زیادہ ہوتی جائے گی اسی قدروقیمت میں اضافہ ہوتاجائے گا اور رسد وطلب بھی صاف ہوجائے گا۔
سرمایہ داری پر مارکسیت کی تنقید
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سرمایہ داری پر مارکسیت کے اعتراضات نقل کرکے ان کو ردکرنے سے ہمار مقصود سرمایہ داری کی حمایت ہے اس لئے کہ وہ اسلام سے ہم آہنگ ہے اس میں بھی سرمایہ دارانہ منافع کا جواز ہے اور اسلام میں بھی ۔اس میں بھی انفرادی ملکیت کا اعتراف ہے اور اسلام میں بھی۔
حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔اسلام ہماری نظرمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دستور زندگی ہے۔اس کے اپنے اصول وقوانین ہیں جنہیں نہ سرمایہ داری کے مفاسد سے کوئی تعلق ہے اور نہ اشتراکیت کے محاسن سے۔
ہمار امقصود صرف یہ ہے کہ مارکس نے اپنی تنقید میں صحیح طریقہ سے نبض پر ہاتھ نہیں رکھااور نہ مرض کی واقعی تشخیص کی ہے اس کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سرمایہ داری کے جملہ مفاسد کا سرچشمہ انفرادی ملکیت ہے۔
ہمارا فرض ہے کہ مرض کی صحیح تشخیص کرکے شخصی ملکیت کے دامن سے اس دھبہ کو مٹادیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی مدعا نہیں ہے۔
ہم تو ان مسلم قلم کاروں کو بھی غلط انداز سمجھتے ہیں جو اشتراکیت کی عداوت میں مغرب کی سرمایہ داری کی حمایت کرنے لگتے ہیں اور اپنی دانست میں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس طرح دین اسلام کی خدمت کررہے ہیں۔
صاحب نظرکا فریضہ ہے کہ اقتصادیات پر قلم اٹھانے سے پہلے دوباتوں پر نظرکر لیاکریں:
(1) مسلم قلمکار کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ مغربی سرمایہ داری کی حمایت کرے اور اس پر وارد ہونے والے صحیح اعتراضات کوبھی غلط تصور کرکے ٹھکرادے صرف اس لئے کہ اسلام بھی انفرادی ملکیت کا حامی ہے
(2) سرمایہ دارمعاشرہ کی موجودہ حالت کی ابتری کا کوئی تعلق شخصی ملکیت سے نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس جس نظام میں ایسی ملکیت کا تصورہووہاں یہ مفاسد ضرور پائے جائیں۔ جیساکہ مارکسیت نے خیال کیاہے اور فقر وفاقہ، احتکارو استعمار ، بے کاری اور بے عاری سب کو اسی ملکیت کا نتیجہ قرار دے دیاہے۔
مارکسیت کے اس خیال پر ہمارے دو بنیادی اعتراضات ہیں:
(1) مارکسیت نے سرمایہ دار نظام کے سیاسی، اقتصادی اور فکری اصول پر غور کئے بغیر اسے شخصی ملکیت کا مترادف قراردے کر اس کی ساری خرابیوں کو اسی ملکیت کے سرڈال دیاجو کسی طرح بھی روا نہ تھا۔
(2) سرمایہ داری کے ارتقاء وتناقض کے بارے میں اس کے وضع کردہ اصول وقوانین غلط اور خلاف واقع ہیں۔
سرمایہ داری کی سب سے اہم نقیض جس پر اس طبقاتی نزاع کی بنیاد ہے جس کے نتیجہ میں سرمایہ دار نظام کا خاتمہ ہوگااور اشتراکیت وجود میں آئے گی۔مارکس کی نظرمیں وہ ''زائد قیمت''ہے جسے سرمایہ دار مزدور سے غصب کرلیتاہے۔
اس مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ ہر شیء کی قیمت اس کے اندر صرف شدہ عمل اور محنت سے لگائی جاتی ہے۔
اگرکوئی شخص ایک دینار کی لکڑی خرید کر اس کا تخت بنوائے اور پھراسے دو دینار میں فروخت کردے توظاہرہے کہ اس ایک دینار کا اضافہ صرف عمل کی بناپر ہوگا جو مزدور نے اس میں صرف کیاہے۔
تقاضائے انصاف تویہ ہے کہ سرمایہ دار وہ پورا دینار مزدور کے حوالے کر دے اس لئے کہ یہ اسی کے عمل کا نتیجہ ہے اس طرح کسی قسم کا ظلم بھی نہ ہوگا،سرمایہ دار کا دیناربھی محفوظ رہے گا اور مزدور کا دینار بھی اسے مل جائے گا۔
لیکن ظاہرہے کہ سرمایہ دار ایسا نہیں کرتاوہ مزدور کو اجرت دے کر روانہ کردیتاہے اور اس کو اپنی پوری ملکیت نہیں ملتی بلکہ اس میں سے ایک حصہ غصب ہوجاتاہے یہی حصہ ہے جس کو اصطلاحی اعتبا رسے''زائد قیمت''کہاجاتاہے۔اس لئے کہ یہ وہ قیمت ہے جسے سرمایہ دار نے اپنے حق سے زیادہ لے لیاہے۔دوسرے لفظوں میں یوں کہاجائے کہ مزدور قیمت زیادہ پیدا کرتاہے اور اجرت اسے کم ہی ملتی ہے جس کے نتیجہ میں چھوٹی چھوٹی اجرت جمع کرکے سرمایہ دار ایک ثروت کا مالک ہوجاتاہے اور مزدور اپنے حق سے محروم ہوجاتا ہے۔
مارکس فائدہ کے سلسلہ میں اپنی اس تشریح کو پوری سرمایہ داری کا راز خیال کرتاہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جس وقت پیداوار کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ
فائدہ کا کوئی موقع نظرنہیں آتا جس سے انسان سرمایہ دار بن سکے۔مالک پہلے تاجر سے تمام آلات خریدتاہے اس کے بعد مزدور سے اس کی طاقتیں خریدتاہے۔ظاہرہے کہ استعمالی منفعت کے اعتبار سے یہ معاملہ دونوں کے حق میں برابر ہے اس لئے کہ طرفین نے ایک شیء دی اور اس کے مقابلہ میں دوسری شیء لی لیکن تبادلی قیمت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ تبادلہ عام طور سے برابر کی چیزوں میں ہوتاہے اور واضح سی بات ہے کہ معاملہ برابر کاہوا تو فائدہ کا کوئی سوال ہی پیدانہ ہوتا سوال یہ ہے کہ پھر فائدہ کہاں سے آگیا ۔
اس کے متعلق چند احتمالات دیئے جاسکتے ہیں۔ایک بات تویہ کہی جاسکتی ہے کہ فائدہ فروخت کرنے والے کی طرف سے پیداہوتاہے اس لئے کہ جب وہ اپنی جنس کو زیادہ قیمت پر فروخت کرے گا تو اسے فائدہ ضرور حاصل ہوگالیکن یہ بات مارکس کی نظرمیں غلط ہے اس لئے کہ یہ فائدہ اس دن ختم ہوجائے گا جب اس بیچنے والے کو جنس خریدنا پڑے گی اور بائع مشتری کی شکل اختیار کرلے گا۔
دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ فائدہ پیداوار والوں کی طرف سے ہو۔اس وقت جب ضرورت مند افرد جنس کو اس سے زیادہ قیمت پر خریدلیں۔لیکن مارکس کی نظرمیں یہ بھی غیر صحیح ہے اس لئے کہ آج کا پیداوار والا انسان کل ضرورت مند ہوسکتاہے لہٰذا وہ تمام فائدہ کل ختم ہوجائے گا جب طرفین کی حیثیت بدل جائے گی۔
مقصد یہ ہے کہ اس فائدہ کا راز ازیادہ قیمت پر بیچنے میں مضمر ہے اور نہ وقت ضرورت زیادہ قیمت پر خریدنے میں بلکہ اس کا رازصرف یہ ہے کہ مالک مزدور سے دس گھنٹہ کاکام لے کر اس پورے وقت کی اجرت نہیں دیتا۔
صرف اس خیال کی بناپر کہ ہم نے عمل نہیں خریداہے بلکہ وہ طاقت خریدی ہے جس کی بناپر یہ عمل ظہور میں آیاہے اور ظاہرہے کہ طاقت کے عوض میں اتنا مال دے دینا کافی ہے جس سے آئندہ کام کرنے کے لئے طاقت محفوظ رہے پوری قیمت کا دینا ضروری نہیں
ہے اگرچہ وہ اسی کے عمل سے پیداہوئی ہے۔
مارکس نے اپنے اس بیان سے یہ واضح کر دیاہے کہ سرمایہ دار مزدور سے اس کی طاقت خریدتاہے اور اسی کی قیمت ادا کرتاہے۔حالانکہ جنس کو تحویل لیتے وقت اسے عمل کی صورت میں وصول کرتاہے۔
ظاہرہے کہ اگر وہ عمل کو لے کر اس سے پیداشدہ پوری قیمت کو مزدور کے حوالے کردے تو کوئی نزاع ہی واقع نہ ہو لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا اس لئے سرمایہ دار اور مزدور کی طبقاتی جنگ شروع ہوجاتی ہے۔
کھلی ہوئی بات ہے کہ مارکس کا یہ پورا بیان اس کے مقرر کئے ہوئے معیار پر مبنی ہے۔اس لئے کہ وہ قیمت کو عمل کے اعتبار سے معین کرتاہے اور اسی لئے یہ دعویٰ کرتاہے کہ سرمایہ دار مزدورسے اس کی پیداکردہ قیمت کا ایک حصہ غصب کرلیتاہے۔
لہٰذا اگر یہ ثابت ہوجائے کہ قیمت کا معیار صرف عمل نہیں ہے بلکہ اس میں اور عناصر بھی شریک ہیں تو مارکس کی پوری بنیاد منہدم ہوجائے گی اور اس کا نظریہ باطل محض ہوکر رہ جائے گا۔
ہم نے گذشتہ بحث میں یہ واضح کردیاہے کہ قیمت کا عمل معیار نہیں ہے بلکہ ایک سیکالوجی صفت ہے۔جس میں پورا معاشرہ شریک ہوتاہے اور وہ ہے رغبت۔لہٰذااس زائد قیمت کی تفسیر کے لئے ہمیں غصب وسلب کے داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم خام مواد کی اہمیت کو پیش نظررکھ کر اس کے راز کو واضح کر سکتے ہیں۔
یادرکھئے کہ جو خام مواد بھی فطری اعتبار سے قدرے ندرت رکھتاہے جیسے لکڑی کہ وہ ہواکہ نسبت سے کمیاب ہے اس کی خود بھی ایک قیمت ہوتی ہے خواہ اس میں کوئی انسانی عمل شریک ہواہویانہ ہواہو اور یہی وہ بات ہے جسے مارکس نے ٹھکرا کر یہ طے کر دیاہے کہ جب تک عمل شریک نہ ہوجائے خام مواد کی کوئی قیمت ہی نہی ہوتی ہے۔
ہم یہ تسلیم کرتے ہیںکہ خام مواد تک ظاہرنہ ہوجائے زیر زمین اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور جب انسانی محنت سے سامنے آجاتاہے تو اس کی ایک قدروقیمت پیداہوجاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پوری قیمت عمل کے زور پر پیداہوئی ہے۔
اس لئے کہ اگر مارکس کو یہ کہنے کا حق ہوگاتو ہم بھی یہ کہیں گے کہ عمل جب تک کسی خام مواد سے معلق نہ ہو اس وقت تک اس کی بھی کوئی قدر وقیمت نہیں ہوتی۔تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم عمل کی اہمیت سے بھی انکار کر دیں۔ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارافرض ہے کہ ہم دونوں عناصر کی اہمیت کو پیش نظررکھ کر یہ دیکھیں کہ جس طرح زیرزمین سونے کی کوئی وقعت نہیں ہے اسی طرح بالائے زمین مہمل مواد میں صرف ہونے والے عمل کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔دونوں اپنا صحیح مرتبہ اسی وقت پاسکتے ہیں جب ایک دوسرے سے منظم ہوجائیں اور اپنے صحیح انداز میں معاشرہ کے سامنے آئیں۔
اور جب یہ با ت واضح ہوگئی کہ نفسیاتی معیار یعنی عمومی رغبت کے اعتبار سے عمل کے ساتھ خام مواد کو بھی قیمت کی ایجادمیں دخل ہوتاہے تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تمام عناصر کو پیش نظررکھیں اور یہ سمجھیں کہ قیمت صرف عمل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس میں زمین کا بھی دخل ہوتاہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی عمل جب باصلاحیت زمین پر صرف ہوجاتاہے تو زیادہ قیمت پیداہوجاتی ہے اور جب بے صلاحیت اراضیات پر لگ جاتاہے تو کم قیمت وجود میں آتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کی تشکیل میں زمین کا بھی حصہ ہے اور جب یہ ثابت ہوگیاکہ تمام قیمت عمل کی پیداوار نہیں ہے تو پھر یہ کہنا صحیح نہ ہوگاکہ سرمایہ دار کا فائدہ مزدور سے چرایاہواہوتاہے بلکہ اسے زمین کی صلاحیت یا خام مواد کی طرف بھی منسوب کرسکتے ہیں۔
آپ یہ سوال نہ کریں کہ اس عالم طبیعت سے حاصل شدہ قیمت کا مالک کون ہے مزدور یاکوئی اور۔
اس لئے کہ یہ بات ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ہم تو صرف اتنا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ فائدوں کی تفسیر کے لئے مزدور کے حقوق کا تذکرہ کوئی ضروری شیء نہیں ہے بلکہ اس کی توجیہ اس کے علاوہ دوسرے اسباب کی بناپر بھی ہوسکتی ہے۔
یہ تو صرف مارکس کے نظریہ کی مجبوری تھی کہ وہ مزدور کے حقوق کی زبردستی حمایت کرے ورنہ عمومی رغبت کے معیار پر یہ توجیہ مہمل ہے اور اس کے علاوہ دیگر توجیہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
اس مقام پر ایک اور شیء بھی قابل توجہ تھی جسے مارکس نے نظرانداز کر دیاہے اور وہ ہے قیمت کی وہ مقدار جو کارخانہ کے مالک کی تنظیمی صلاحیتوں سے پیداہوتی ہے۔
مارکس کو چاہئے تھاکہ اپنے نظریہ کی بناپر اس عمل کی بھی ایک قیمت لگاتااور سرمایہ دار کے تمام فائدوں کو لوٹ مار پر محمول نہ کرتالیکن اس نے بنیاد ہی ایسی قائم کی تھی جس کی بناپراتنے اہم کام سے بھی غفلت کرنا پڑی اور اس طرح مزدوروں،آلات خام مواد، درآمد، برآمد جیسے تمام اہم کاموں کی اہمیت کا انکار کرناپڑا۔
اور جب ہم نے یہ واضح کردیاہے کہ مارکس کا قانون قیمت اور نظریۂ''قیمت زائد'' دونوں باطل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہواکہ طبقات میں قائم ہونے والی داخلی نزاع بھی بے بنیاد ہوگئی اور مارکسی تحقیق کی پوری عمارت مسمار ہوگئی لیکن تاہم اس تفصیل کی طرف ایک مختصر اشارہ ضروری ہے۔
یادرکھئے مارکس کی نظرمیں دوقسم کے تناقض ہیں۔ایک مالک اور مزدور کا تناقض۔
ایک طاقت اور تناقض۔
مالک اور مزدور کے تنازع کا سبب یہ ہے کہ مالک مزدور کی پیداکردہ قیمت کا ایک حصہ مارلیتاہے اور اسے اس کا پورا حق نہیں دیتا۔اس بنیادکے باطل ہونے کا رازیہ ہے کہ قیمت کا تمام تر تعلق عمل سے نہیں ہے۔
لہٰذا اس حصہ کا مزدور کی طرف منسوب ہونا ہی ثابت نہیں ہے کہ مزید کسی غصب سلب یالوٹ مار کا سوال پیداہو۔
یہ صحیح ہے کہ مالک کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ مزدوری کم ہواور مزدور کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ مزدوری زیادہ ہو اور یہ بھی صحیح ہے کہ ایک کے فائدہ سے دوسرے کا نقصان ہوگا اور اس طرح دونون میں ایک قسم کی کشاکش ہوگی لیکن یادرکئے کہ اسے اس طبقاتی نزاع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جسے مارکسیت کی اصلاح میں داخلی تناقض کہتے ہیں بلکہ یہ مصالح کا اختلاف ہے جو دکاندار اور خریدار کے درمیان بھی ہوتاہے اور فنکار وغیر فنکار کے درمیان بھی۔
اول الذکر کا مطلوب یہ ہوتاہے کہ قیمت یا اجرت زیادہ ہواور آخر الذکر کا مقصد یہ ہوتاہے کہ قیمت کم یااجرت مساوی ہو۔
ظاہر ہے کہ اس اختلاف کو کسی مارکسی نظریہ کے انسان نے داخلی تناقض یا طبقاتی نزاع سے تعبیر نہیں کیا اور نہ کسی کو اس بات کا حق ہی پہنچتاہے۔
طاقت اور عمل کے تناقض کا سبب یہ ہے کہ مالک مزدور سے اس کی طاقت خریدتا ہے اور پھر وقت تحویل عمل وصول کرتاہے جس کی بناپر ایک باہمی طبقاتی نزاع پیداہوجاتی ہے۔
طاقت کے خریدنے کے سلسلہ میں مارکسیت کا فلسفہ یہ ہے کہ مزدور کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک عمل اور ایک اس کی طاقت۔
ظاہر ہے کہ عمل خریداری کے قابل نہیں ہے اس لئے کہ خریداری کے لئے قیمت کا تعین ضروری ہے اور قیمت کا تعین عمل سے ہواکرتاہے ۔لہٰذابراہ راست عمل کی خریداری غیر ممکن ہے اور جب عمل کسی معیار کے نہ ہونے کی بناپر خریداری کے قابل نہ رہاتو اب خرید و فروخت اس طاقت میں منحصر ہوگئی جو اس کی پشت پر کارفرماہے۔
اسلامی اقتصادیات سے باخبرافراد جانتے ہیں کہ وہ مارکس کے اس تجربہ کا پورے
طور پر مخالف ہے اس کی نظرمیں مزدور سے نہ اس کا عمل خریداجاتاہے اور نہ اس کی طاقت بلکہ خریدوفروخت کا تمام تر تعلق اس منفعت سے ہوتاہے جو عمل کے نتیجہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے مثال کے طورپریوں سمجھ لیں کہ اگر لکڑی کا مالک نجار سے تخت بنواکراسے اجرت دے تو اس اجرت کا تعلق نہ اس کے عمل سے ہوگا اور نہ اس کی طاقت سے بلکہ اس کا پورا پورا تعلق اس کیفیت اور ہیئت سے ہوگا جو نجار کے عمل کے نتیجہ میں ان لکڑیوں میں ظاہر ہوئی ہے یعنی صورت تخت اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہیئت نہ عمل سے تعلق ہے اور نہ طاقت سے بلکہ اس کا کوئی تعلق انسانی اجزاء سے بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستقل شیء ہے جس کی قیمت نفسیاتی معیار یعنی عمومی رغبت کی بناپر لگائی جائے گی جیساکہ سابق میں واضح کیا جاچکاہے۔
(غنیتہ الطالب فی حاشیہ المکاسب،ص16)
اس مقام پر یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ قیمت کی تشکیل میں اگرچہ منفعت اور خام مواد دونوں کا دخل ہوتاہے لیکن اس کے باوجود دونوں میں ایک مختصر سافرق بھی ہے اور وہ یہ کہ منفعت ایک اختیاری کام ہے اس لئے انسان اس بات پر قادر ہے کہ اس منفعت میں قدرت پیداکرکے اس کی قیمت بڑھادے جیساکہ عام طور پر ہر طبقہ کی یونین کی طرف سے ہوتاہے اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت قیمت کا اضافہ سیاسی بنیاد پر ہوگیاہے۔
حالانکہ ایساکچھ نہیں ہوتا۔اس کا راز بھی اسی عمومی رغبت میں پوشیدہ ہوتاہے سیاسی مصالح کا کام صرف یہ ہوتاہے کہ جنس کو نادرا لوجودبنادیں۔اس کے بعدرغبت کا زیادہ ہوجانا تو ایک فطری اور لازمی قانون ہے۔
سرمایہ داری کے تجربے کے سلسلہ میں مارکس کے بنیادی نقطہ کی تحلیل کرکے یہ بتایا جاچکاہے کہ''زائد قیمت کی مارکسی تفسیر جس پر اس کی نظر میں پورے نظام کی بنیاد ہے ایک بے بنیاد شیء ہے۔''
مناسب معلوم ہوتاہے کہ مارکسیت کے دیگر مراحل پر بھی ایک نظرکرلی جائے
تاکہ بحث کے خاتمہ سے پہلے ہی مارکسیت کی پوری حقیقت طشت ازبام ہوجائے۔
مارکسیت نے''قیمت''اور''قیمت زائد''کے بارے میں اپنے قوانین مقرر کرنے کے بعد ان سے استنتاج شروع کیا اور یہ بیان کیاکہ ان قوانین کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوگاکہ معاشرہ میںایک طبقاتی نزاع قائم ہوجائے گی۔ایک طرف وہ مالک ہوگاجو مزدور کی پیداکردہ قیمت کا ایک حصہ غصب کررہاہوگا اور دوسری طرف مزدور ہوگا جس کے حقوق پامال ہورہے ہوں گے۔نتیجہ یہ ہوگاکہ یہ کشمکش بڑھتی جائے گی اور آخر کار معاشرہ انحطاط کی اس منزل پر پہنچ جائے گا اور جنگ اتنی شدید ہوجائے گی کہ موجودہ نظام کو کرسی زعامت سے دست بردار ہوجانا پڑے گا اور جدید نظام کے لئے راستہ ہموار ہوجائے گا۔
دوسرا نتیجہ ہوگا''قلت فائدہ''اس لئے کہ جب سرمایہ داروں میں باہمی مقابلہ ہوگا اور ہر شخص اپنے کارخانے کو ترقی دینے کے لئے نئے آلات خریدے گا تو اس کا واضح اثر یہ ہوگاکہ فائدہ کا زیادہ حصہ دوبارہ سرمایہ بنادیاجائے گا اور فائدہ کی مقدار کم ہوجائے گی اس لئے کہ فائدہ عمل کا تابع ہوتاہے اور جب آلات زیادہ ہوجائیں گے تو فائدہ کی مقدار کم ہوجائے گی اور پھر عمل بھی کم ہوجائے گا۔
اب یاتو مزدوروں سے مقررہ قیمت پر زیادہ کام لیاجائے گا یا ان کی اجرت میں کمی کر دی جائے گی اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں اس طبقاتی جنگ کے شعلوں کو تیز تر کر دینے کیلئے کافی ہیں جس کے بعد سرمایہ دار کے خاتمہ کے امکانات قوی تر ہوجائیں گے۔
تیسرا نتیجہ ہوگا''عمومی فقر وفاقہ''اس لئے کہ جب نئے نئے آلات برسرکار آجائیں گے تو مزدوروں کی ضرورت کم ہوجائے گی ان کی جگہ آلات سے کام لیاجائے گا اور انجام یہ ہوگاکہ مزدورطبقہ عمومی فقر وفاقہ میں مبتلا ہوجائے گا اور طبقاتی جنگ کے عوامل و موثرات میں کچھ اور بھی اضافہ ہوجائے گا۔
چوتھا اور پانچواں نتیجہ احتکارواستعمار کی شکل میں ظاہرہوگا۔اس لئے کہ جب ملک
کی پبلک عمومی تندرستی میں مبتلا ہوجائے گی تو ان اجناس کے خریدار کم ہوجائیں گے اور سرمایہ دار کو ضرورت ہوگی کہ اپنے مال کا احتکار کرے اور خارج حدود مملکت دوسرے بازاروں پر قبضہ کرے جسے استعماری حرکت کہتے ہیں اور یہ تمام باتیں وہ ہوں گی جو انقلاب کے اسباب مہیاکریں گی اور مزدور کے ہاتھوں سرمایہ دار نظام کا خاتمہ ہوگا۔
مارکسیت کے اس استنتاج کو نقل کرنے کے بعد ضرورت محسوس ہورہی ہے کہ ان نتائج کی بنیادوں کو واضح کرکے ان کی حقیقت کو بے نقاب کیاجائے۔
ظاہر ہے کہ پہلے نتیجہ کاتمام تر تعلق قانون قیمت سے ہے۔اگریہ تسلیم ہوجائے گا کہ قیمت کا معیار صرف عمل ہی ہے تو یہ کہاجاسکتاہے کہ مالک مزدور کی پیداکردہ قیمت میں سے ایک حصہ سرقہ کرلیتاہے۔
لیکن واضح ہے ہم نے اس معیار کو باطل کر دیاہے اور ہماری نظرمیں اس نتیجہ کی کوئی وقعت نہیں ہے۔
دوسرا نتیجہ بھی اسی قانون کی ایک فرع ہے اس میں بھی یہی فرض کیاگیاہے کہ قیمت عمل سے پیداہوتی ہے اورجب آلات کی زیادتی سے عمل کم ہوجائے گاتو قیمت بھی کم ہوجائے گی اورسرمایہ دار کو بقدر ضرورت فائدہ حاصل نہیں ہوسکے گا جس کا خمیازہ مزدور کو بھگتنا پڑے گا۔
ظاہر ہے کہ جب یہ بنیاد ہی ختم کر دی گئی ہے تو اب اس نتیجہ پر بحث کرنا عبث اور مہمل ہے۔
تیسرا نتیجہ مارکس کی اس تقلید کا اثر ہے جسے اس نے ریکارڈو سے حاصل کرکے اس پر اپنی تحقیقات کا اضافہ کیاہے ،ریکارڈو نے مزدور اور آلات کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے یہ بیان کیاہے کہ آلات کی فراوانی مزدور کے حق میں ہمیشہ مضر ہواکرتی ہے اس لئے کہ اس طرح مزدور کی ضرورت کم ہوجاتی ہے اور وہ تنگ دستی کاشکار ہوجاتاہے۔مارکس نے
اس تحقیق کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایک نکتہ کا اضافہ کردیاہے کہ آلات کی فراوانی سے فقط مزدور کی کمی ہی نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرا نقصان یہ بھی ہوگاکہ آلات کے باعث بڑے سے بڑا کام عورتیں اور بچے بھی کرنے لگیں گے اور اس طرح قومی اور ماہر مزدور بیکار ہوجائیں گے ۔جوان کی موت کا پیش خیمہ ہوگا۔
مارکس تو اسپنی تحقیقات نذر کا غذ کرکے رخصت ہوگیالیکن جب اس کے پرستاروں نے یہ دیکھاکہ یورپ اور امریکہ کے سرمایہ دار ممالک میں یہ تنگ دستی، یہ فقر وفاقہ نہیں ہے تو وہ متحیر ہوگئے اور انہوں نے اس امر کی ضرورت محسوس کی کہ مارکس کے کلام کی تاویل کی جائے چنانچہ یہ کہاگیاکہ لوگ اگرچہ مستقل طور پر مطمئن نظرآتے ہیں لیکن سرمایہ داروں کے مقابلہ میں انہیں تنگ دست اور فقیرہی کہاجائے گا اور یہ نسبت یوں ہی بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ آخری نقطہ پر پہنچ جائے۔
حقیقت یہ ہے کہ مارکسیت کی یہ تاویل اسی غلط بنیادکی بناپر ہے جس کی طرف ہم نے متعددباراشارہ کیاہے کہ مارکس نے اپنے بیانات میں انسانی اقتصادیات کو اس کے اجتماعیات کے ساتھ بالکل مخلوط کردیاہے اور اس طرح ایک کا عذاب دوسرے کے سر ڈال دیاہے ورنہ ہر صاحب عقل وانصاف سمجھ سکتاہے کہ فقروفاقہ کا ایک مفہوم ہے جو انسان کی ذاتی پریشانی سے پیداہوتاہے اسے کسی دوسرے شخص کی مالی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ایک شخص اپنے حالات کے اعتبار سے مطمئن زندگی بسر کررہاہے تو اسے فقیر نہیں کہاجا سکتا خواہ اس کی مالیت اور آمدنی ہزاروں آدمیوں سے کم ہو۔
یہ فقراور یہ تنگ دستی اجتماعی اعتبار سے تو فرض کی جاسکتی ہے لیکن اقتصادیات میں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے مارکس چونکہ تمام عالم کو اقتصادی بناناچاہتاہے اس لئے وہ اپنے کو اس قسم کے بیانات پرمجبور پارہاہے۔
بہرحال اب یہ سوال رہ جائے گا کہ یہ عمومی تنگ دستی کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور
اس کا سرچشمہ کیاہے؟اس کے متعلق یادرکھئے کہ اس کا تعلق انفرادی ملکیت سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب سرمایہ دارانہ منافع کی وہ آزادی ہے جوکسی محدودیت اور پابندی سے دوچار نہیں ہوئی۔نہ اس میں باہمی تعاون کا کوئی سوال ہے اور نہ پست طبقہ کی کفالت کا، ورنہ اگر کوئی نظام انفرادی ملکیت کے ساتھ اس قسم کے اجتماعی قوانین کا بھی حامل ہوتو اس میں اس قسم کی خرابیاں نہیں پیداہوسکتیں۔
چوتھا نتیجہ ہے کہ استعمار، مارکسیت نے اپنی عادت کے مطابق اسے بھی اقتصادیات سے مربوط کرتے ہوئے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ شخصی ملکیت کے طفیل میں جب سرمایہ داری آخری نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی ہے تو اس کے واسطے ملکی بازار ناکافی ہوجاتے ہیں اور اسے غیر ملکی بازاروں پرقبضہ جمانے کی فکر ہوتی ہے اور اسی غاصبانہ حرکت کا نام استعمار ہے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ مارکس کا یہ بیان بھی خلاف واقع ہے۔اگر استعمارکا تعلق سرمایہ داری کی ترقی سے ہوتاتو اس کا وجود صرف ان ممالک میں ہوتا جہاں سرمایہ داری آخری منزل پرہو، حالانکہ تاریخ نے ہمیں یہ بتایاہے کہ استعمار سرمایہ داری کے وجود کے ساتھ چلتاہے وہ اس کی ترقی کا انتظار نہیں کرتا۔چنانچہ آپ ملاحظہ کریں گے یورپ میںسرمایہ داری کے آتے ہی استعمار کی فکر شروع ہوگئی۔برطانیہ نے ہندوستان، برما، جنوبی افریقہ، مصر، سوڈان وغیرہ پر قبضہ جمایا، فرانس نے ہند چینی، جزائر،مراکش، تونس، مڈغاسکر وغیرہ کو لیا، جرمنی ے مغربی افریقہ اور جزائرباسفیک پر چھاپہ مارا، اٹلی نے غربی طرابلس اور صومال پر اپنا رنگ جمایا، بلجیک نے کانگو، روس نے ایشاء کے بعض حصے اور ہالینڈ نے جزائر ہند کو اپنے استعمارمیں داخل کرلیا۔
کیا ان حالات کے باوجود بھی مارکس کی تفسیر کو قبول کیاجاسکتاہے؟نہیں ہرگز نہیں۔ استعمار کا تمام ترتعلق معاشرہ کے اخلاقی اور روحانی انحطاط سے ہوتاہے جس معاشرہ کی نظرمیں مادہ ہی مادہ ہوتاہے وہ اپنی اس مادی ترقی کے استحصال کے لئے اس قسم کے
ناجائز اقدامات کیاکرتاہے۔اگرکوئی ایسا نظام تلاش کرلیاجائے جس میں انفرادی ملکیت کے ساتھ اخلاقی اقدارا اور روحانی افکار کا بھی لحاظ ہوتوا س میں اس قسم کے اقدامات کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔
پانچواں نتیجہ ہے احتکار، ماکسیت نے اسے بھی انفرادی ملکیت کا نتیجہ قرار دیاہے کہ جب ملک میں فقر وفاقہ عام ہوجائے گا اور لوگ بقدر ضرورت قیمت نہ دے سکیں گے تو سرمایہ دار اپنے مال کا ذخیرہ کرے گا اور اس طرح لوگ بھوک سے ہلاک ہوجائیں گے۔
حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے احتکار اور ذخیرہ اندوزی کو انفرادی ملکیت سے کیاتعلق ہے، یہ ملکیت تو صرف انسان کو مالدار بناتی ہے،احتکار کی فکر تو اس وقت پیداہوسکتی ہے جب اس کی یہ ثروت مندی اور مالداری بالکل ہی مطلق العنان ہو اور اس پر کسی قسم کی قانونی اورا خلاقی پابند ی نہ ہو۔
لیکن اگر نظام ایسا ہوجس میں انفرادی ملکیت کے ساتھ بڑھتی ہوئی سرمایہ داری کے روکنے کے قوانین بھی ہوں تو پھر اس نظام میں احتکار ااور ذخیرہ اندوزی کا تصور غلط ہوگا۔
مقصد یہ ہے کہ مارکسیت کے بیان کردہ مفاسد کا کوئی تعلق انفرادی ملکیت سے نہیں ہے بلکہ اس کے اسباب وعوامل کچھ اور ہی ہیں لہٰذا اس ملکیت سے بدظنی خلاف قانون ہے۔
مارکسی مذاہب
تمہید
ابتدائے کتاب میں ہم یہ کہہ آئے ہیں کہ اقتصادی مذہب اس مکمل تنظیم اور دستور زندگی کا نام ہے جس کے انطباق سے معاشرہ کی اقتصادی حالت سنور سکے اور وہ خیر و برکت سے ہم آغوش ہوسکے اور علم الاقتصاد اس طریقۂ تحقیق کا نام ہے جس کے ذریعہ ان فطری قوانین کا انکشاف کیاجائے جو عالم طبیعت پر حکومت کررہے ہیں۔ظاہرہے کہ اس تقسیم کی بناپر مذہب دعوت عمل کا نام ہے اور علم انکشاف حقیقت کا، مذہب ایک تخلیقی عنصر ہے اور علم ایک تحقیقی میدان۔
یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابتدائے مارکسیت کے بارے میں تاریخی مادیت کو اس کی تنظیمات سے الگ کر دیاتھا کہ تاریخی مادیت پیداوار کے فطری تکامل اور تاریخی ارتقاء سے بحث کرتی ہے اور مذہب انسانیت کو ان تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتاہے مادیت محقق ومفکر ہے اور مذہب داعی ومبشر۔
لیکن اس سے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ مارکسی تنظیمات کو مادیت تاریخ سے کوئی ربط نہیں ہے بلکہ یہ مذاہب درحقیقت اسی مادیت کے فطری نتائج ہیں جو جدلی قوانین کی بناپر
مستقبل میں رونما ہوں گے۔ان دونوں میں ایک بنیادی اتحاد ہے جس کی بناپر ایک دوسرے کی تعبیر اور اس کا ترجمان کہہ سکتے ہیں،اشتراکیت واشتمالیت در حقیقت اسی تاریخی ارادے کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔جو مادیت کی روشنی میں حتمی ہوچکاہے اور جس پر عمل درآمد تاریخ کی ایک اہم ضرورت ہے۔
شائد اسی باطنی اتحاد کا اثر تھا کہ مارکس نے اپنی اشتراکیت کو''علمی اشتراکیت'' کے نام سے موسوم کیاہے اور باقی تمام اشتراکیتوں کو ذہنی خیالات کا درجہ دیاہے صرف اس لئے کہ ان کی بنیاد کسی علمی قانون پر نہ تھی اور وہ جلد ہی تباہی کے گھاٹ اتر گئیں۔
مارکسی تنظیم کے دو مرحلے ہیں۔جنہیں وہ تدریجی حیثیت سے رائج کرنا چاہتی ہے پہلے مرحلے کانام ہے اشتراکیت اور دوسرے کا نام ہے اشتمالیت، تاریخ مادیت کے لحاظ سے اشتمالیت تاریخ کا وہ آخری درجہ ہے جہاں پہنچ کر قافلۂ بشریت ٹھہر جائے گا اور تاریخ اپنا آخری فیصلہ سنادے گی،معجزہ ظاہر ہوجائے گا اور عالم کو اطمینان کی سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔
اشتراکیت درحقیقت اسی مستقبل کی ایک تمہید ہے جس کا مقصد سرمایہ داری کا خاتمہ کرکے اشتمالیت کے لئے راستہ ہموار کرناہے۔
اشتراکیت واشتمالیت کیاہیں؟
مارکسیت نے تاریخ کے ہر مرحلہ کے لئے کچھ قواعد وقوانین وضع کئے ہیں جن پر تاریخ کو سیرکرنا ہے۔اشتراکیت کے لئے چار اصول ہیں:
(1) طبقات کو ختم کرکے ایک غیر طبقاتی معاشرہ کی ایجاد۔
(2) مزدور طبقہ کی طرف سے اشتراکیت کے استحکام کے لئے ایک ڈکٹیٹر شپ کا قیام۔
(3) ثروت اور ذرائع پیداوار پر اشتراکی قبضہ۔
(4) بقدر طاقت عمل اور بقدر عمل اجرت کی بنیاد پر ثروت کی تقسیم۔
اس کے بعد تاریخ جب ترقی کرے گی اور اشتمالیت کی منزل میں قدم رکھے گی تو ان اصولوں میں کسی قدر تغیر ہوجائے گا۔
دوسرے میں اتنا تغیر ہوگاکہ ڈکٹیٹر شپ کا تصور بھی ختم ہوجائے گا اور لوگ حکومتی قید وبند سے بالکل آزاد ہوجائیں گے۔
تیسرے قانون میں فقط سرمایہ دارانہ وسائل پر قبضہ نہ ہوگا بلکہ شخصی پیداوار بھی مجموعی حیثیت پیداکرے گی اور انفرادی ملکیت کا مکمل خاتمہ ہوجائے گا۔
چوتھے قانون میں تقسیم کا معیار عمل کے بجائے ضرورت کو قرار دیاجائے گا اور ہر شخص کو بقدرحاجت مال ملاکرے گا۔
یادرکھئے کہ کسی نظام پر تنقید کرنے کے لئے تین قسم کے طریقے استعمال ہوتے ہیں:
(1) ان اصولوں پر تنقید کی جائے جن پر اس نظام کی بنیاد ہے۔
(2) یہ دیکھاجائے کہ آیا یہ اصول اس نظام پر منطبق بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔
(3) اس بات پر غور کیاجائے کہ آیایہ نظام معاشرہ پر انطباق کے قابل بھی ہے یا نہیں؟
ہم بھی انہیں طریقوں کو پیش نظررکھ کر مارکسیت کے ان مذاہب وتنظیمات پرتبصرہ کریں گے۔
مارکسی مذہب پر عمومی تنقید
مارکسی مذاہب کے سلسلہ میں سب سے پہلااور خطرناک سوال یہ اٹھتاہے کہ ان مذاہب کی دلیل کیاہے۔جس کی بناپرسارے عالم کو ان کی پابندی کی دعوت دی جارہی ہے۔
ظاہرہے کہ مارکس اپنی اس مساوات کو اخلاقی قدروں کا نتیجہ قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہے۔اس لئے کہ اخلاقیات اس کی نظرمیں ادہام کا نتیجہ ہیں۔درحقیقت چند اقتصادی ضروریات ہیں جن کو اخلاقیات کا نام دیاجاتاہے یادیاجانا چاہئے۔اس کے علاوہ اخلاق کا کوئی اور مفہوم نہیں ہے۔
اس نقطۂ خیال کے ماتحت وہ اپنے مذاہب پر تاریخی مادیت سے استدلال کرتی ہے۔ اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ مادیت فطری طور پر سرمایہ داری کو ختم کرکے اشتراکیت کی بنیاد ڈال دینا چاہتی ہے۔
اس مقام پر ایک جدید سوال یہ ابھرتاہے کہ مادیت اشتراکیت کو کس طرح چاہتی ہے اس کا جواب دیاجاچکاہے جس کا خلاصہ یہ تھاکہ تاریخ اپنے مخصوص عوامل ومحرکات کے تحت چلتی ہے جو اس کا مستقبل معین کرتے ہیں اور چونکہ سرمایہ داری کے دور تک پہنچ کر اس میں زائد قیمت کا دخل ہوجاتاہے۔اس لئے اسے ایک دن طبقاتی نزاع سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور اس کے نتیجہ میں مزدوروں کی فتح ہوگی جس کا دوسرا نام اشتراکیت ہوگا۔
ہم اپنی سابق گفتگو میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ مادیت ایک بے بنیاد نظریہ ہے اور تاریخ اس کے قوانین کا اتباع کرنے پر راضی نہیں ہے۔
ہم نے یہ بھی بتادیاہے کہ سرمایہ داری کے تناقضات میں زائد قیمت وغیرہ کا نام لینا غلط ہے۔ان سب کی ایک قانونی بنیاد ہے جو ان کے ماسواہے۔لہٰذا ان اسباب کی بنا پر
سرمایہ داری کا خاتمہ غیر معقول ہے اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو یہ سوال بہرحال باقی رہے گا کہ اشتراکیت کی خلافت کی دلیل کیاہے؟
کیایہ ممکن نہیں ہے کہ سرمایہ داری کے خاتمہ کے بعد حکومتی اشتراکیت قائم ہوجائے یاایسی تنظیم آجائے جس میں مختلف قسم کی ملکیتیں ہوں یا ایسا نظام حکومت کرے جس میں مظلوموں کے اموال واپس دلادیئے جائیں۔
اور اگر یہ تمام امکانات پائے جاتے ہیں تو اشتراکیت کے حتمی ہونے کا خواب کیونکر شرمندۂ تعبیر ہوگا اور مارکسی استدلال کس طرح درجہ تکمیل کو پہنچے گا؟یہ مسئلہ جواب طلب ہے۔
اشتراکیت
اس اجمالی تجزیہ کے بعد ہم اشتراکیت کے قوانین کا ایک تفصیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں، آپ کویاد ہوگاکہ اس کا پہلا قانون ہے طبقات کا خاتمہ اور غیر طبقاتی معاشرہ کی ایجاد ۔
اس کا یہ سبب بیان کیاگیاہے کہ تاریخ کے تمام ادوار جد لیاتی مادیت کے تحت چل رہے ہیں۔ہردور کاایک تقاضہ ہوتاہے جس کے مطابق نظام برسرکارآتاہے۔اب چونکہ سابق کے نظاموں میں انفرادی ملکیت کا ایک مقام تھا اس لئے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھاکہ ایک شخص سرمایہ دار ہو اور دوسرا مزدور،ایک امیرہواور دوسرا فقیر، اور اس طرح طبقات کی بنیاد پڑجائے گی۔
اشتراکی معاشرہ چونکہ ان خرافات کو قبول نہیں کرتااور انفرادی ملکیت کی کسی
حیثیت کا قائل نہیں ہے۔اس لئے اس میں طبقات کا وجود غیر ممکن ہی ہونا چاہئے۔
ہم نے تاریخ مادیت کا جائزہ لیتے وقت ہی اس بات کا اظہار کردیاتھا کہ مارکسیت تمام طبقات کو اقتصاد میں منحصر کردینے میں سخت غلطی پر ہے۔معاشرہ میں اس کے اور بھی عوامل واسباب ہوسکتے ہیں جیساکہ ہوابھی ہے کہ کبھی طبقات دین کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں اور کبھی سیاست کی بنیاد پر۔
اور جب یہ امکانات پائے جاتے ہیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اشتراکی معاشرہ میں یہ اسباب پیدانہ ہوں گے اور ان کے زیر اثر طبقاتی نظام وجود میں میں نہ آئے گا؟بلکہ میں تویہاں تک کہہ سکتاہوں کہ اس نظام میں بحسب عمل دولت کی تقسیم خود بھی ایک طبقاتی معاشرہ کی ایجاد کا سبب ہے۔اس لئے کہ لوگ اعمال کے اعتبار سے مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔
لہٰذا ان کے منافع مختلف ہوں گے اور اس طرح طبقات پیداہوجائیں گے بلکہ اشتراکیت میں توسیاسی بنیاد پر بھی طبقات پیداہوسکتے ہیں اس لئے کہ یہاں ایک جماعت انقلابی پارٹی کی قیادت کرتی ہے۔جسے بست وکشاد کے تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ لینن نے1905ء میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اصل انقلاب کی خود بھی ایک جماعت ہوتی ہے جس طرح سابق میں کاشتکاروں کے انقلاب کی لیڈری ایک جماعت اقتصادی امتیازکی بناپر کررہی تھی۔اسی طرح اس مزدور جماعت کی لیڈی فکری اور انقلابی شعور کی بناپر ہوگی۔
ظاہرہے کہ جب معاشرہ میں ایک ایسی خود مختار جماعت پیدا ہوجائے گی جو سرمایہ داری سے تصیفۂ حساب کے لئے ہر قسم کا تصرف کر سکتی ہو جیسا کہ لینن نے کہا تھا ''خانہ جنگی سے محفوظ زمانہ میں اشتراکیت اس وقت تک اپنا فریضہ ادا نہیں کرسکتی جب تک کہ اس پر ایک آہنی نظام نہ مسلط کیاجائے جو فوجی نظام کے مانند ہو اور اس کی صلا حیتیں پوری
پوری وسعت رکھتی ہوں ۔عوامی اعتماد بھی درجۂ کمال پر ہو۔''
اسٹالین نے اس بیان پر اتنا اضافہ اور کر دیا کہ''پرسکون دور میں ڈکٹیٹر شپ کے قیام کے لئے اس قسم کی تنظیم ہونی چاہئے بلکہ یہی تنظیم ڈکٹیٹر شپ کے قیام کے بعد بھی مناسب بلکہ ضروری ہے۔ ''
ان بیانات سے معلوم ہوتاہے کہ اشتراکیت اپنے انقلابی مفہوم کی بناپر ہمیشہ ایک ایسی جماعت کی ضرورت محسوس کرتی ہے جو بست وکشاد کے تمام اختیارا ت رکھتی ہو تاکہ وہ اپنے جابرانہ طرز حکومت سے لوگوں کے''اشتراکی مزاج''بنائے، نئے انسان ڈھالے اور ان کی فطرت میں اشتراکیت بھر دے۔
ظاہر ہے کہ تاریخ نے آج تک ایسے مطلق العنان اور آزاد طبقہ کی نشاندہی نہیں کی جس کے اختیارات اتنے زیادہ وسیع ہوں تو کیا طبقات کا اس سے بہترکوئی مفہوم ہو سکتاہے؟
اشتراکی اور غیر اشتراکی طبقیت میں اتنا فرق ضرورہوتاہے کہ غیر اشتراکی معاشروں میں طبقات اقتصادکا نتیجہ تھے۔جس شخص کے پاس سرمایہ زیادہ تھا وہ حکومت کا حق رکھتاتھا اور اشتراکی معاشرہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔
یہاں صاحبان فکر وانقلاب حکومت کریں گے اور پھر اس کے نتیجہ میں سرمایہ پیدا کریں گے۔
ظاہر ہے کہ جب اس منتظم جماعت کے امتیازات حکومت، کارخانے اور دیگر فردعات حیات تک پھیلے ہوئے ہیں اور پوری جماعت کو ایسے اختیارات حاصل نہیں ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگاکہ مزدوروں کی اجرت اور حکام کی تنخواہ میں تناقض شروع ہوجائے اور اس کے نتیجہ میں پارٹی کی طہارت کا عمل سامنے آجائے۔جیسا کہ مارکسیت میں اکثر ہوا ہے اور ہوتارہتاہے۔
اس کا واضح سبب یہ ہے کہ یہ ممتاز طبقہ اپنی فکری صلاحیتوں کی بناپر ضرورت سے
زیادہ تصرف کرنے لگتاہے۔اس کے ہاتھ باہر تک پہنچ جاتے ہیں اور نتیجہ میں ان کے مقابلہ میں پارٹی کے افراد کھڑے ہوجاتے ہیں۔یہ دیکھ کر کہ انہیں یہ امتیازات حاصل نہیں ہیں یا انہیں پارٹی سے الگ کر دیا گیاہے۔ اور پھر اس طبقہ کو خیانت سے متہم کرتے ہیں اور کبھی ان کا مقابلہ وہ افراد کرتے ہیں جو پارٹی سے خارج ہیں لیکن حاکم جماعت اپنے اختیارات کی بناپر ان سے بھی استفادہ کرنا چاہتی ہے۔
نتیجہ یہ ہوتاہے کہ پارٹی کو پاکیزہ بنانا ضروری ہوجاتاہے اور یہ کام انتہائی دشوار گذار ہوتاہے اس لئے کہ حاکم پارٹی پہلے ہی سے اپنا رنگ جماچکی ہوتی ہے اب اس کی علیحدگی آسان نہیں ہوتی۔
اس کا مشاہدہ اس طرح سے ہوسکتاہے کہ ایک ایک مرتبہ کی تطہیر میںپورا پورا نظام بدل کررہ جاتاہے وہ حادثہ جو طبقاتی نظام میں بھی پیش نہیں آتا چنانچہ 1936ء میں سودیت دیس کے 11 وزیروں میں سے 9کر نکال دیا گیا۔ قانون ساز جماعت کے سات افراد میں سے 5 کو الگ کیاگیا۔ مرکزی خفیہ جماعت کے 53 رئیسوں یں سے 43 نکالے گئے۔ جنگی ریاست کے 80افراد میں سے 70 الگ کئے گئے، پانچ مارشل افراد میں سے تین کو ہٹادیا گیا۔ 60 فیصد جنرل الگ کئے گئے، لینن لے سیاسی مکتب کے تمام ممبران علاوہ اسٹالین کے سب علیحدہ کر دیئے گئے، بیس لاکھ پارٹی ممبروں کو نکالاگیا۔یہاں تک کہ 1939ء میں پارٹی کے ممبران 15لاکھ اور خارج شدہ بیس لاکھ تھے۔
یہ تمام حالات وہ تھے جو ڈکٹیٹر شپ کی تشکیل میں پیش آئے۔ہمارا مقصد ان کے بیان سے اشتراکیت کی توہین نہیں ہے اس لئے کہ یہ بات اس کتاب کے موضوع سے باہر ہے بلکہ ہمارا مقصد صرف ان نتائج کو واضح کرناہے۔جو اس قسم کی سیاسی طبقیت کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔
اشتراکیت کا دوسرا رکن ہے ڈکٹیٹر حکومت، مارکسیت کا خیال ہے کہ اس کی
ضرورت صرف وقتی ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعہ سرمایہ داری کے جملہ اثرات ختم کردیئے جائیں اور فضاصاف ہوجائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ ایک فریب کی حیثیت رکھتاہے اس جماعت کی ضرورت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک انسان میں عام انسانی جزیات پائے جائیں گے۔ا س لئے کہ جب بھی مناسب تقسیم دولت کا سوال پیدا ہوگا ایک نہایت ہی جابراور بااختیار حکومت کی ضرورت ہوگی جو تمام حالات پر قبضہ کرکے ان میں مناسب طریقہ سے بحسب عمل تقسیم کرے اور ظاہرہے کہ یہ سوال استمراری حیثیت رکھتاہے۔لہٰذا اس حکومت کی ضرورت بھی دوامی حیثیت کی ہوگی۔
اشتراکیت کا تیسرارکن ہے تامیم املاک۔اس قانون کا علمی پہلو یہ ہے کہ جب سرمایہ داری کے مظالم اور ا س کے تناقضات حد سے بڑھ جائیں گے تو تاریخ ایک ایسا رخ اختیار کرے گی جہاں تمام املاک پوری قوم سے متعلق ہوں اور کسی شخص کو اس قسم کی پس اندازی کا موقع نہ ملے۔
عملی اعتبار سے اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کو ختم کرکے تمام مملکت کے حاصلات کو عام کردیاجائے اور ہر شخص کو اس کا مالک تصور کیا جائے البتہ تنہا نہیں بلکہ امت کا ایک جزء ہونے کی حیثیت سے۔
جہاں تک علمی پہلو کا تعلق ہے ہم پہلے ظاہر کرچکے ہیں کہ مارکس کی قائم کردہ بنیاد بے اصل ہے لہٰذا اس پر جو عمارت بھی کھڑی کیجائے گی وہ منہدم ہوجائے گی۔
عملی پہلو کے متعلق یہ عرض کرناہے کہ یہ قانون مارکسیت کے اشتراکی مرحلہ پر منطبق ہوتا نظرنہیں آتا اس لئے کہ جب تک سیاسی میدان میں حاکم پارٹی کا وجود باقی رہے گا اور اس کے اختیارات غیر محدود رہیں گے۔
اس وقت تک عملی اعتبار سے اس بات کی کوئی ضمانت نہیں لی جاسکتی کہ وہ پارٹی اپنے اختیارات سے فائدہ نہیں اٹھائے گی اور تمام پیداوار کو قاعدہ سے تقسیم کردے گی جبکہ
امتیاز کے مواقع اس پارٹی کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے بھی زیادہ حاصل ہیں۔
اگر ہم مارکس کی اصطلاحوں میں گفتگو کرنے کے عادی ہوتے تویہ کہتے کہ اس نظام میں حقیقی ملکیت اس حاکم جماعت کی ہے اور لفظی یاقانونی ملکیت تمام افراد معاشرہ کی اور یہ بات خود ہی ایک تضاد وتناقض کا سرچشمہ ہے اس لئے کہ ملکیت تصر ف میں آزادی چاہتی ہے اور یہ بات صرف حکام کو حاصل ہے۔عوام اس سے بالکل محروم ہیں۔
حکام کی مالکیت اور عام مالکوں کی ملکیت میں اتنا فرق ضرور رکھاگیاہے کہ عام افراد اپنے کو مالک کہہ سکتے ہیں لیکن حکام کو یہ اختیار نہیں ہے۔ان کا فریضہ ہے کہ اپنی ملکیت کو حقوق وامتیازات سے تعبیر کریں۔
میر اخیال ہے کہ تایخ میں ایسے شرمیلے مالک کم پیداہوئے ہوں گے جو اپنے کو مالک بھی نہ کہہ سکیں۔
یادرکھنا چاہئے کہ ملکیت کی عمومیت کا قانون اشتراکیت کے دور کا جدید حادثہ نہیں ہے بلکہ تاریخ میں اس سے پہلے بھی اس کا تجربہ ہو چکاہے۔چنانچہ بعض بیلنیٹ ممالک اور قدیم مصر نے بھی اپنے یہاں اس قانون کو رائج کیاتھا۔پیداوار کی نگرانی اپنے ذمہ لی تھی اور اس کے نتیجہ میں بے شمار فائدے حاصل کئے تھے لیکن چونکہ اس نظام پر فرعونیت غالب تھی اس لئے وہ اپنے راز کو پوشیدہ نہ رکھ سکی اور آخر کار یہ بھی ظاہر ہوگیاکہ حکومت کے زیر اثر اجتماعی ملکیت دراصل حکومت ہی کی ملکیت کا دوسر نام ہے اور یہ بھی واضح ہوگیا۔کہ ایسے نظام میں خیانیت بے حد ہوتی ہے۔چنانچہ حکومتی اقتدار واستبداد نے اسے اس منزل پر پہنچا دیاکہ بادشاہ نے خدائی کا لباس اختیار کرلیا اور پھر ساری دولت اس خدائی پر صرف ہونے لگی،کبھی عبادت گا ہوں پر توکبھی قصوروقبور پر۔
آپ اسے اتفاق نہ سمجھیں کہ ان دونوں معاشروں میں پیداوار کی رفتار تیز ہوگئی اور مملکت کو کافی منافع حاصل ہوگئے۔اس لئے کہ یہ ہر اس معاشرہ میں ہوگا جہاں کام لینے
والا مطلق العنان ہو اور کام کرنے والا مجبور محض، اخلاقیات نام کو نہ ہوں اور روحانی اقدار بے معنی ہوں۔
مادیت پوی زندگی کا مقصد ہواور اقتصادیات سارے اقتدار کا ہدف۔
اب چونکہ دونوں معاشروں میں یہی اسباب جمع ہوگئے تھے اس لئے پیداوار کی رفتار کا تیز ہوجانا ضروری اور لازمی تھا۔
یہ بھی کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ ہم نے دونوں تجربوں میں حاکم جماعت پر خیانت کا الزام سنا ہے۔جیساکہ اسٹالین نے خود بھی اعتراف کیاتھا کہ''آخری جنگ کے دوران حاکم جماعت کو اتنا موقع مل گیاکہ اس نے اپنے لئے بے پناہ اموال جمع کر لئے۔''
بظاہر مملکت میں یہ بات اس قدر عام ہوچکی تھی کہ اسٹالین نے برسراعلان کہہ دینے میں کوئی عیب نہیں محسوس کیا۔
ان بیانات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ دونوں تجربے اگرچہ حالات اور زمانہ کے اعتبار سے بالکل مختلف تھے لیکن اس کے باوجود آثار ونتائج کے اعتبار سے بالکل یک رنگ اورمتحد تھے۔جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقہ کی عمومیت اگرچہ پیداوار کے حق میں مفید ہوتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان نتائج میں بھی مبتلا ہوجاتی ہے جس میں فرعونیت اور اشتراکیت دونوں کومبتلا ہونا پڑا۔
اشتراکیت کا چوتھا رکن ہے تقسیم ثروت بحسب عمل اس کی توجیہ تاریخی مادیت کی بناپر یوں کی جاتی ہے کہ جب سرمایہ داری کے خاتمہ کے ساتھ مالک ومزدور کے امتیازات ختم ہوجائیں گے اور معاشرہ یک رنگ ہوجائے گا تو اس وقت ملکیت کی کوئی بنیاد سوائے عمل کے باقی نہ رہے گی۔اس لئے کہ عمل ہی قیمت کی بنیاد ہوتاہے۔اب جو شخص زندگی چاہے گا وہ عمل کرے گا اور جو شخص جس قدر زیادہ عمل کرے گا یعنی قیمت پیداکرے گا اسی قدر اس کا استحقاق بھی ہوگا۔اس لئے کہ معاشرہ میں ''زائد قیمت''کا سرقہ نہیں ہوتا۔
ایک حقیقت یہ ہے کہ قانون خود ہی ایک طبقیت کی بنیاد ہے اس لئے کہ تمام انسانوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ان میں خود واضح حد تک اختلاف ہوتاہے۔ایک شخص تواناہے وہ آٹھ دس گھنٹے کام کرے گا۔ایک ناتواں اور لاغر ہے وہ چھ گھنٹے سے زیادہ کام نہ کرسکے گا۔
ایک میں فطری صلاحیتیں ہیں وہ کام میں ندرت پیداکرے گا ایک تقلیدی حیثیت رکھتاہے۔اس کے کاموں میں بھی تقلیدی انداز ہوگا۔ایک ماہر فن ہے وہ برق وکہرہاء کے کام کر سکتاہے۔ایک سادہ لوح ہے وہ فقط حمالی کرے گا۔
ظاہرہے کہ اعمال کے اس اختلاف سے قیمتوں میں اختلاف ہوگا اور قیمت کے اختلاف سے ملکیتوں میں تفاوت ہوگا اور اس طرح ایک طبقاتی معاشرہ وجود میں آجائے گا۔
مارکسیت کو اپنے اس انجام کا احساس تھا اس لئے اس نے عمل کو بسیط ومرکب کی شکلوں میں تقسیم کر دیا تھا لیکن ظاہرہے کہ اس کے باوجود اس کے پاس دو ہی قسم کے حل ہیں:
(1) اپنی بنائی ہوئی تنظیم پر عمل درآمد کرے اور اس طرح ایک نئے طبقاتی معاشرہ کی ایجاد کردے جس کے خاتمہ کے لئے برسوں سے جنگ وجدل قائم رہی ہے۔
(2) اپنے قانون سے دستبردار ہوکر اچھے مزدوروں کی اجرت کا ایک حصہ قطع کرے تاکہ تقسیم مساوی حیثیت سے ہواور طبقات وجود میں نہ آسکیں اور اس طرح سرمایہ داران سرقہ کا شکار ہو۔
مارکسیت نے اس مقام پر نظریہ اور اس کے انطباق میں شدید اختلاف سے کام لیا ہے انطباق یعنی اشتراکی معاشرہ کی موجودہ حالت سے معلوم ہوتاہے کہ وہاں اعمال کی اجرتوں میں اختلاف ہے اور ظاہرہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور ایک حمال کو ایک فوجی، سیاسی، عالم وماہر فن کے برارکر دیاجاتاتو کوئی شخص بھی دشوار گذار اور مشکل علمی مشاغل کو اختیار نہ کرتا سب معمولی معمولی کاموں کی طرف متوجہ ہوتے اور برابر کی اجرت لیتے اور اس طرح
معاشرہ چند ہی دنوں میں تباہی کے گھاٹ اترجاتا۔
یہی وجہ تھی کہ اجرتوں میں تفادت رکھاگیا اور اس طرح کی نگرانی کے لئے ایک زبردست خفیہ پولیس کا محکمہ قائم کیاگیاتاکہ وہ ان اعمال اور اجرتوں کی نگرانی کرے مگر افسوس کہ ان تمام باتوں کے باوجود جب پردۂ ظلمت چاک ہواتو سوائے طبقاتی نظام کے اور کچھ نظرنہ آیا۔
نظریہ کے اعتبار سے مارکسیت نے جو حل پیش کیاہے وہ انگلز کے لفظوں میں (صند دو ہرنگ )سے سماعت فرمایئے۔
سوال یہ ہے کہ مرکب اعمال کی زیادہ اجرت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے؟
اس کا حل یہ ہے کہ آزاد(سرمایہ دار)معاشرہ میں اس عمل کی مہارت کی ذمہ داری خود افراد پر ہوتی ہے۔اس لئے کہ اس کا معاوضہ انہیں ملنا چاہئے۔اور اشتراکی معاشرہ میں یہ ذمہ داری حکومت کے سرہوتی ہے۔لہٰذا اس مہارت کے صلے میں جو اجرت ملنے والی ہوگی اس کا استحقاق حکومت کو ہوگا افراد کو نہیں؟ (صنددوہر نگ،ج2،ص92)
انگلز نے اپنے اس بیان میں یہ فرض کیا ہے کہ مرکب اعمال کی خصوصیات کو اس ٹریننگ کے مقابلہ میں قرار دیاجائے گا جس کے نتیجہ میں یہ صلاحیت پیداہوئی۔اب چونکہ سرمایہ دار معاشرہ میں ٹریننگ افراد کے ذمہ ہے اس لئے استحقاق ان کا ہوگا اور اشتراکی معاشرہ میں یہ کام حکومت اپنے ذمہ لے گی لہٰذا اس زیادتی کا استحقاق بھی اسی کا ہوگا۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بیان حقیقت سے پوری پور ی مخالفت رکھتاہے۔دنیا جانتی ہے کہ سرمایہ دار معاشرہ میں ماہر انسان اس مقدار سے کہیں زیادہ کمالیتاہے جو اس نے اس مہارت کے حاصل کرنے میں صرف کی ہے۔
علاوہ اس کے انگلز نے یہ بیان دیتے وقت مارکسی اصولوں کا بھی بغورمطالعہ نہیں
کیا ورنہ وہ یہ دیکھتاکہ مارکسیت میں ماہر فن انسان کی اجرت میں اس لئے اضافہ نہیں ہوگا کہ اس نے مہارت حاصل کی ہے بلکہ وہاں موجودہ عمل کے ساتھ اس مقدار عمل کا اضافہ کر دیا جاتاہے جو اس نے اس زمانہ مہارت میں صرف کیاہے۔
اس بنیاد پر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دس سال ٹریننگ حاصل کی اور اس کی اس تربیت پر ایک ہزار دینار خرچ کئے توظاہر ہے کہ یہ ایک ہزار اس تربیت کی قیمت ہیں لیکن اس عمل کی قیمت سے کہیں کم ہیں جو اس نے ٹریننگ کے زمانہ میں کیاہے جس طرح کہ قوت پیداکرنے کی زحمت نتیجہ میں ظاہرہونے والے عمل سے کہیں زیادہ کم ہوتی ہے۔
ایسی صورت میں اگرمزدور پر صرف ہونے والا عمل مقدار کے اعتبار سے اس عمل سے کم ہوجائے جو اس نے زمانہ تربیت میں کیاہے تواس باقی اجرت کا حقدار کون ہوگا۔ظاہر ہے کہ حکومت کو اس کا حق نہیں ہے۔اس لئے کہ اس نے اگر ایک ہزار صرف کئے ہیں تو اس سے زیادہ کام لے لیاہے۔اب اگر اس اجرت کو بھی لے لے تو یہ وہی حرکت ہوگی جو سرمایہ دار لوگ کیاکرتے تھے۔اور اگر دے دے تو طبقات کی بنیاد قائم ہوجائے گی۔
ایک دوسری بات جو انگلزکے ذہن سے نکل گئی تھی یہ ہے کہ عمارت کی شائستگی اور خوبی ہمیشہ تربیت ہی سے نہیں پیداہوتی ہے۔بلکہ کبھی کبھی اس میں انسان کی صلاحیت بھی دخل اندازہوتی ہے۔با صلاحیت انسان ایک ساعت میں اتنی ہی قیمت ایجاد کردیتاہے۔
جتنی قیمت بے صلاحیت مزدور دو ساعت میں ایجاد کرتاہے۔اب ایسی صورت میں مارکسیت اس زیادتی کو دے گی یا نہیں۔اگر دے دے گی تو طبقیت اور اگرنہ دے تو ظلم۔ دونوں صورتیں اچھے معاشرہ کے مطلوب کے خلا ف ہیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ مارکسیت کے سامنے دوہی راستے ہیں جن میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا ناگزیر ہے:
(1) اپنے نظریہ کو منطبق کرکے ہر شخص کو بقدر عمل اجرت دے اور اس طرح ایک جدید
طبقاتی معاشرہ کی بنیاد ڈال دے۔
(2) اپنے نظریہ سے دست بردار ہوکر بسیط ومرکب،عادی اور دقیق اعمال کو مساوات کی نظر سے دیکھے اور اس طرح ماہر فن مزدور کے عمل سے ایک حصہ سرقہ کرلے جیسا کہ سرمایہ داری کے دور میں ہواکرتاتھا اور جس سے پناہ حاصل کرنے کے لئے اشتراکیت کا انقلاب برپاکیاگیاتھا۔
اشتمالیت
اشتراکیت کے بعد سلسلۂ بحث اس آخری مرحلہ تک پہنچ جاتاہے جسے مادیت تاریخ کی زبان میں دنیوی جنت سے تعبیر کیاجاسکتاہے۔جہاں پہنچ کر قافلۂ تاریخ ایک منزل پرتوقف کرے گا اور انسان اشتمالیت کی حسین اورمطمئن زندگی بسر کرے گا۔اس اشتمالیت کے دواہم رکن ہیں:
(1) انفرادی ملکیت کا انکار
(2) حکومت کا خاتمہ
(1) انفرادی ملکیت کے بارے میں اس کا خیال یہ ہے کہ اس معاشرہ میں اس کا نام بھی نہ لیاجائے گا۔تمام املاک خواہ وہ سرمایہ دارانہ ہوں یا شخصی، سب کو عوام کی ملکیت قرار دیاجائے گا۔اور پھر ایک معین ضابطہ کے ساتھ تقسیم کیاجائے گا۔
(2) خاتمۂ حکومت کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اشتراکی دور کی مختصر حکومت کابھی خاتمہ کردیاجائے گا اور لوگوں کے ذہن سے حکومت کا تصور ہی مٹادیاجائے گا۔
یادرہے کہ اشتراکیت میں انفرادی ملکیت کا انکار''زائد قیمت''کے قانون پر مبنی
تھا لیکن اس مقام پر اس انکار کا کوئی علمی مدرک نہیں ہے بلکہ اسے اس فرض پر تسلیم کیاگیاہے کہ اشتراکیت کے دور میں پیداوار ثروت اور اموال کی اس قدر فراوانی ہوجائے گی کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق مال مل جائے گا۔تقسیم میں عمل کے بجائے حاجت ہی کو معیار قرار دیاجائے گا۔ظاہرہے کہ بقدر ضرورت مال مل جانے کے بعد انسان انفرادی ملکیت کانام بھی نہیں لے گا۔
انصاف تویہ ہے کہ ہم نے آج تک اس سے بہتر نہ کوئی خواب دیکھاہے اور نہ سناہے اس لئے کہ اس بیان کے مطابق تومارکسیت دہرے دہرے معجزے کرے گی۔
اول تو انفرادی ملکیت کے چھن جانے سے دکھے ہوئے دلوں میں پیداوار کی امنگ پیداکرے گی اوروہ پوری دلچسپی سے کام کریں گے۔
پھر عالم طبیعت میں اتنی وسعت پیداکرے گی کہ ہر شیء ہوااور پانی کے مانند بقدر کفایت پیداہوتاکہ اموال کی تقسیم بقدر ضرورت ہو۔نہ کوئی مزاحمت ہواور نہ کسی کوشوق ملکیت۔
ہم نے اپنی بدقسمتی سے آج تک یہ معجزہ نہیں دیکھاااور نہ مارکسیت کے پرستاروں ہی نے دیکھاہے۔اسی لئے ان کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑاکہ فی الحال اشتمالیت کا قیام غیر ممکن ہے خودلینن نے پہلے تو اشتمالیت قائم کرنے کے لئے زمینداروں سے زمینیں لے لیں،کاشتکاروں سے ان کے آلات چھین لئے۔ لیکن جب سب نے عمل سے انکار کر دیا اور ملک میں قحط شروع ہوا تو پھر انہیں حق ملکیت دے دیا اور ملکت کو پہلی حالت کی طرف پلٹا دیا۔یہاں تک کہ 3837ء تک دوسرا انقلاب کیاگیاتاکہ اس ملکیت کو ناجائز قرار دیاجائے لیکن کاشتکاروں نے بھوک ہڑتال کر دی اور کشت وخون پر آمادہ ہوگئے۔ قیدخانے چھلکنے لگے، قربانیاں ایک لاکھ تک پہنچ گئیں اور 32 ء تک بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 40 لاکھ تک پہنچ گئی اور حکومت نے اپنا طرز عمل بدل دیا، کاشتکاروں کو تھوڑی سی زمین
اور کچھ حیونات دے دیئے تاکہ انہیں کلخوذپارٹی کا ممبر بنایا جائے اور حکومت اس کی نگرانی کرتی رہے۔
خاتمۂ حکومت کے بارے میں مارکسیت کا کہناہے کہ حکومت طبقاتی نظام کا نتیجہ ہوتی ہے۔لہٰذا جب یہ طبقات ختم ہوجائیں گے اور اشتراکی نظام بروئے کارآجائے گا تو پھر حکومت کا سوال ہی نہ رہے گا۔
ہمارا سوال یہ ہے کہ اشتراکی قید وبند سے اشتمالی آزادی کیسے پیداہوگی؟کوئی نیا انقلاب برپاہوگایا خود بخود حکومت کا تصور مضمحل ہوجائے گا؟اگرانقلاب ہوگا تو انقلابی کون ہوگا؟یہاں تو انقلاب حکومت کی مخالف جماعت کیاکرتی ہے توکیا مزدوروں کے علاوہ کوئی جماعت پھر پیداہوگی۔اور گرتدریجاً خود بخود ختم ہوگی تو یہ جدلیت کے خلاف ہے اس لئے کہ وہاں کیفیت اور نوعیت کا انقلاب دفعتاً ہوتاہے۔تدریج کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔
پھر یہ کہ حکومت روز بروز ترقی کرتی ہے۔یہ اشتراکیت کیسے کمزور ہوجائے گی۔
ہر اشتراکیت میں ایک مطلق العنان حکومت ہوتی ہے اور اس سے بعید ہے کہ مستقبل کے لئے اپنی منزل سے انکار کردے اور عام افراد کے مثل ہوجائے اور اگر ایسا ہوبھی جائے تو کیا بقدر ضرورت تقسیم میںضرورت کی تعین کے لئے یادو ضرورتوں کی مزاحمت میں ترجیح دینے کے لئے یا صحیح تقسیم کی نگرانی کے لئے کسی حاکم طبقہ کی ضرورت نہ ہوگی؟
سرمایہ داری کے ساتھ
(1)سرمایہ دار تنظیم کے بنیادی نکات
(2)سرمایہ دار تنظیم کا علمی قوانین سے ارتباط
(3)سرمایہ دار تنظیم علمی قوانین میں بھی دخیل ہے
(4)سرمایہ دار تنظیم کے افکار واقدار پر نقد ونظر
سرمایہ دار تنظیم کے بنیادی نکات
تمہید
ابتدائے کتاب میں اس امر کی طرف اشارہ کیاجاچکاہے کہ اقتصادکے دو شعبے ہیں۔علم ومذہب،علم سے مراد ان قوانین طبیعت کومعلوم کرناہے جو بلاکسی شخص کی دخالت کے اپنا کام انجام دے رہے ہیں اور مذہب سے مراد وہ تنظیم ہے جس کے انطباق سے معاشرہ کی اصلاح اور سدھار کا دعویٰ کیاجاتاہے۔سرمایہ داری میں بھی یہی دونوں شعبے پائے جاتے ہیں لیکن اکثراہل فکروقلم حضرات نے اس نکتہ سے غفلت کرکے یہ خیال کرلیا ہے کہ علم ومذہب دونوں ایک چیزہیں اور اسی لئے ان لوگوں نے ایک کے مطالب کو دوسرے میں داخل کرکے اصل مفہوم کو بعیداز قیاس بنادیاہے حالانکہ ایسا ہونا نہ چاہئے تھا۔
اس مقام پر سرمایہ داری اور اشتراکیت میں ایک فرق پایاجاتاہے اور وہ یہ کہ اشتراکیت کے جملہ تنظیمات اس کے علم الاقتصاد یعنی تاریخی مادیت سے ماخوذ ہیں۔وہ اپنے نظام کو حرکت تاریخ کا حتمی نتیجہ قرار دیتی ہے لیکن سرمایہ داری میں ایسا نہیں ہے۔اس کی تنظیم علم سے اس قدر متحد نہیں ہے اوریہی وجہ ہے کہ اس مقام کی ہماری گفتگو گذشتہ گفتگو سے مختلف ہوگی ہم پہلے سرمایہ داری کے بنیادی نکات پیش کریںگے۔اس کے بعد علم الاقتصاد سے ان کا ارتباط و تعلق دیکھیں گے اور آخر میں علمی قوانین کی روشنی میں ان تنظیمات کا جائزہ لیں گے۔
ارکان سرمایہ داری
ان نظام میں تین ایسے اصول پائے جاتے ہیں جن کی بناپر یہ جملہ نظام ہائے زندگی سے ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھتاہے:
(1)آزادیٔ ملکیت:
اس نظام کاقانون یہ ہے کہ ہرفرد کو ملکیت میں مطلق العنان ہوناچاہئے۔اس پر کسی قسم کی پابندی نہ ہونی چاہئے۔حکومت کا فرض صرف یہ ہے کہ اس کی اس آزادی کی حمایت کرے۔ہاں اگر کسی وقت اجتماعی مصالح کی بنا پر کسی ملکیت کو عام کرنے کی ضرورت پڑجائے تو اسے مملکت پر صرف کیاجاسکتاہے۔
درحقیقت یہ نظام،اشتراکیت سے پوراپورا تضاد رکھتاہے۔وہاں اصلی حیثیت اجتما ع کو حاصل تھی۔افراد کو املاک،استثنائی حالت میں دی جاتی تھیں اور یہاں اصل حیثیت افراد کو حاصل ہے۔اجتماع پر ان کے اموال کو صرف بعض ضروری حالات میں صرف کیاجاسکتاہے۔
(2)آزادیٔ تصرف:
ہر شخص کو اس بات کا ختیار ہوگاکہ اپنے اموال میں اضافہ کرنے کے لئے پیداوار کے مختلف ذرائع استعمال کرے۔اپنی زمین میں چاہے تو خود زراعت کرے چاہے اسے کرایہ پردے دے یا بیکا رپڑارہنے دے۔حکومت کو دخل اندازی کا اختیارنہ ہوگا۔
اس قانون کا منشا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مصالح کو بہترجانتاہے اور اس کے لئے بہتر سعی کرسکتاہے۔لہٰذا اگر نظام اقتصادی کو اسی محور پر چلادیاجائے تو قہری طور پر پیداوار میں اضافہ ہوگا اور معاشرہ کی حالت سدھر جائے گی۔
(3)آزادیٔ صرف:
ہر شخص کو اپنے اموال کو صرف کرنے کا اختیار ہونا چاہئے جس طرح جس راہ میں چاہے صرف کرسکتاہے۔ہاں اگر کسی اجتماعی مصلحت کی بناپر حکومت رد کردے تو پھر اسے رک جانا پڑے گا اس لئے کہ اجتماعی مصلحت ایک اہم درجہ رکھتی ہے جیسے منشیات کا کاروبار۔
سرمایہ داری کے ان اصول وقوانین کا خلاصہ تین الفاظ ہیں:
(1)آزادیٔ ملکیت
(2)آزادیٔ تصرف
(3)آزادیٔ صرف
سرمایہ داراوراشتراکیت کا تناقض تویہیںسے واضح ہوجاتاہے کہ دونوں کا مرکز نظربالکل بدلاہواہے۔اشتراکیت میں بنیادی ملکیت معاشرہ کی ہے۔افراد کو اموال صرف استثنائی حالت میں دیئے جاتے ہیں۔اور سرمایہ داری اس کے بالکل برعکس ہے یہاں ملکیت کا براہ راست تعلق افراد سے ہے۔جماعت کے اختیارات صرف استثنائی حالت کے لئے ہیں۔
لیکن بعض اہل نظرنے ایک دوسرا فرق بھی قائم کیاہے جو اسی بنیادی فرق سے پیداہوا ہے اور وہ یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام کی نظرفرد پر ہوتی ہے۔وہ اس کی مصلحت کا خواہاں ہوتاہے اور اسی کو اپنے نظام اقتصاد کا محور قراردیتاہے۔
اشتراکی نظام میں افراد پر نظرنہیں ہوتی ہے بلکہ پورے اجتماع کو ایک نظر سے
دیکھا جاتاہے انہیں کے نفع ونقصان کو معیار قرار دیاجاتاہے۔یعنی سرمایہ دارانہ نظام افرادی ہے اور اشتراکی نظام اجتماعی۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انکشاف بالکل ہی غلط ہے اور اس کامنشا ایک بڑا حسین فریب ہے جو اشتراکیت کی طرف سے استعمال ہوتاہے اور عام اہل نظراسے نہیں سمجھ سکتے ورنہ در اصل دونوں نظام افرادی ہیں اور دونوں ہی میں افراد کو محورومرکز قرار دیاگیاہے۔
فرق یہ ہے کہ سرمایہ داری کی نظرنیک بحث اور ثروت مند افراد پر ہوتی ہے۔ وہ انہیں کی خیر خواہی کرتی ہے اور انہیں کے مصالح کو معیار قرار دیتی ہے۔اور اشتراکیت کا مطمح نظروہ پسماندہ طبقہ ہوتاہے جو ثروت مندوں کے مظالم سے پامال ہوتارہتاہے وہ اس طبقہ کے افراد کو سرمایہ داروں کے خلاف ابھارکر ان میں یہ شعور پیداکرتی ہے کہ یہ تمہاری ''زائد قیمت''کے چور ہیں۔
ان کے مظالم پر سکوت تمہاری حمیت وغیرت کے خلاف ہے اور یہ کوشش اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ انقلاب کے تمام جراثیم مہیا نہ ہوجائیں اور معاشرہ میں انقلاب نہ آجائے۔
ظاہرہے کہ اس تحلیل کی بناپر دونوں کا مرکز نظروہی فرد ہے چاہے وہ ترقی یافتہ ہویا پسماندہ ۔
اجتماعی مذہب تو وہ ہوگا جس کی نظراس طرح سے افراد پر نہ ہوبلکہ انہیں اپنی مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس دلائے تاکہ وہ از خود اپنے املاک کو اجتماعی مصالح پر قربان کریں نہ اس تصور کے ساتھ کہ انہوں نے دیگر افراد کا مال چرایاہے۔اور اب اسے واپس کر رہے ہیں بلکہ اس احساس کے ساتھ کہ وہ اپنے انسانی اور اخلاقی فریضہ کو اداکررہے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔
سوال صرف یہ رہ جاتاہے کہ وہ اجتماعی مذہب کون ساہے؟یہی وہ مقصد ہے جس
کی تحقیق کے لئے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے۔
(1)سرمایہ دار تنظیم کا عملی قوانین سے ارتباط
تاریخ اقتصادیات کی صبح اول جب اس علم کا سنگ بنیاد رکھا جارہاتھا تو علماء اقتصاد کے ذہن میں دو فکریں گونج رہی تھیں:
(1) اقتصادی زندگی چند طبیعی قوتوں کا نتیجہ ہے جو معاشرہ کے جملہ شعبوں پر اسی طرح حکومت کرتی ہیں جس طرح دوسرے طبیعی قوانین ۔علم الاقتصاد کا فریضہ ہے کہ ان قوتوں کے قوانین اور ان کے تقاضے معلوم کرے تاکہ انہیں کی روشنی میں تاریخ اقتصاد کا تجزیہ کیاجائے۔
(2) یہی طبیعی قوانین اگر اپنی آزادی پر باقی رہیں اور کھلی فضا میں کام کریں تو انسان پوری پوری رفاہیت سے زندگی بسر کر سکتاہے۔بشرطیکہ آزادی کا تعلق ملکیت، تصرف اور صرف تمام شعبوں سے ہو۔
پہلی فکر پر علم الاقتصاد کی بنیاد رکھی گئی تھی اور دوسری پر اقتصادی مذہب و تنظیم کی۔
بظاہر اس وقت کے مفکرین نے یہ طے کرلیاتھاکہ یہ دونوں فکریں باہم متحدہیں اور یہی وجہ ہے کہ آزادی پر ہر قسم کی پابندی کو عالم طبیعت سے مقابلہ خیال کرتے تھے اور اسے ایک ناقابل تلافی جرم قرار دیتے تھے۔ان کی نظرمیں اس پابندی کے پس منظر میں پورے سماج کی تباہی مضمر تھی۔
حالانکہ آج کے دور میں یہ فکر بالکل مضحکہ خیز ہے ۔آج طبیعی قوانین کی مخالفت
جرم نہیں ہوتی بلکہ ان قوانین کے باطل ہونے کی دلیل ہوتی ہے ورنہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ کوئی شخص عالم طبیعت کے قوانین وقواعد کی مخالفت کرسکے۔جب کہ وہ تمام انسانوں کی دسترس سے بالاتر ہیں ۔اور اپنے مخصوص شرائط وحالات کے ساتھ اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں۔
انسان کے امکان میں فقط اتنی سی بات ہے کہ ان حالات میں تغیر پیداکردے اور پھر ان قوانین کے دیگر آثارسے فائدہ اٹھائے جیساکہ فزکس میں ہواکرتاہے۔
لہٰذا ان قوانین پر اس انداز سے نظرنہ ہوئے گی کہ یہ عالم طبیعت کے قوانین کے حتمی نتائج ہیں بلکہ ان کو مستقل حیثیت دے کر دیکھاجائیگاکہ یہ انسان کی سعادت ونیک بختی کے اسباب کہاں تک مہیاکرسکتے ہیں جیساکہ آخری دور کے نقادوں نے کیاہے۔
یہیں سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ اشتراکیت اور سرمایہ داری پر تبصرہ کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔
اشتراکی نظام تاریخی مادیت کا حتمی نتیجہ ہے اس لئے وہاں مرکز بحث ونظر اس مادیت کو قرار دیاجائے گا اور سرمایہ دار نظام اخلاقی اور عملی افکار کی بنیادوں پرقائم ہواہے اس لئے یہاں ان افکار واقدار سے بحث کیجائے گی۔
ہم بحیثیت ایک مسلم نقاد کے جب اشتراکیت کے سامنے آتے ہیں تو ان بنیادوں پر بھی نظرکرتے ہیں جن کا لازمی نتیجہ اشتراکیت کو قرار دیاگیاہے اور اسی لئے ہم نے پہلے مادیت کا تجربہ کرکے اسے باطل کیاہے اور پھر اس کے بعد نظام پر قلم اٹھایاہے۔
لیکن جب ہمارا سامنا سرمایہ داری سے ہوتاہے تو ہم اس کے علمی قواعد کو نہیں دیکھتے اس لئے کہ یہ ہمارے موضوع سے خارج ایک شیء ہے ہم ان عملی اور اخلاقی اقدار پر نظرکرتے ہیں جن پر اس نظام کی بنیاد ہے۔
یہی وجہ ہے کہ یہاں ہم نے علمی بنیادوں پر تبصرہ ترک کر دیاہے اور اب براہ راست تنظیمی اصولوں پر تنقید شروع کر رہے ہیں۔یہ اور بات ہے کہ اثناء گفتگو اگر کوئی علمی مسئلہ
سامنے آگیاتو اس پر بھی بقدر ضرورت تبصرہ کریں گے۔
سرمایہ دارانہ نظام میں بھی علم الاقتصاد سے کسی حد تک بحث اس لئے ضروری ہے کہ ہم بغیر اس بحث کے سرمایہ داری کا صحیح نقشہ نہیں کھینچ سکتے اور نہ بتاسکتے ہیں کہ ایسے نظام کے رواج کا انجام کیاہونا چاہئے۔
دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگاکہ ان علمی قوانین کو معلوم کرکے انہیں ان تنظیمات پر بھی منطبق کریں گے جو مذہب نے پیش کئے ہیں۔اور ان کے ان قوانین سے ہم آہنگ ہونے کا دعویٰ کیاہے۔
یہیں سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جن علماء اقتصاد نے سرمایہ دار تنظیمات کو علمی قوانین پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ہر قانون کو علم الاقتصاد کے کسی قانون سے ہم رنگ کردیاجائے۔وہ انتہائی خطا کی منزل میں ہیں۔وہ اپنی اسی غلطی کی بناپر یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح''جنس کی زیادتی سے قیمت کی کمی'' ایک علمی ونظری قانون ہے اسی طرح ''آزادی کی فراوانی''بھی کوئی علمی قانون ہوگا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔اس کی بنیاد چند خود ساختہ اخلاقی اقدار پر ہے اس کو نظری اقتصاد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیاجاسکتاہے۔
(3)سرمایہ داری کے علمی قوانین کا تنظیمی رنگ
یہ تو پہلے ہی واضح کیاجاچکاہے کہ سرمایہ دار نظام نہ کسی علمی قانون کا حتمی نتیجہ ہے اور نہ اس کی پشت پر کوئی فکری اصول ہے۔اب ہم ایک اس سے زیادہ گہرے نکتہ کی طرف اشارہ کرناچاہتے ہیں اور وہ یہ کہ سرمایہ داری کی تنظیم اگرچہ علمی قوانین سے متاثر نہیں ہے
لیکن اس کے علمی قوانین مذہب سے ضرورمتاثر ہیں گویاکہ یہ قوانین بظاہر تو علمی ہیں لیکن واقعہ کے اعتبار سے ان کا رنگ تنظیمی اور مذہبی ہے۔لہٰذا یہ صرف اس معاشرہ پر منطبق ہو سکتے ہیں جو ان تنظیمات کا قائل اور ان کے افکار واقدار کا معترف ہو۔اب اگر کوئی معاشرہ ان کے افکار سے الگ اور ان تنظیمات سے بیگانہ ہوگا تو اس میں ان قوانین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔
وضاحت مطلب کے لئے یہ سمجھنا چاہئے کہ علم الاقتصاد کے قوانین دو قسم کے ہیں:
(1) وہ قوانین جن کا تعلق براہ راست عالم طبیعت سے ہے اور انسانی ارادہ کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے جیسے یہ قانون کہ''جو پیدا وار بھی زمین اور اس کے ابتدائی خام مواد پر موقوف ہوگی۔ وہ زمین ہی کی مقدار کے برابر ہوسکتی ہے۔''یا یہ قانون کہ''پیداوار کے اضافہ سے فائدہ میں اضافہ ہوتارہے گا یہاں تک کہ زمین کی صلاحیت جواب دے جائے تو اب مزید پیداوار کی کوشش کرنابے سود ہوگا اور غلہ بجائے زیادتی کے کمی کا رخ اختیار کرلے گا۔''
ظاہر ہے کہ ان فطری قوانین کو انسان کے ارادہ واختیار سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے افکار واقدار،سماج واخلاق کے بدل جانے سے ان میں تغیر ہوجائے بلکہ ان کا تمام تر تعلق عالم ارض سے ہے لہٰذا جب تک زمین رہے گی اس وقت تک پیداوار کا یہ قانون بھی یوں ہی رہے گا انسان کے افکار اچھے ہوں یا برے اس کا سماج سرمایہ دار ہویاغیر سرمایہ دار۔
(2) وہ قوانین جن میں انسانی ارادہ اختیارکودخل ہوتاہے اور وہ اپنے مخصوص انداز و معاشرہ کی بناپر ان میں تغیر پیداکردیتاہے۔جیسے یہ قانون کہ''جب غلہ بقدر ضرورت نہ ہوگا اور مانگ زیادہ ہوگی توقیمت بڑھ جائے گی۔''
ظاہرہے کہ اس قانون کو عالم طبیعت سے کوئی ربط نہیں ہے کہ غلہ کی کمی سے خود بخود قیمت بڑھ جائے بلکہ اس کا تعلق انسان کے ارادہ واختیار سے ہے اور یہ صرف اس
لئے ہوتاہے کہ انسان اپنے ذوق فطرت کی بناپر جنس کی کمی کو دیکھ کر زیادہ راغبت ہوتاہے۔
اور ظاہرہے کہ جب خریدار کی رغبت زیادہ ہوگی تو دکاندار کو قیمت بڑھادینے کا موقع بھی مل جائے گا۔
بعض علماء اقتصاد کا خیال ہے کہ دوسری قسم کے قوانین کو علم الاقتصاد کے قوانین میں شمار کرنا چاہئے۔اس لئے کہ عالم کے قوانین حتمی اور ان کے نتائج لازمی ہوتے ہیں۔وہ کسی کے ارادہ واختیار،رضا ورغبت کا انتظار نہیں کرتے اور ان قوانین میں یہی باتیں فرض کی گئی ہیں۔جس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ قوانین علمی نہیں ہیں۔بلکہ مذہبی اور تنظیمی ہیں۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ ان حضرات نے انسان واقتصاد کے ارتباط پر غور نہیں کیا۔ورنہ یہ بات واضح تھی کہ اقتصادیات انسانی زندگی کا ہی ایک شعبہ ہیں اس کے قوانین میں انسانی شعور کا لحاظ ضروری ہے ایسا نہیں ہوسکتاکہ اس کے اصولوں کو انسان کے نفسیات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔
اور جب یہ بات واضح ہے تو یہ کہاجاسکتاہے کہ علم الاقتصاد کا یہ قانون کہ''طلب کی زیادتی سے قیمت میں زیادتی ہوجاتی ہے۔''در حقیقت انسانی فطرت کی ترجمانی ہے۔ یہ ارادہ واختیاریا عالم طبیعت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے کہ ان دونوں میں تناؤ۔ اورٹکراؤ پیدا ہوجائے۔
اتنا ضرور ہے کہ قسم دوم کے قوانین ایک اعتبار سے قسم اول کے قوانین سے مختلف ہیں کہ پہلے قوانین حالات، سماج اور افکار کے بدلنے سے نہیں بدل سکتے۔اور دوسرے قسم کے قوانین ان میں سے ہر ایک کے بدل جانے سے بدل جائیں گے اور کبھی کبھی توایسا ہوگاکہ پورا عالم اقتصادہی منقلب ہوجاے گا۔
ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ایک مستقل اور مطلق قانون وضع کر دینا غیر ممکن
ہے لیکن تاہم ہمیں ہر قانون کواس کوحالات پر منطبق کرکے دیکھناپڑے گا کہ اس معاشرہ پر اس کا کیا اثر ظاہرہوتاہے۔
مثال کے طور پر اس بنیاد کو لے لیجئے جس پر اکثر اقتصادی قوانین کو مبنی کیاگیاہے یعنی انسان کا مادی اور اقتصادی ہونا۔ ظاہرہے کہ جب تک یہ فکر انسان کے ذہن میں رہے گی کہ وہ صرف مادی ہے۔اس کا مقصد حیات عیش وعشرت اور لذت اندوزی ہے۔ اس کے طریقے اور ہوں گے اور جب نظام اس میں یہ شعور پیداکردے گاکہ وہ مادی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے کچھ روحانی افکار اور اخلاقی اقدار بھی ہیں تو اس کا اقتصادی نظام بدل جائے گا اور اس کے طریقۂ زندگی میں نمایاں فرق پیداہوجائے گا۔
میرے خیال میں یہ بات اس وقت زیادہ واضح ہوجائے گی جب آپ سرمایہ دار سماج کو اسلامی معاشرہ سے ملاکر دیکھیں گے اور اس بات کو ملاحظہ کریں گے کہ افکار کے تغیر نے اقتصادی زندگی کو کس طرح متاثر کیاہے۔
ظاہرہے کہ اسلامی پرچم کے زیر سایہ پرورش پانے والے بھی گوشت وپوست ہی کے انسان تھے لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں وہ افکار جلوہ گر تھے جو ان کو تمام عالم سے ایک ممتاز حیثیت دے رہے تھے۔ان کا کردار ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اقتصادی قوانین کی حقیقت وغیر حقیقت کا فیصلہ کررہاتھا۔ وہ اپنے وجود سے بتارہے تھے کہ سرمایہ داری جیسے مزعومات حتمی نہیں ہیں بلکہ افکار واقدار کے بدل جانے سے بدل سکتے ہیں چنانچہ تاریخ نے اس مختصر مدت کی حالت بھی بیان کی ہے جس میں اسلامی قوانین کا تجربہ ہو رہاتھا۔اور انسان ایک روحانی مخلوق کی حیثیت سے روئے زمین پر اپنی زندگی گذاررہاتھا۔ اس میں ایک رسالتی اسپرٹ تھی جو اسے آفاق میں گم ہونے سے روک رہی تھی۔ اس کا عالم یہ تھاکہ: فقیروں کی ایک جماعت سرکار رسالت کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگی، یارسول اللہ سارا اجر تو مالداروں کو مل گیا۔وہ ہماری طرح نمازروزہ بھی کرتے تھے اور اسی
کے ساتھ صدقہ بھی دیتے ہیں۔
جو ہمارے امکان سے باہرہے ہم کیاکریں؟تو آپ نے فرمایاکہ تمہاری تسبیح وتکبیر اور تمہارا امرباالمعروف ونہی عن المنکر سب صدقہ ہے۔
ظاہرہے کہ اس جماعت کا مقصد دولت حاصل کرنا نہ تھا وہ اس اجر آخرت سے محرومی پر فریادی تھی جو امراء کو ان کے صدقات سے حاسل ہورہاتھا اور یہی وجہ تھی کہ جب ایک صدقہ کا سراغ مل گیا تو مطمئن ہوگئے۔
شاطبی نے اس دور کی تجارت اور اس کے اجارہ کی یوں تصویر کشی کی ہے کہ:
آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کم سے کم اجرت یافائدہ لیتے ہیں۔ایسا معلوم ہوتاہے کہ کاروبار سے ان کا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچاناہوتاہے۔یہ نصیحت میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں۔جیسے دوسروں کے وکیل ہوں۔یہ اپنے لئے زیادہ لینا دوسرے کے حق میں خیانت تصور کرتے ہیں۔
باہمی تعاون کے متعلق محمد بن زیاد کا بیان ہے:
اکثر ایسا ہوتاہے کہ کسی کے گھر مہمان آگیااور اس نے دوسرے کی پتیلی آگ پرسے اتارکر مہمان کردے دی اور مالک کو معلوم ہواتو وہ میزبان سے کہتاہے اللہ مبارک کرے۔
اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ کیاایسے معاشرہ کے قوانین کسی دوسرے سماج میں نافذ ہوسکتے ہیں؟اور کیا اس کے بعد اقتصادیات کے جملہ قوانین حتمی قرار دیئے جاسکتے ہیں؟ہرگزنہیں۔
اس قسم کا ایک دوسرا قانون بھی ہے جس کا تعلق عرض وطلب اور تقسیم منافع سے ہے جس کی شرح ریکارڈو نے اس طرح کی ہے کہ مزدور کو اجرت میں سے ایک حصہ ملنا چاہئے جس سے وہ اپنی طاقت عمل کو محفوظ رکھ سکے۔اس حصہ کی تحدید بھی بازار کی قیمت کے اعتبار سے ہونی چاہئے اور باقی منافع کو مختلف انداز سے تقسیم کرلینا چاہئے۔
اس قانون کا علمی پہلو یہ قرار دیاگیاہے کہ اگر اجرت زیادہ ہوگی تو مزدور اپنی رفاہیت کی بناپر نکاح ونسل کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس طرح اولاد کی زیادتی سے مزدوروں کی زیادتی ہوگی اور مزدوروں کی زیادتی سے قیمت کم ہوجائے گی اور جب قیمت کم ہوگی تو فقر وفاقہ بڑھے گا او رجب فقر وفاقہ کی فراوانی ہوگی تو مزدور کم ہوجائیں گے اور جب مزدر کم ہوجائیں گے تو اجرت پھرزیادہ ہوجائے گی۔
سرمایہ دار اہل اقتصاد نے خیال کیاہے کہ ان کایہ قانون کوئی حتمی پہلو رکھتاہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔یہ قانون اسی وقت کارگر ہوگاجب معاشرہ میں پسماندہ طبقہ کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اور قیمت کا معیار بازار کو قرار دیاجائے لیکن اگر کسی معاشرہ میں عمومی ذمہ داری کا قانون موجود ہوا (جیساکہ اسلام میں ہے)یابازار کاکوئی اعتبار نہ ہوجیسا کہ اشتراکیت میں ہے، تووہاں یہ قانون بالکل لغو ہوجائے گا۔
خلاصہ یہ ہے کہ سرمایہ دار علم اقتصاد نے جتنے قوانین بھی وضع کئے ہیں سب کا تعلق دوسری قسم سے ہے اور چونکہ اس قسم کے قوانین کا تعلق ارادہ، افکار ،مفاہیم،اقدار، معاشرہ اور نظریات وغیرہ سے ہوتاہے لہٰذا ان کا انطباق صرف ایک معاشرہ پر ہوسکتاہے کسی دوسرے معاشرہ کے لئے بالکل لغواور بے کار ہوں گے۔
(4)مذہبی سرمایہ داری کے افکار واقدار پر نقد ونظر
سرمایہ دار تنظیم سے یہ معلوم ہوتاہے کہ اس کاسنگ بنیاد انسان کی اقتصادی زندگی ہے۔اسی پر جملہ قوانین کی بنیاد ہے اور اسی رنگ میں علمی قوانین ڈھالے گئے ہیں۔ایسے
حالات میں ایک نقاد کا فریضہ ہے کہ اس آزادی کا تجزیہ کرے تاکہ اس بنیاد کی حقیقت معلوم ہوسکے جس پر پوری عمارت قائم ہے۔
اس سلسلہ میں سب سے پہلاسوال یہ ابھرتاہے کہ سماج میں اقتصادی آزادی کیوں ضروری ہے؟انسان کو یہ حق کہاں سے حاصل ہواہے؟
سرمایہ دار نظریات نے اس سوال کے جواب میں چند طریقے اختیار کئے ہیں اور اس کی بناپر آزادی کا احترام واجب قرار دیاہے:
(1) انسان کے انفرادی اور اجتماعی مصالح میں موافقت ہوتی ہے لہٰذا ہر اجتماع پسند نظام کے لئے ضروری ہے کہ وہ افراد کو مکمل آزادی دے تاکہ وہ اپنے ذاتی اغراض کے پیش نظر کام کریں اور آٹومیٹکل طریقہ سے اجتماعی مصالح وجود میں آئیں۔اور چونکہ انفرادی آزادی ہی تمام اجتماعی اور سماجی مصالح کا سرچشمہ ہے اس لئے اس کا پورا پورا تحفظ ضروری ہے۔
(2) آزادی کے عالم میں انسان پورے طور سے پیداوار پرزوردے سکتاہے اس لئے ہر شخص کو اس آزادی سے بہرہ ور ہونا چاہئے تاکہ اپنے ذاتی اغراض کی بناپر پیداوار سے پوری پوری دلچسپی لے اور اس طرح معاشرہ میں ثروت کااضافہ ہو۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ فکر پہلی فکر سے الگ کوئی شیء نہیں ہے بلکہ اسی کا ایک شعبہ ہے۔وہاںانفرادی مصالح کو تمام اجتماعی مصالح کا وسیلہ قرار دیاگیاتھا اور یہاں صرف پیداوار کی حد تک محدود کر دیاگیاہے۔
(3) آزادی انسان کا ایک فطری حق ہے جو اسے ملنا چاہئے۔چاہے اس سے مصالح عامہ روبراہ ہوں یا نہ ہوں۔پیداوار کی اصلاح ہو یا نہ ہو۔اس لئے کہ کسی شخص کو بھی اس کے فطری حق سے محروم کر دینا انسانیت ے خلاف ہے۔
ظاہر ہے کہ یہ انداز فکر سابق کے طریقوں سے مختلف ہے اس لئے کہ اب تک
آزادی کو واقعی اور خارجی حیثیت حاصل تھی اور اب یہ انسان کی داخلی طلب ہو گئی جس کا قبول کرنا انسانی فرض ہے۔
سرمایہ داری کے ان تمام افکار کا خلاصہ تین باتیں ہیں:
(1) حریت مصالح عامہ کا وسیلہ ہے۔
(2) آزادی پیداوار کے اضافہ کا باعث ہے۔
(3) آزادی انسان کا فطری حق ہے۔
ہمیں اس مقام پر انہیں تینوں کا حقیقی تجزیہ کرناہے۔
حریت مصالح عامہ کا وسیلہ ہے
اس دعویٰ کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسان کے ذاتی مصالح ہمیشہ اجتماعی مصالح سے ہمرنگ ہوتے ہیں لہٰذااگر انسان کو انفرادی آزادی دے دی جائے کہ وہ اپنے لئے ہی کوئی کام کرے تو اس کا فائدہ اجتماع کو بھی پہنچ جائے گا اور اس کے لئے نہ اخلاقیات کی ضرورت ہوگی اور نہ رسوم وتقالید کی۔اس لئے کہ انسان کسی قدر بھی بداخلاق کیوں نہ ہوجائے اپنی ذات کے لئے کام ضرور کرے گا یہ طے شدہ ہے کہ ذاتی فائدہ کا اثر بھی اجتماعی مصلحت پر پڑتاہے لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوگاکہ معاشرہ غیبی طریقہ سے اس کام سے استفادہ کرلے گا۔
شاید یہی وجہ ہے سرمایہ دار معاشرہ میں روحانیت اور اخلاقیات کا کوئی درجہ نہیں ہے ان کا تمام کام بغیر ان پابندیوں کے بھی چل جاتاہے۔تو ان پابندیوں کو اپنے سرلے لینا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔
میرامطلب یہ نہیں ہے کہ اس معاشرہ میں اخلاقی قدروں کا وجود نہیں ہے کہ کوئی شخص اس پر اعتراض کردے بلکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اس نظام کو ان اخلاقی اقدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا کام بغیر ان اقدار کے بھی چل سکتاہے۔
سرمایہ دار نظام کے ہواخواہوں نے اس کویوں بھی بیان کیاہے کہ آزادی کے دور میں ہر کارخانے والا اپنے خارکانے کو ترقی دینے کی کوشش کرے گا۔مقابلہ کا بازار گرم ہوگا۔
ہر شخص کو دوسرے کے آگے بڑھ جانے کا خطرہ ہوگا اور نتیجہ میں وہ عمدہ سے عمدہ آلات استعمال کرے گا۔اچھی سے اچھی ایجادیں کرے گا اور اس طرح صرف ذاتی اغراض کی بناپر انسانی ضرورت کی تمام چیزیں بہتر سے بہتر عالم وجود میں آسکیں گی۔
اس کے بعد اور کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ اخلاقی اور روحانی افکار کی بھی پابندی کی جائے۔نصیحت وموعظے بھی سنائے جائیں۔دعوت عمل بھی دی جائے؟جبکہ تمام کام بغیر ان زحمتوں کے بھی ہورہاہے اور بہتر سے بہتر ہورہاہے۔ان کے لئے سب سے بڑاموعظہ اور سب سے موثر نصیحت مقابل کا وجود ہے جس کے آگے بڑھ جانے کا خطرہ ہر آن لگاہواہے اور جس کے پس منظر میں اپنی موت بھی لکھی ہوئی ہے۔
سرمایہ داری اپنی فکر کو پیش کرکے چل بسی لیکن آج دنیا اس فکر پر خندہ بہ لب ہے کیا تاریخ کے وہ تمام صفحات محوکردیئے جائیں گے جن میں اس سرمایہ داری کے مظالم کی داستانیں ہیں۔
کیاوہ خوشگوار حالات نظروں سے غائب ہوجائیںگے جن میں انفرادی اور اجتماعی مصالح کا تضاد نمایاں طور پرنظر آرہاتھا۔
کیا اخلاق واقدار کے انکار کی یہ بدنظمی فراموش کر دینے کے قابل ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرہ کا اندازہ بڑی سہولت سے ہوسکتاہے جس نے تمام افکار واقدار کا انکار کردیاہو خواہ اقتصادی زندگی میں اس کا اندازہ کیاجائے یا اخلاقی انحطاط میں یادیگر معاشروں سے تعلقات میں۔
اور یہی وجہ تھی کہ سرمایہ پرست افراد نے بھی اس بدنظمی کا احساس کیا اور آزادی میں ترمیم شروع کی۔لیکن ظاہر ہے کہ بنیاد ی افکار سے خالی افکار کی ترمیم بھی ایک تاریخی خیال سے زیادہ حیثیت نہ رکھے گی۔
آپ ملاحظہ کریں تو معلوم ہوگاکہ اسی محدود آزادی کا نتیجہ تھا کہ ہر صاحب
صلاحیت انسان نے اسے اپنے ہاتھ میں ایک بہترین اسلحہ خیال کیا اور اس کے ذریعہ پست طبقہ کی گردن کاٹنا شروع کر دی۔اسے اپنے مصالح سے غرض تھی دوسروں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔فطری اعتبار سے صلاحیت بھی زیادہ پائی جاتی تھی۔
لہٰذا استفادہ کے مواقع بھی زیادہ تھے۔اب باقی افراد کا فرض ہے کہ اس کے زیردست رہیں اور اسی کے کرم کا سہارا لے کر زندگی گذاریں۔جس کا آخری انجام یہ ہواکہ خود انسان بھی ایک متاع بن گیا اور اس کی خریدوفروخت شروع ہوگئی۔جب انسانوں کی زیادتی ہوگئی تو ان کی قیمت گھٹ گئی۔اور اس حد تک کہ لوگ بھوک سے تباہ ہونے لگے۔ سٹرکوں پر ان کے جنازے نظرآنے لگے لیکن بنیادی فکر محفوظ رہی کہ مکمل آزادی ہونی چاہئے۔
چنانچہ ایک طبقہ آزادی سے استفادہ کرتارہااور دوسرا موت کے گھاٹ اترتارہا۔ ہر شخص اس امیدپر جیتارہاکہ اگر ہماری قوم کے چند افرادیوں ہی بھوک سے مرجائیں تو اچھا ہوتاکہ کام کرنے والوں کی تعداد کم ہو اور اس طرح اجرت میں کچھ اضافہ ہو سکے۔
ظاہر ہے کہ جب انفرادی اور اجتماعی مصالح کی مطابقت کا یہ رنگ اقتصادیات کے بارے میں ہے تو روحانیت واخلاقیات کے حق میں تونتیجہ اور بھی بدتر ہوگا۔یہاں نہ احسان کے جذبات ہوں گے اور نہ صلۂ رحم کے حوصلے۔ نفسی نفسی کی دنیا ہوگی اور انانیت کا بازار، باہمی امداد کی جگہ جنگ وجدل کو ملے گی اور اجتماعی کفالت کا درجہ اقتصادی گھوڑدوڑ کو۔
آپ یہ خیال نہ کریں کہ اخلاقی اقدار کا منکر ہمیشہ خود غرضی ہی سے کام لے گا۔ نہیں نہیں یہ بھی ہوسکتاکہ وہ کسی بناپر اپنے ذاتی مصالح کو قربان کردے۔یااس کے ذاتی مصالح کو اجتماع کی طرف کھینچ لائیں تو ایسے وقت میں اس کے کام اجتماعی بھی ہوں گے۔لیکن وہ انسان نفس پر ست ہوگا اخلاق پر ست نہ ہوگا۔اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فرق انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی وقت ضرورظاہر ہوگا۔جیسا کہ ہم آئندہ تفصیل کے ساتھ
بیان کریں گے۔
ہم سرمایہ داری کے ان آثار سے قطع نظربھی کرلیں جو ملک کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔توہمیں ایک نظر ان حالات پر ضرورکرنی ہوگی جو بیرونی ممالک میں پیش آتے ہیں تاکہ یہ بھی دیکھ لیاجائے کہ یہ انفرادی مصالح صرف اپنے معاشرہ کے اجتماعیات سے مطابقت کرتے ہیں یا ان میں دیگر معاشروں پر حادی ہونے کی قوت بھی ہے۔
اس مسئلہ کا سب سے بہتر حل خود سرمایہ داری کی تاریخ ہے۔جس میں انسانیت نے بڑی ہولناک منزلیں طے کی ہیں۔اور روحانیت واخلاقیات نے بڑے صبر آزما مواقع دیکھے ہیں۔جہاں آزادی تاریخ کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ ہے اور حریت انسانیت کی تباہی کا بہترین وسیلہ۔
آزادی ہی کا اثرتھاکہ یورپ کے ممالک نے دیوانہ وار ہمسایہ ممالک پر قبضہ جمانا شروع کردیاتھا۔اور ان کے ساکنین کو غلام بنارہے تھے۔ذراافریقہ کی تاریخ کے خونچکاں اوراق ملاحظہ کیجئے۔
شقادت وسنگدلی کا وہ طوفان جس میں برطانیہ،فرانس اور ہالینڈ جیسے ممالک ملک کے مختلف رہنے والوں کو غلام بنابناکربازاروں میں بچ رہے تھے۔عالم یہ تھاکہ دیہاتوں میں آگ لگادی جاتی تھی۔اور جب بیچارے گاؤں سے باہر نکل پڑتے تھے تو انہیں گرفتار کرکے کشتیوں کے ذریعہ اس پار لاکر بیچ دیاجاتاتھا۔
19دیں صدی تک یہ مظالم جاری رہے یہاں تک کہ برطانیہ نے ظاہری ہمدردی کی بناپر ایک شدید اقدام کیا۔اور ایسے معاہدات کی بنیاد ڈالی جس میں بردہ فروشی ممنوع ہولیکن ظاہرہے کہ یہ تمام باتیں صرف ظاہری تھیں جس کا نتیجہ یہ ہواکہ برطانیہ نے افریقہ کے ساحلوں پر اپناا سطول مقرر کردیاتاکہ وہ جائز تجارتوں کی کڑی نگرانی کرے۔
بظاہر اس اقدام سے افریقی اقوام کی حمایت کی گئی لیکن اندر ہی اندر استعماری
حرکت شروع ہوگئی کہ اور اب ان اقوام پر ان کے گھروں میں قبضہ ہونے لگا۔یورپ کے بازاروں کی ضرورت بھی نہ رہی اور کام بھی بننے لگا۔کیا ان حالات کے بعد بھی کوئی انصاف پسند انسان یہ کہہ سکتاہے کہ اخلاقیات سے عاری سرمایہ دار معاشرہ اپنے مصالح کی تحصیل کے لئے عمومی مصالح کی ایجاد میں حصہ لے گا؟
آزادی پیداوار کی زیادتی کا ذریعہ ہے
آپ کو یادہوگاکہ سرمایہ دار نظام میں مطلق آزادی کا دوسراجوازاس امر کو قرار دیا گیاتھا کہ آزاد معاشرہ میں کارخانوں کا مقابلہ ہوتاہے اور ہر شخص اپنی اجتماعی حالت کو خوشگوار بنانے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جنس ایجاد کرتاہے۔نتیجہ یہ ہوتاہے کہ یہی آزادی ملک کو جنس ومتاع کی فراوانی سے مالامال کر دیتی ہے۔
لیکن افسوس کہ سرمایہ داری نے اس مقام پر نہ سرمایہ دار آزادی کے مفہوم پر غور کیاہے اور نہ پیداوار کی قدروقیمت پر۔
آزادی کے مفہوم سے غفلت کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرہ میں تمام کارخانے برابر کے تونہیں ہوتے کہ سب مقابلہ میں شریک ہوجائیں اور اس طرح پیداوار پر اچھا اثر پڑے بلکہ کارخانے اپنی صلاحیت واستعداد کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔لہٰذا اس آزادی کا اثر یہ ہوگاکہ بڑے بڑے کارخانوں کے مالک چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کو ہڑپ کر جائیں اور معاشرہ تباہی کے آخری درجہ پر پہنچ جائے۔احتکار کی فراوانی ہواور مالک طبقہ کے لئے موت کی ارزانی۔
پیداوار کی قدروقیمت نہ سمجھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان مفکرین نے اپنی تمام فکروں کو پیدا وار کی زیادتی کی طرف مبذول کر دیاہے اور اس بات پر غور نہیں کیا کہ معاشرہ کی اصلاح اور اس کی رفاہیت کا تعلق صرف پیداوار کے اضافہ سے نہیں ہے بلکہ اس میں دوسرے عناصر بھی شریک ہیں۔اور ان میں سب سے اہم عنصر ہے پیداوار کی صحیح تقسیم اور یہی وہ منزل ہے جہاں سرمایہ داری کو اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا پڑتاہے۔
اس لئے اس کی نظر میں تقسیم ثروت کا معیار ہے قیمت، جس کے پاس جنس کی قیمت ہووہ خریدلے اور کھائے۔اور جس کے پاس قیمت نہ ہو، خواہ اس کے اسباب کچھ ہی کیوں نہ ہوں،اسے نہ کھانے کا حق ہے اور نہ جینے کا۔
ظاہر ہے کہ آزادی سے متاثر افراداتنی قیمت کے مالک نہ رہیں گے کہ اپنی زندگی سکون و اطمینان کے ساتھ گذارسکیں۔ان کی ساری دولت ناکام مقابلہ کی نذر ہوگئی ہوگی یا سرمایہ دار نے ان کے خدمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہوگا۔ایسے عالم میں پست طبقہ کا آخری انجام موت اور تباہی کے سوااور کیاہوسکتاہے؟
معلوم ہوتاہے کہ معاشرہ کی اقتصادی اصلاح کی ذمہ داری صرف پیداوار پر نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ثروت کی تقسیم پر ہے۔
اور یہی وہ نکتہ ہے جو سرمایہ داری کے بس سے باہر ہے اس لئے کہ اس نے مطلق آزادی کا قانون وضع کر دیاہے۔
حریت انسان کا فطری حق ہے
سرمایہ داری کا آخری حربہ جسے اس نے آزادی کی حماعت کے لئے استعمال کیاہے یہ ہے کہ آزادی انسان کا فطری حق ہے جو اسے ملنا چاہئے۔آزادی کے بغیر انسانیت ایک بے معنی لفظ ہے۔
ہم اس حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لئے پہلے حریت اور آزادی کا مفہوم سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ اسی کی روشنی میں اس بیان کی صحت کا اندازہ ہوسکے۔
یادرکھئے حریت کی دو قسمیں ہیں:طبیعی اور اجتماعی۔
طبیعی حریت عالم طبیعت کے دیئے ہوئے فطری اقتدار کی بناپر ہوتی ہے۔ اور اجتماعی حریت نظام زندگی کے ذمہ ہوتی ہے اس کے مہیا کرنے کی مسئولیت نظام اجتماعی کی گردن پر ہوتی ہے۔
ان دونوں قستموں کو الگ کر دینے سے ہمارامقصد یہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی ایک قسم کی خصوصیات کو دوسرے پر منطبق نہ کریں۔جیساکہ خود سرمایہ داری نے کیاہے۔
طبیعی حریت سے مراد حیات کا وہ اقتدار ہے جو ہر جاندار کو دیاگیاہے اور چونکہ انسان ان تمام انواع سے مافوق ہے لہٰذا اس کی حریت بھی زیادہ وسیع ہوگی۔ اس حریت کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان جانداروں کا مقابلہ بے جان اشیاء سے کریں تاکہ حیات کے اختیارات کی وضاحت ہوسکے۔پتھر ایک بے جان شیء ہے آپ جب تک نہ پھینکیں گے نہیں جائے گا۔جب پھینک دیں گے تو راستہ نہیں بدلے گا اگر سامنے کوئی مزاحم پیداہوگیاتوواپس نہیں آئے گا۔اس لئے کہ اس میں حیاتی قوت کا فقدان ہے اور وہی امور کا سرچشمہ ہوتی ہے لیکن اگر نبات کو دیکھیں تو وہ حیات کے پست ترین طبقہ میں ہونے
کے باوجود مزاحمت پیداہوجانے سے اپنا رخ بدل سکتاہے۔حیوان کا رتبہ اس سے زیادہ بلند ہے وہ اپنی طبیعت اور خواہش کی بناپر راہیں بھی نکال سکتاہے۔طریقہ بھی بدل سکتاہے، دفاع بھی کرسکتاہے لیکن اس میں بھی اتنا اختیار نہیں ہے کہ طبیعی خواہشات سے مقابلہ کرسکے۔ اس لئے کہ اس کی قوت حیات بھی کم ہے۔یہ مرتبہ تو قدرت نے صرف انسان کو عطاکیاہے کہ اسے آزادی کے آخری درجہ پر فائز کردیاہے۔وہ تمام تصرفات کے ساتھ طبیعی تقاضوں کو بھی بدل سکتاہے اور خواہشات کو ٹھکراکرایک نئی راہ نکال سکتاہے۔
طبیعی آزادی حیات کی پابندہے اسی کی وسعت سے وسیع اور اسی کی تنگی سے تنگ ہوجاتی ہے۔غیر جاندار اشیاء کاموقف اس کے مقابلہ میں سلبی ہے اور جاندار کا موقف ایجابی۔
یہی وہ حریت ہے جس کو جوہر انسانیت قرار دیاجاسکتاہے اور یہی وہ آزادی ہے جس کے بغیر انسانیت ایک بے معنی لفظ ہے۔
لیکن ظاہرہے کہ اس کے بارے میں کوئی اجتماعی بحث بیکار ہے اس لئے کہ یہ قدرت کا ایک عطیہ ہے جو بقدر صلاحیت عطاہوچکاہے۔اس کی تحدید غیبی انداز سے ہوچکی ہے اب اس پر مزید غور وفکر کی گنجائش نہیں ہے۔
سرمایہ داری کا طبیعی حریت کو محل بحث میں لانا اور پھر اجتماعی حریت کو انسانی جوہر کا ایک جزو قرار دینا اسی اشتباہ کا نتیجہ ہے کہ اس نے دونوں کے احکام کو مخلوط کردیاہے۔
اجتماعی حریت کا مفہوم سمجھنے کے لئے یہ سمجھنا ہوگاکہ اس آزادی کی بھی دوقسمیں ہیں واقعی اور صوری۔
واقعی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی نظام اپنے افراد کے لئے تمام صلاحیتیں مہیا کرے کہ وہ اس آزادی سے استفادہ کرسکیں۔کوئی شیء خرید نا چاہتے ہیں تو نظام زندگی اس کی قیمت کا انتظام کرے۔جنس کو بازار تک پہنچائے۔احتکار کی ممانعت کرے اور اس
طرح لوگوں کو واقعی معنی میں آزاد قرار دے ورنہ اگر قیمت پاس نہ ہویا جنس ہی موجود نہ ہو اور عوام کو مکمل اختیار بھی دے دیاجائے تو یہ واقعی آزادی نہ ہوگی بلکہ صرف ایک صوری اعلان ہوگا جس کا فی الحال کوئی مقصد نہ ہوگا۔
اس لئے کہ صوری حریت میں کسی قسم کے انتظام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اس شخص کوبھی دی جاسکتی ہے جس کے لئے عمل کرنا محال ہویا وہ کسی کام کے قابل نہ ہو۔اس آزادی کے اعتبار سے آپ ایک قلم کی خریداری میں اسی طرح آزاد ہیں جس طرح ایک کروڑ روپیہ کے کارخانے کی خریداری کے بارے میں۔اس لئے کہ حکومت کا فریضہ نہ اس کا انتظام کرناہے اور نہ اس کا۔یہ صرف انسان کی قسمت سے وابستہ ہے اگر تقدیر نے یاوری کی اور اسباب مہیا ہوگئے تو یہ واقعی آزاد ہوجائے گا اور خریدلے گا۔ورنہ صوری اور لفظی آزادی پر مسرت کا اظہار کرتارہے گا۔
اس مقام پر یہ بھی واضح رہے کہ صوری آزادی صرف لفظ نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی اس کا موقف ایجابی بھی ہوجایاکرتاہے اور یہ انسان کے حق میں مفید ہوجایاکرتی ہے اس لئے کہ اگر کوئی شخص تمام اسباب رکھتاہو اور قانونی حیثیت سے کارخانہ خریدنے میں آزاد نہ ہوتو اس کے لئے یہ تمام اسباب بیکار ہیں۔
اب ایسے حالات میں صوری آزادی دے دینا ایک پورے کارخانہ کی خریداری کا باعث ہوسکتاہے۔
مطلب یہ ہے کہ صوری آزادی قدرت کے مرادف نہیں ہے لیکن قدرت کے لئے ضروری ضرور ہے۔درحقیقت یہ انسانی صلاحیتوں کے امتحان کا ایک وسیلہ ہے جو شخص بھی اپنی صلاحیتوں کا امتحان کرنا چاہتاہے اور اپنی طاقتوں کو آزمانا چاہتاہے اسے چاہئے کہ اس آزادی کا سہارالے کر کھڑاہوجائے اور اسباب مہیاکرکے حقیقی آزادی حاصل کرلے۔
سرمایہ دار نظام نے جس آزادی کو اپنایاہے۔وہ صوری اور ظاہری آزادی ہے۔
حقیقی آزادی کے متعلق اس کا خیال یہ ہے کہ یہ آزادی کی کوئی قسم نہیں ہے۔بلکہ آزادی کا نتیجہ ہے۔نظام اجتماع کا فریضہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کی راہ میں حائل نہ ہو اور انہیں آزادی سے کام کرنے دے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کے لئے وسائل معیشت کا بھی انتظام کرے۔
واقعی آزادی کے غیرممکن یا غیر مناسب ہونے کے لئے سرمایہ داری کے پاس دو دلیلیں ہیں:
(1) کسی اجتماعی نظام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوسکتی کہ وہ ہر شخص کے تمام مطالبات کو پورا کردے اس لئے کہ اکثر افراد کے پاس تو اس بات کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مصالح کا تحفظ کرسکیں اور کسی نظام حیات کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بیوقوف کو عقل مند اور کندذہن کو ذہین بنادے۔اس کے علاوہ بہت سے مطالبات ایسے ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا غیر معقول ہے کہ ہر شخص کو ملک کا بادشاہ نہیں بنایا جاسکتا اور ہر شخص کو ریاست نہیں دی جاسکتی۔حالانکہ اس کی تڑپ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔نظام زندگی صرف اتنا ہی کرسکتا ہے کہ تمام افراد کے لئے اقتصادی میدان صاف کردے کہ وہ اپنی اپنی استعداد آزمائیں کامیاب ہوں یا وسط راہ ہی میں گرجائیں جو انجام بھی ہو اس کی ذمہ داری خود ان کے سرہوگی۔حکومت کسی بات کی مسئول نہ ہوگی۔
(2) ہرشخص کے لئے واقعی آزادی کے جملہ اسباب کا مہیا کردینا اور اس کی گردن سے مسئولیت کا بارااٹھالینا ایک ایسا کام ہے جس سے اس کی عملی سرگرمی ختم ہوجائے گی اور وہ دوسروں پر اعتماد کرتے کرتے خود اعتمادی کی دولت سے محروم ہوجائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگاکہ وہ اپنی قسمت آزمائی نہ کر سکے گا اور اس کی عملی طاقتیں شل ہوجائیں گی۔
اس میں شک نہیں ہے کہ ان دلائل میں کسی حد تک معقولیت ضرورپائی جاتی ہے
لیکن اس انداز سے سرمایہ دارانہ طریقہ پر واقعی آزادی کا ختم کرنا ایک غیر مناسب اقدام ہے۔جبکہ ایک ایسا حل بھی موجود ہے جس کی بناپر ان تمام خرابیوں کا علاج ہو سکتاہے۔
پوری پوری آزادی انسان کو نہیں دی جاسکتی ۔وہ اس طرح بے اعتماد ہوجائے گا لیکن یہ تو ممکن ہے کہ اسے بڑی حد تک آزاد کردیاجائے تاکہ اسے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی رہے اور وہ بڑے بڑے ترقی یافتہ معاشروں کے مقابلہ میں جدوجہد بھی کرتارہے۔
حقیقت امر یہ ہے کہ سرمایہ داری کا واقعی حریت کے بارے میں یہ سلبی موقف اس ایجابی موقف کا نتیجہ ہے جو اس نے صوری اور ظاہری حریت کے بارے میں اختیار کیاہے اس لئے کہ جب معاشرہ میں تمام اشخاص کو ظاہری آزادی دے دی جائے گی اور ان کے لئے کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوگی تو غیرترقی یافتہ افراد کے لئے آزادی اور معیشت کا مکمل سامان مہیا کرنا غیر ممکن ہوجائے گا۔
اس لئے کہ تمام افراد کے لئے سامان کا مہیا کرنا اس بات پر موقف ہے کہ سب سے پہلے بڑھتی ہوئی دولت پرپابندی لگائی جائی۔اور یہی وہ بات ہے جو ظاہری آزادی کے دور میں نہیں ہوسکتی۔
اب نظام حیات کے سامنے دوہی راستے رہ جاتے ہیں:
(1) تمام افراد کو مکمل طور سے آزاد کردیاجائے اور ان پرکسی قسم کی پابندی نہ لگائی جائے۔
ظاہر ہے کہ ان حالات میں غیردولت مند افراد کی ضمانت کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتاہے اس لئے کہ وہ ثروت مندوں کی پابندی پرہی ممکن ہے۔
(2) غریب طبقہ کی ضمانت لی جائے اور ان کے لئے سامان معیشت مہیا کیاجائے۔
ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ آزادی نہیں محفوظ رہ سکتی جو مطلق طور پر ثروت مندوں کو دی گئی ہے اور جس پرپورے نظام کی بنیاد ہے۔
سرمایہ داری کی طرف سے صوری آزادی کی یہ حمایت اس بات کی موجب ہوئی ہے
کہ اشتراکیت اس سے بالکل متضادموقف اختیارکرے۔چنانچہ اس نے ڈکٹیٹر نظام قائم کرکے اس بات کا ذمہ لیاہے کہ وہ واقعی آزادی کا انتظام کرے گی اور اب یہ دونوں نظام ایک طرفہ حساب رکھتے ہیں۔ایک ظاہری آزادی کا حامی ہے تو دوسرا واقعی حریت کا۔
دین اسلام نے ان دونوں سے الگ ایک راستہ اختیار کیاہے جس میں دونوں قسم کی آزادی کا بھی تحفظ کیاہے اور ان کے باہمی تضاد کو بھی دور کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔اس نے ایک طرف پورے معاشرے کو آزادی دی ہے تو دوسری طرف ضمانت کا ایک معیار مقررکرکے تمام افرادپر اس کی رعایت بھی ضروری قرار دی ہے۔
اس کی نظرمیں ثروت مندافراد اپنے معاملات میں آزاد ہیں لیکن اس لحاظ کے ساتھ کہ ان کی اس آزادی سے پسماندہ طبقات کی معیشت کو نقصان نہ پہنچے اور ان کی زندگی ضیق میں نہ پڑجائے۔
آزادی اور ضمانت کا یہی وہ حسین امتزاج ہے۔جس کی ضرورت آج بھی محسوس کی جارہی ہے۔اور لوگ اس مفہوم کو ایجاد کرنے کے لئے آزادیوں پر پابندیوں کے پہرے بٹھارہے ہیں۔
اس مقام پر ایک سوال ضرور ابھرتاہے کہ سرمایہ داری کی نظرمیں اس شکلی اور ظاہری آزادی کی بنیاد کیاہے اور اسے کن اقدار پر قائم کیا گیاہے؟ضمانت اور واقعی آزادی کو کیوں پس پشت ڈال دیاگیاہے؟
سرمایہ داری نے اجتماعی نظام کے اعتبارسے تووہی جوابات دیئے ہیں جو ہم ابھی نقل کرآئے ہیں۔اور ان پرایک مناسب تبصرہ بھی کرچکے ہیں البتہ ذاتی اور شخصی اعتبار سے جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ طبیعی آزادی انسان کا فطری حق ہے اور اس کا انکار گویا انسانی کرامت وشرافت کا انکا رہے۔
ظاہر ہے کہ اس دلیل سے وہ شخص مطمئن ہوسکتاہے جو لفظی بازی گری کا عادی
ہو۔ حقیقت پسند انسان اس قسم کی خطابت سے مطمئن نہیں ہوسکتا۔
اس لئے کہ اس پر یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کا فطری حق اس کی فطری اور طبیعی آزادی ہے نہ کہ اجتماعی اور سماجی آزادی۔
اکثر اس مقام پر یہ بھی کہہ دیاجاتاہے کہ جب طبیعی آزادی انسان کا فطری حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطری طور پر آزاد رہنا چاہتاہے لہٰذا اب اگر اسے اجتماعی قید و بند میں گرفتار کرلیاجائے گا تویہ فطرت سے مقابلہ ہوگا اور فطرت سے مقابلہ کسی نظام کے لئے بھی مناسب نہیں ہے۔
بظاہر یہ بات کسی حدتک صحیح معلوم ہوتی ہے اور یہ حق بھی ہے کہ اجتماعی نظام کو انسانی جذبات کا احترام کرنا چاہئے لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان کے نفس ناطقہ میں گوناگوں جذبات پائے جاتے ہیں اور یہ غیر ممکن ہے کہ ایک جذبہ کا احترام کیاجائے اور دوسرے کو ٹھکرا دیاجائے۔اجتماعی نظام کا جہاں یہ فرض ہے کہ جذبۂ حریت کا تحفظ کرے وہیں یہ بھی فرض ہے کہ جذبۂ سکون واطمینان کا لحاظ رکھے۔اور واضح سی بات ہے کہ اس جذبہ کا پوراپورا خیال اسی وقت ہو سکتاہے جب جذبۂ حریت کو پابند بنادیاجائے ورنہ بڑے طبقہ کی آزادی چھوٹے طبقہ کی دولت سکون کو تباہ وبرباد کردے گی۔
آخرکلام میں یہ بھی واضح کردینا ضروری ہے کہ ظاہری آزادی کے اختیار کرنے میں سرمایہ داری کا نظریہ صحیح ہویا غلط لیکن اپنی بنیادوں کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اس لئے کہ اس کے بنیادی نظریات کا لحاظ رکھتے ہوئے واقعی حریت کا اعتراف ممکن ہی نہیں ہے واقعی آزادی ایک پابندی کی طالب ہے اور پابندی کے تین ہی راستے ہیں:
(1) اس پابندی کوتاریخی ضرورت قرار دیاجائے اور یہ کہاجائے کہ تاریخ اس دور میں اسی قید وبندکی طالب ہے جیساکہ اشتراکیت نے اپنی ڈکٹیٹر حکومت کے لئے دعویٰ کیاہے۔ لیکن یہ دعویٰ سرمایہ دار نظام کے لئے غیر ممکن ہے اس لئے کہ وہ تاریخی
مادیت کے مارکسی مفہوم کی منکر ہے۔
(2) اس پابندی کو کسی بلند وبالا ذات کے اعتقاد کا نتیجہ قرار دیاجائے اور یہ کہاجائے کہ اس کائنات شعور کا کوئی خالق ہے جسے انسنان نظام حیات کے پورے پورے اختیارات حاصل ہیں اور انسان کا فریضہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے جیساکہ دینی تعلیم کا تقاضہ ہے۔
لیکن ظاہرہے کہ سرمایہ داری اس مسلک سے بھی مجبور ہے۔اس نے دین کو اپنے فلسفۂ مادیت سے پہلے ہی جداکردیاہے۔
(3) اس پابندی کو اس ضمیر کی آواز قرار دیاجائے جو انسان کو روحانی افکار اور اخلاقی اقدار پرمجبور کرتاہے اور اس کے لئے ایک عادل نظام کا مطالبہ کرتاہے لیکن ظاہرہے کہ سرمایہ داری اس راستہ پر بھی چلنے سے معذور ہے۔اس کے یہاں ضمیر کاکوئی مفہوم ہی نہیں ہے وہ وجدان کے تقاضوں کو عرف وعادت اور رسم ورواج کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔
ایسے حالات میں انسان خود ہی سوچ سکتاہے کہ واقعی آزادی کی کوئی راہ باقی نہیں رہ گئی ہے اور حکومت کا بھی صرف اتنا ہی فریضہ ہے کہ وہ عوام کی آزادی کا تحفظ کرے۔اسے ان کے معاملات میں اس وقت تک دخل دینے کا حق نہیں ہے جب تک کہ اجتماعی نظام پر کوئی افتاد نہ پڑجائے۔
اسلامی اقتصادیات کے ارکان
1۔اسلامی اقتصادیات کا مختصر خاکہ
2۔اسلامی اقتصاد ایک مجموعی نظام کا جزء ہے
3۔اسلامی اقتصاد کوئی علمی قانون نہیں ہے
4۔تقسیم، پیداوار سے الگ صور ت میں
5۔اقتصادی مشکلات کے اسلامی حل
1۔اسلامی اقتصادیات کا خاکہ
اسلامی اقتصادیات کے وہ بنیادی ارکان جن کی بناپر وہ تمام اقتصادی نظاموں سے ممتاز اور ممیز ہوتاہے حسب ذیل تین نکات ہیں:
(1) مرکب ملکیت
(2) محدود آزادی
(3) اجتماعی عدالت
ہمارے گفتگو کا تعلق فی الحال انہیں نکات کی تشریح وتوضیح سے ہے اور اس کے بعد ان کی تفصیلات پر تنقیدی نگاہ ڈالی جائے گی۔
تاکہ اسلامی اقتصادیات کا ایک مکمل نقشہ انسان کے ذہن میں آسکے اور وہ یہ اندازہ کرسکے کہ اسلام کا اقتصادی مزاج کیاہے۔
(1)مرکب ملکیت
اسلام اپنے نظریۂ ملکیت میں سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے جداگانہ موقف کا حامل ہے۔سرمایہ داری نظام کا خیال ہے کہ معاشرہ میں انفرادی ملکیت کو مرکزی نقطہ قرار دینا چاہئے اور کسی شیء کی اجتماعی ملکیت کا اس وقت تک اعتراف نہ کرنا چاہئے جب تک کہ حکومتی ضرورت اس امر پر مجبور نہ کردے۔
گویاکہ بنیادی نکتہ انفرادی ملکیت ہے ا ور استثنائی صورت اجتماعی ملکیت۔
اشتراکیت نے اس سے بالکل متضادموقف اختیارکیاہے۔اس کا خیال یہ ہے کہ اجتماعی ملکیت کو مرکزی حیثیت دی جائے اور انفرادی ملکیت کو صرف ان مواقع پر جائز قرار دیاجائے جب حکومتی حالات اس بات پر مجبور کر دیں۔
یعنی اجتماعی ملکیت اصل ہے اورا نفرادی ملکیت استثنائی۔
دین اسلام نے اپنے لئے ان دونوں سے الگ ایک راستہ نکالاہے۔اس کی نظرمیں مرکزیت نہ اسے حاصل ہونی چاہئے اور نہ اسے۔بلکہ ملکیت کی ایک ایسی شکل قرار دینی چاہئے جس میں تنوع اور ہمہ گیری ہوتاکہ جملہ قواعداپنے اپنے حالات سے مخصوص رہیں۔ اور کسی قسم کے استثنائی کی نوبت نہ آئے۔وہ انفرادی ملکیت کا بھی قائل ہے اور اجتماعی وحکومتی ملکیت کا بھی لیکن ان سب کے میدان اس طرح الگ الگ کر دیئے ہیں کہ ایک دوسرے پر اثرانداز نہیں ہوسکتا۔
اسلامی نظام کو سرمایہ دارانہ نظام قرار دینا۔
اسی طرح غلط ہے جس طرح اسے اشتراکی نظام سے تعبیر کرناہے۔
سرمایہ داری فقط انفرادی ملکیت کے اعتراف کا نام نہیں ہے اور نہ اشتراکیت ہی فقط اجتماعی ملکیت کا نام ہے بلکہ ان دونوں میںایک قیدیہ بھی ہے کہ اسی ملکیت کو اصل اور بنیادقرار دیاجائے اور دوسری قسم کو استثناء اور یہی وہ بات ہے جسے اسلامی اقتصاد کا مزاج برداشت نہیں کرسکتا۔
اسلامی نظام کو دونوں کا مجموعہ قراردینا بھی ایک فاش غلطی ہے جیساکہ بعض تحدید پسند مفکرین کا خیال ہے۔وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں سے ایک ایک جزء کو لے لیاہے اور اس طرح دونوں کی خوبیوں کا مجموعہ بن گیاہے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اسلامی نظام کے تجزیہ کے وقت انتہائی مہمل معلوم ہوگی اس لئے کہ وہ نہ سرمایہ داری کی انفرادیت کا قائل ہے اور نہ اشتراکیت کی اجتماعیت کا۔ اس کا اپنا ایک انداز نظرہے جس پر اس نے اپنی پوری عمارت قائم کی ہے۔اور اس کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ دونوں نظاموں نے ایک ایک قسم کو اپناکر اپنے کو ایسی مصیبت میں مبتلا کردیاہے جس کے بعد انہیں استثنائی حالات کا اعتراف کرناپڑرہاہے۔
سرمایہ داری میں اجتماعی ملکیت کی تحریک تو ایک عرصہ سے چل رہی تھی۔ اشتراکیت جو ابھی طفل نوزائیدہ کے مانند ہے۔اس میں بھی انفرادی ملکیت کے قوانین بننے لگے ہیں۔
چنانچہ سودیت دیس کے قانون کی دفعہ7میں یہ بات کہہ دی گئی ہے:''جو لوگ باہمی زراعت کرتے ہیں انہیں ہر خاندان کے حساب سے کچھ زمین،ایک رہائشی مکان، کچھ جانور اور کچھ زراعتی آلات دے دیئے جائیں۔''
اسی طرح دفعہ9میں یہ قانون بنادیاگیاہے کہ کاشتکاروں اور چھوٹے کاریگروں کو معمولی کارخانوں کی ملکیت کا حق دے دیاجائے اگرچہ اشتراکی ملکیت کاقانون محفوظ ہے۔
(2)محدود آزادی
اسلامی اقتصاد کا دوسرا اہم رکن یہ ہے کہ افراد کو اقتصادی آزادی دی جائے لیکن ان پر ایسی پابندیاں بھی عائد کی جائیں جو ان کے روحانیت اور اخلاقیات کا نتیجہ ہوں اور ان کو بالکل مطلق العنان نہ چھوڑاجائے۔
اس مقام پربھی اسلام نے دونوں نظاموں سے ہٹ کر ایک نیاراستہ نکالاہے۔ وہ نہ بالکل پابندی کا قائل ہے اور نہ مطلق آزادی کا،وہ ایک ایسی آزادی دینا چاہتاہے جس سے اس کے مسلم اقدار وافکار پر کوئی برااثر نہ پڑے بلکہ وہ اسی آزادی کے ذریعہ اپنے فریضہ کو ادا کرکے انسانیت کی صحیح رہنمائی کرسکے۔
اسلام نے اس تحدید اور پابندی کے دو طریقے اختیار کئے ہیں:
(1)داخلی تحدید: جس کے قیود نفس کی گہرائی سے پیداہوتے ہیں اور جس کی پابندی روحانیت اور اخلاقیات کی بنیادوں پر ہوتی ہے۔
(2)خارجی تحدید: جس کے قیدوبند کا ذمہ دار نظام زندگی ہوتاہے اور جو انسان پر اس کے خارجی حالات سے بار کی جاتی ہے۔
داخلی تحدید اس معاشرہ کا لازمی نتیجہ ہے جو اسلام کے زیر سایہ تربیت پارہاہو جس کی پرورش کی ساری ذمہ داری اسلام کے اصول وقوانین نے لے لی ہو اس لئے کہ اسلام کے روحانی افکار اپنے اندر ایک ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ اگر انہیں تاریخ میں تصرف کرنے کا موقع دے دیاجائے تووہ مہذب اور صالح انسان ڈھال سکتے ہیں۔وہ ایک ایسا انسان
بناسکتے ہیں جسے اپنے داخلی حالات وکیفیات کی بناپر ان حدود دقیود کا احساس بھی نہ ہو اور وہ اس حدبندی کو روحانی فرحت تصور کرکے صدق دل سے قبول کرلے۔
یہ تحدید اور پابندی نہیں ہے بلکہ انسان میں ایک ایسا صالح شعور پیداکرانے کا نام ہے جس کے تحت اس کے تمام افعال صالح اور شائستہ ہوں۔
آپ تاریخ پر نظرڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگاکہ اسلامی تجربہ اگرچہ بڑی قلیل مدت کے لئے صفحۂ تاریخ پر ظاہر ہواہے اور اس کو پورے طریقے سے کارکردگی کا موقعہ نہیں ملا لیکن اس نے اتنے ہی عرصہ میں ایسی ذہنیتیں ایجاد کر دیں جن سے خیروبرکت،عدل واحسان کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگے۔
اب اگر اس تجزیہ کی مدت کچھ زیادہ ہوجاتی اور اسلام کو مکمل تربیت کا موقع مل جاتاتو کیا وہ یہ ثابت نہ کر دیتاکہ انسان ہی زمین پر الٰہی خلافت کا حقدار ہے اور وہی اس کرہ خاکی کو عدل و رحمت سے معمور اور ظلم وجور سے خالی کراسکتاہے۔
اسلام کی اس مختصر ذہنی تربیت کا ایک نمایا اثریہ ہے کہ آج کے وہ مسلمان جو بظاہر اسلام کی حقیقی رہنمائی سے محروم ہوچکے ہیں۔خلافت الٰہیہ کے صحیح مفاہیم ان کی نظروں میں نہیں ہیں۔زمانی اعتبار سے صدراسلام ان سے بالکل الگ ہوچکاہے۔سماج کے اعتبار سے وہ دوسرے قوانین کے زیر سایہ جی رہے ہیں۔
لیکن ان تمام باتوں کے باوجود زکوٰة جیسے الٰہی حقوق پابندی سے ادا کرتے ہیں اور خیر وبرکت کے وہ راستے جن پر اسلام انہیں چلانا چاہتاتھا۔بغیر کسی خارجی پابندی کے چل رہے ہیں اور زبان حال سے اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگراسلام کو اس سے زیادہ موقع ملاہوتاتو سارا کرہ ارض خیر واحسان سے معمور ہوجاتا۔
خارجی تحدید یعنی وہ پابندی جو اسلام نے معاشرہ پر اپنے تشریعی اصول اور شرعی احکام کے ذریعہ عائد کی ہے اور اس طرح ہر اس کیف ونشاط کو ممنوع قرار دے دیاہے۔
جس سے اس کی اعلیٰ قدروں پر غلط اثر پڑتاہو۔اس پابندی کے نفاذ کے لئے بھی اس نے حسب ذیل طریقے اختیار کئے ہیں:
(1) اس اقتصادی طرب ونشاط کو حرام قرار دے دیاہے جس سے اسلامی قدریں متاثر ہورہی تھیں جیسے سود خوری،ذخیرہ اندوزی وغیرہ۔
(2) عام اجتماعی حالات پرولی امر کو نگراں قرار دیا اور اس کو اتنا اختیار دیا کہ اگر افراد کے جائز تصرفات بھی معاشرہ کے حق میں مضر ہوتو ان کے ان تصرفات پر پابندی لگادے اور اس طرح اجتماعی مفاد کا تحفظ کرے۔
اسلام نے اس طریقۂ کار کو صرف اس لئے اختیارکیاکہ اس کا نصب العین سماج میں اجتماعی عدالت اور توازن کا قائم کرنا تھا اور ظاہر ہے کہ زمانہ کے حالات اور مکانات کے تغیرات سے عدالت کے تقاضے بدل جایاکرتے ہیں۔ایک ماحول کا عدل دوسرے ماحول کے حق میں ظلم ہوجاتاہے ایک زمانہ کی عدالت دوسرے زمانہ کے لئے عذاب بن جاتی ہے۔زمانہ کے حالات اور تغیرات بھی اتنے رنگارنگ اور گوناگوں ہیں کہ ان غیر متناہی تغیرات کے لئے دفعات واحکام کا وضع کرنا غیر ممکن ہے۔
ضرورت اس بات کی تھی کہ کچھ بنیادی اصول مقررکرکے ایک ایسی حکومت قائم کردی جائے جو انہیں اصولوں کے ماتحت زمانہ کے حالات کی نگرانی کرے اور ہر دور تاریخ میں ایسے احکام نافذ کرے جو اس دورمیں اجتماعی عدالت کی بنیادیں مضبوط کرسکتے ہوں۔
قرآن کریم نے(َطِیعُوا اﷲَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاُوْلِی الْأًمْرِ مِنْکُمْ) میں اسی سلطنت اور اقتدار کی طرف اشارہ کیاہے اور یہ واضح ہے کہ اقتدار اعلیٰ کو اس قسم کی دخل اندازی کا پوراپورا اختیار ہے۔مسلمانوں میں اگرچہ اولی الامر کے اوصاف وشرائط کے بارے میں اختلاف ہے لیکن اتنا مسلم ہے کہ ان حضرات کو اسلامی نظام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک تصور کیاجائے گا۔
یہ اور بات ہے کہ ان کے اقتدار کا دائرہ بھی کلی احکام اور بنیادی اصول کے ساتھ تنگ ہو جایاکرے گا۔یہ امت کے مصالح عامہ کی خاطر معاملات میں دخل اندازی کرسکتے ہیں۔لوگوں کی آزادی پر پابندی لگاسکتے ہیں۔لیکن ان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ سودخوری اور خیانت کو جائز کردیں۔قانون ملکیت کو باطل کردیں اس لئے کہ ان کے اختیارات انہیں اصولوں کے تخفظ کے لئے وضع کئے گئے ہیں اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں اختیارات سے اصولوں کوباطل کردیاجائے۔
ان کاکام یہ ہے کہ زمین کی آبادکاری،کانوں اور نہروں کی کھدائی جیسے مباح اور جائز کاموں کی نگرانی کریں۔جب تک لوگوں کے تصرفات مصالح عامہ کے لئے مضر نہ ہوں انہیں پوری آزادی سے استفادہ کرنے دیں۔اور جب یہ دیکھ لیں کہ اب یہ آزادی عمومی مفاد کے حق میں مضرہوئی جارہی ہے تو فوراً اس پر پابندی لگادیں تاکہ اجتماعی عدالت کے قیام میں کوئی دشواری نہ پیش آسکے۔
اقتدار اعلیٰ کے یہ وہ اختیارات تھے جنہیں سرکار دوعالم نے خود بھی صرف فرمایاہے۔جیساکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے مدینہ کے نخلستانوں کی چھوٹی چھوٹی نہروں کے بارے میں یہ حکم فرمایاہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پانی پر قبضہ نہ جمایاجائے بلکہ دوسروں کو استفادہ کا موقع دیاجائے اس کے علاوہ ایک مستقل اعلان کر دیاتھا۔ لاضرر ولا ضرار (وسائل الشیعہ کتاب احیاء الموت)
فقہاء اسلام سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ پانی سے روک دینایاگھاس سے استفادہ کرنے کا موقع نہ دینا کوئی فعل حرام نہیں ہے۔
ہر شخص اپنے مال میں پورے پورے اختیارات رکھتاہے لیکن اس کے باوجود سرکار رسالت کی یہ نہی اور ممانعت اس بات پر صاف طریقہ سے دلالت کرتی ہے کہ آپ بحیثیت رسول کوئی کلی یا عام قانون نہیں بیان کررہے تھے بلکہ اقتدار اعلیٰ کے دیئے ہوئے
اختیارات کو صرف کرکے مباح اور جائز اقدام پر پابندی لگارہے تھے۔اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ روایت میں لفظ نہی نہیں ہے بلکہ قضاوت کا لفظ ہے جس سے کسی حکم خاص کا اظہار ہوتاہے۔
(3)اجتماعی عدالت
اسلامی اقتصادیات کا تیسرا رکن ہے اجتماعی عدالت۔
اس کا مقصد اسلام کی نظرمیں یہ تھاکہ ملکی ثروت کی تقسیم عادلانہ انداز سے ہواور اسلام کے وہ اعلیٰ اقدار بھی محفوظ رہیں جن کے لئے یہ سارے قوانین بنائے گئے ہیں۔
یادرہے کہ اسلام جب بھی عدالت کا ذکرکرتاہے تو اس سے مراد عدالت کا تجریدی مفہوم نہیں ہوتااور نہ یہ کوئی ایسا مبہم لفظ ہوتاہے کہ ہر شخص کو اس کی تشریح و تفسیر کرنے کا حق حاصل ہوبلکہ اس نے اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ عدالت سے اپنا مقصد بھی واضح کردیاہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ عدالت انسان کے رگ وپے میں اس طرح سرایت کرجائے کہ ہر شخص کی رفتار سے عدالت کی آواز سنائی دے۔اسلام نے اپنی اس عدالت کی بنیاد دوچیزوں پر رکھی ہے اور دونوں کے الگ الگ تفصیلات بیان کئے ہیں۔
پہلی بنیاد ہے باہمی کفالت۔
اور دوسری بنیاد ہے اجتماعی توازن
یہی دونوں باتیں ہیں جن سے اسلامی اقدار نمایاں ہوتی ہیں۔اورانہیں سے اجتماعی عدالت کی نشان دہی ہوتی ہے۔
اسلام نے انسانی معاشرہ کی ایجاد میں جواقدامات کئے ہیں ان میں یہ پہلو ایک
نمایاں حیثیت رکھتاہے۔خود سرکاررسالت نے اپنے اعلان حکومت کے ساتھ جس نکتہ کا اعلان کیا تھا وہ یہی تھا۔''َیُّہَا النَّاسُ'' اپنے لئے کچھ پیشگی روانہ کر دو تمہیں معلوم ہے کہ ایک ایسا موقع بھی آئے گا ۔جب تم گھبراکر اپنے جانوروں کو بغیر کسی نگرانی کے چھوڑدوگے اور پروردگار تم سے سوال کرے گا۔
کیا تمہارے پاس ہمارا رسول نہیں آیاتھا؟کیا ہم نے تمہیں مال کثیر نہیں دیاتھا؟ پھر تم نے کیاکیا؟
اس وقت سوائے یمین ویسار نظرکرنے کے اور کیاچارہ ہوگا۔سامنے عذاب جہنم ہوگا اب اگر کوئی شخص اپنے کو اس عذاب سے بچانا چاہتاہے تو اسے چاہئے کہ اس امر کی کوشش کرے خواہ ایک دانہ خرماسے کیوں نہ ہو بلکہ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو ایک کلمۂ طیب ہی سے سہی۔ایک نیکی کا عوض دس سے سات سو تک چلاجاتاہے۔والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ
اس کے بعد جب سیاسی اعمال کی ابتدا کی توسب سے پہلے مواخات(باہمی برادری)کی بنیادڈالی اس لئے کہ باہمی امداد وکفالت کا اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہوسکتا تھا۔
اسلامی اقتصادیات کے بنیادی ارکان یہ ہیں:
(1) مرکب ملکیت جس کی روشنی میں ثروت کی تقسیم ہو۔
(2) محدود آزادی جس سے پیداوار، تصرف،صرف وغیرہ کی نگرانی کی جائے۔
(3) اجتماعی عدالت جس کی بناپر باہمی کفالت اور اجتماعی توازن کے اصول قائم کئے جائیں۔
اسلامی اقتصاد کی دو بنیادی صفتیں اس کے جملہ احکام وقوانین میں نمایاں طور پر نظرآتی ہیں۔ایک واقعیت اور ایک خلاقیت۔
اسلام نے اپنے اصولوں میں واقعیت کے ساتھ اخلاقی پہلو کا بھی لحاظ رکھاہے اور یہ لحاظ صرف نتیجہ کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ طریقے بھی ایسے ہی اختیار کئے ہیں جن میں
واقعی اوراخلاقی دونوں پہلو نمایاں ہوں۔
نتیجہ کے اعتبار سے واقعیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نظام سے ایسے مقاصد حاصل کرنا چاہتاہے جو انسانی طبع وضمیر کے موافق ہوں۔
نہ احکام کی زنجیروں سے جکڑکر قوانین سے پامال کرنا چاہتاہے اور نہ لفظوں کی بازی گری سے ہوائی فضامیں پرواز کرناچاہتاہے۔اشتمالی حکومت یہ خیالی پلاؤ پکاسکتی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب انسان اپنے تمام داخلی کیفیات اور باطنی جذبات واحساسات سے الگ ہوکر ایک ایسی شکل اختیار کر لے گا جس سے اپنی پوری آمدنی کو بلاکسی جبروکراہ کے پورے سماج پر تقسیم کر دے گا لیکن اسلام اس قسم کے خواب نہیں دیکھتااور نہ امت کو ایسے سبزباغ دکھاناچاہتاہے۔وہ وہی معاشرہ قائم کرناچاہتاہے جس میں انسان اسی زمین کا انسان رہے اور پھر اعلیٰ اقدار کا تحفظ کرے۔
طریقہ کی واقعیت کا عالم یہ ہے کہااس نے اتنے اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لئے صرف واعظوں اور مرشدوں کی بیانات پر اکتفا نہیں کی بلکہ ایسے قوانین بھی وضع کردیئے جو ایک ایسے ہی معاشرہ کی ایجاد کے پورے پورے ضامن ہوں۔وہ باہمی کفالت کو قضاو قدر کے حوالے نہیں کرتابلکہ اس کے اسباب اپنے احکام وقوانین میں تلاش کرتاہے۔وہ اجتماعی عدالت وتوازن کو اتفاقی حادثہ نہیں قرار دیتابلکہ اپنے احکام کا حتمی نتیجہ تصور کرتاہے۔
اخلاقی اعتبار سے واقعیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے اقتصادی نظام کے رواج میںان طریقوں کا قائل نہیں ہے جن کا انسان سے کوئی تعلق نہ ہو اور جن سے قدرتی طور پر نتیجہ حاصل ہوجائے بلکہ وہ اپنے مقاصد ونتائج کو اخلاقی رنگ سے حاصل کرنا چاہتاہے۔
اس کا یہ مقولہ نہیں ہے کہ مزدوروں کی زندگی ذرائع پیداوار کے ذمہ ہے جو حتمی طور سے اسے زندہ رکھیں گے۔بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی زندگی معاشرہ کا ایک اخلاقی
فریضہ ہے جسے ادا کرنا سب پر لازم ہے اور جس کا ایجاد کرنا ہر صاحب صلاحیت کے لئے ضروری ہے۔
طریقہ کی اخلاقیت کا یہ عالم ہے کہ اس نے اپنے مقاصد میں فقط واقعیت پر اکتفا نہیں کی۔وہ یہ نہیں چاہتاکہ میرامقصد حاصل ہوجائے۔خواہ کوئی طریقہ بھی استعمال کیاجائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان طریقوں میں بھی ایک اخلاقی اندازہو۔
وہ اپنے مقصد کی تحصیل کے لئے یہ بھی کر سکتاتھاکہ امت سے اموال کو سلب کرکے فقراء پر تقسیم کردے۔اور اس طرح اجتماعی توازن قائم ہوجائے لیکن اسے یہ کسی طرح بھی پسندنہیں ہے وہ تو اس عمل کو انسان ہی کے ہاتھوں سے دیکھنا چاہتاہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس نے اکثرطریقوں کی عبادت قرار دے دیاہے تاکہ اس کی ادائیگی اندرونی جذبات اور داخلی احساسات کی بناپر ہواور اس طرح انسان اقتصادی ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی بھی ہو اور مذہب واقعی ہونے کے ساتھ ساتھ مفاہیم واقدار کا معترف بھی ہو۔
نفسیاتی عوامل کے لئے اسلام کا یہ اہتمام واحترام کوئی عجیب بات نہیں ہے بلکہ ہر صاحب بصیرت انسان یہ جانتاہے کہ انسان کی شخصیت کی تشکیل میں اس کے نفسیات کو بہت بڑادخل ہوتاہے اور یہی شخصیت اس کے اجتماعی اور سماجی حالات پراثرانداز ہوتی ہے۔اب اگر اس شخصیت کی اصلاح کرلی گئی اور اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیاگیاتو پھر اجتماعی سدھاربھی بآسانی ممکن ہوجائے گا۔
دنیا جانتی ہے کہ آج یورپ میں اقتصادی فریاد اسی نفسیاتی اصلاح کے نہ ہونے کی بناپر ہے۔
نفسیات کے اقتصادیات سے گہرے تعلق کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتاہے کہ اقتصادیات کے عرض وطلب کے مسائل انہیں نفسیاتی رغبت وکراہت سے پیداہوتے
ہیں پیداوار کا اضافہ ونقصان مزدور کی انہیں نفسیاتی کیفیات ہی کا نتیجہ ہوتاہے۔وغیرہ وغیرہ
یہی وجہ توہے کہ اسلام اپنے تعلیمات میں فقط انسان کے ظاہر پر نظرنہیں رکھتابلکہ اس کے نفس کی گہرائی میں اترجاتاہے تاکہ اس کی داخلی زندگی کا علاج کرکے اسے اپنے ماحول کے لئے سازگار بنائے اور اس کے بعد اپنے احکام کو اس پرنافذ کرے تاکہ وہ بلا تکلف انہیں قبول کر سکے۔
وہ حصول مقصد کے لئے ہر ایک طریقہ کو نہیں اپناتاہے بلکہ صرف ان طریقوں سے کام لیتاہے جن میں ہدف ومقصد کی جھلک دکھائی دیتی ہو۔جن میں نفسیاتی محرکات کا جلوہ نظرآتاہو۔جن کے خمیر میں ضمیر کے جذبات واحساسات ہوں تاکہ اس طرح داخلہ وخارجہ سیاستوں میں یک رنگی اور واقع واخلاق میں یگانگت پیداہوسکے۔
(2)اسلامی اقتصادایک مجموعہ کا جزء ہے
اسلامی اقتصادپر گفتگوکرتے وقت یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ اس کے ہر حکم کو الگ الگ مستقل طور سے زیر بحث لایاجائے۔سودخوری کی حرمت اور انفرادی ملکیت جیسے تمام احکام کو مذہب سے جداگانہ حیثیت دے دی جائے اور پھر ان کے بارے میں گفتگو کی جائے بلکہ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اقتصادیات کو دیگر اجتماعی اور سیاسی مسائل سے الگ کرکے دیکھاجائے۔
اس سلسلہ کا صحیح طریقۂ بحث یہ ہے کہ اقتصادیات کے مسئلہ کو اس سانچہ میں ڈھال کر دیکھیں کہ جو حیات انسانی کے تمام شعبوں پر حاوی ہواس لئے کہ اس قسم کی محیط
نظرعام کوتاہ نظروں سے مختلف ہوتی ہے۔آپ ایک ہی خط کو دو طریقوں سے دیکھیں تو اس کی حیثیتیں مختلف ہوجائیں گی۔
ممکن ہے کہ وہ مستقل طریقہ پر طویل معلوم ہولیکن ایک نقشہ کے ضمن میں آکر کوتاہ نظر آئے گا۔بعینہ یہی حال اقتصادی مسائل اور دیگر مسائل زندگی کا ہے کہ جب تک اقتصادیات کو حیات کے تمام شعبوں کے ساتھ ملاکر نہ دیکھیں گے ان کی صحیح نوعیت معلوم نہ ہوسکے گی۔
اسلامیات پرگفتگو کرنے کے لئے ایک دوسرا فریضہ یہ بھی ہے کہ اس ماحول اور سر زمین کا بھی جائزہ لے لیاجائے۔جن پر ان احکام نے جنم لیاہے اور اپنی زندگی کے دن گذارے ہیں۔اس لئے کہ کسی بھی نظام زندگی کو اگر اس کے ماحول سے الگ کر لیاجائے گا تو اس کی صحیح حیثیت معلوم نہ ہوسکے گی۔
اسلام کے احکام وقوانین نے بھی ایک خاص فکری سرزمین پر اپنی نشودنما کے دن گذارے ہیں ہمیں اس سرزمین کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔
اسلام کے جملہ اقتصادی احکام باہم مربوط ومتحد ہیں۔انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کرنا چاہئے۔
پھر پورا اقتصادی نظام ایک مذہب سے مربوط ہے جس میں متعدد شعبے پائے جاتے ہیں اور پھر یہ مذہب بھی ایک خاص سرزمین اور ایک مخصوص ماحول سے تعلق رکھتاہے جس پر اس کے احکام وقوانین نے پرورش پائی ہے۔لہٰذا اقتصادیات کی بحث کو مذہبی طورپر اور احساسی وجذباتی ماحول سے الگ کرکے محل بحث میں نہیں لایاجاسکتا۔
اسلامی معاشرہ کا ماحول چند عناصر سے مرکب ہوتاہے۔
عقیدہ، مفاہیم واقدار ، جذبات واحساسات
(1)عقیدہ
وہ مرکزی قاعدۂ فکر جو مرد مسلم کی آفاقی نظرکے حدود معین کرتاہے۔
(2)مفاہیم واقدار
جو کائنات کے بارے میں عقیدہ کی روشنی میں اسلامی افکار کی عکاسی کرتے ہیں۔جن سے یہ معلوم ہوتاہے کہ بنیادی عقیدہ کو پیش نظررکھتے ہوئے کائنات کے موجودات کا مفہوم کیاہوسکتاہے اور ان کی قدریں کیاہیں؟
(3)جذبات واحساسات
جو انہیں مفاہیم واقدار کی بناپر نفس انسانی میں ابھرتے ہیں۔صرف اس لئے کہ کائنات کا اسلامی مفہوم مرد مسلم کے دل میں ہر شیء کی طرف سے ایک خاص شعور واحساس کی بنیاد ڈالتاہے اور اسی کے اعتبار سے جذبات و عواطف پیداکرتاہے۔
مقصد یہ ہے کہ جذبات وعواطف مفاہیم واقدار سے پیداہوتے ہیں اور مفاہیم عقیدہ کی روشنی میں معین ہوتے ہیں لہٰذا کسی ایک نکتہ پر بھی نظر کرنے کے لئے ان تمام
جہات کا پیش نظررکھنا ضروری ہے۔
ہمارے اس بیان کی ایک واضح سی مثال ہے تقویٰ اس کا مفہوم اسلامی عقیدۂ توحید کے زیر اثرپیداہوتاہے اور پھر تمام شرافتوں اور کرامتوں کا منبع ومرکزبن جاتاہے اور مرد مسلم کے دل میں اہل تقویٰ کی طرف سے ایک خاص جذبہ کی ایجاد کرتاہے جس کا نام ہے جذبۂ احترام و تعظیم، گویاکہ اسلامی احکام کی سرزمین اور اس کا ماحول۔عقیدہ ومفاہیم اور مخصوص احساسات وعواطف سے مل کر مرکب ہوتاہے اور انہیں اسباب وموثرات کی بناپر مذہب ایک ایسا قابل تجزیہ مجموعہ ہوجاتاہے جس کے کسی ایک جزء پر بھی اس وقت تک گفتگو نہیں ہوسکتی جب تک باقی اجزاء کو ساتھ نہ ملایاجائے اور پھر جب یہ تمام اجزاء ایک جگہ جمع ہوکر ایک مجموعہ کی شکل اختیار کرلیں گے تو اسلام کو اس بات کا یقین پیداہوجائے گا کہ وہ اپے عالمی پیغام کو صحیح طریقہ سے پہنچاسکے گا۔اور وہ انسان کو اسی سانچے میں ڈھال سکے گا جس میں ڈھالنے کے لئے اس نے اس دنیا میں قدم رکھاتھا۔سعادت مندی اور رفاہیت کی فراوانی ہوگی اور انسانی معاشرہ کو اس سے مکمل استفادہ کا موقع ملے گا۔
اب اگر ہم تمام اجزاء کو الگ الگ رکھ کر اس بات کی امید کریں کہ اسلام اپنے پیغام کو منزل مقصود تک پہنچادے گا اور اپنی مہم میں کامیاب ہوجائے گا تو یہ ایک موہوم خیال ہوگا جس کی کوئی واقعیت نہ ہوگی اس لئے کہ کسی انجینئر کے نقشہ کا حسن اسی وقت ظاہر ہوتاہے جب اس کے مطابق مکمل عمارت تیار ہوجائے لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک گوشہ تعمیر کرکے اسی کے مطابق حسن کی امیدکرے تو اس کی یہ امیدایک وہم وخیال وجنون سے زیادہ وقعت نہ رکھے گی۔
اسلام نے اپنے نقشۂ تعظیم سے انسانی فلاح وبہبود کی ضمانت ضرورلی ہے لیکن یہ اسی وقت جب اس نقشہ کے مطابق مکمل تعمیر عالم وجود میں آجائے اور اس کو کامل شکل میں سماج پر منطبق کردیاجائے۔اب اگر اس کے شیرازہ کو منشر اور اس کے اجزاء کو پریشان کر
دیاجائے تو اس سے یہ توقع بالکل غلط ہوگی اور اس میں نظام زندگی کا کوئی قصور نہ ہوگا۔ ساری کوتاہی انطباق کی ہوگی۔
علوم طبیعیہ بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ عالم کی ہر شیء ایک خاص فائدہ اور خاصہ کی حامل ہوتی ہے لیکن یہ فائدہ انہیں مخصوص حالات میں حاصل ہوتاہے جن میں یہ فائدہ رکھاگیاہے اب اگر کوئی شخص حالات کی پرواکئے بغیر وہی استفادہ کرنا چاہے تو سوائے خسارت اور ناامیدی کے کوئی شیء حاصل نہ ہوگی۔
اس تمہید کے بعد ضرورت تھی کہ ہم اسلامی اقتصادیات کے ان تمام تعلقات و روابط کو ظاہر کرتے جو انہیں عقیدہ،ماحول، جذبات سیاست، اجتماعیت یادیگر شعبہ ہائے زندگی سے حاصل ہیں۔لیکن ظاہر ہے کہ اس مختصر بیان میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔نمونہ کے طورپر صرف چند روابط کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے یہ واضح ہوجائے کہ ان احکام کے متصل اور منفصل کی صورت میں نتائج کس قدر مختلف ہوجاتے ہیں۔
(1)اقتصادکا ارتباط عقیدہ سے
عقیدہ مذہب کی روحانیت کا مرکز اور اس کا سرچشمہ ہے اسی زمین سے اس کے احکام وقوانین کے سوتے پھوٹ کر نکلتے ہیں اور یہی مردمسلم کی نفسیت کو مذہبی سانچہ میں ڈھال کر اسے مسلم انسان بناتاہے۔
عقیدہ ہی انسان کے اعمال کو ایمانی رنگ دے کر اس میں ایک معنوی قیمت پیداکرتاہے۔
ان تمام نتائج کے علاوہ جو خارجی طورپر ہمارے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں۔ عقیدہ ہی مردمسلم کے دل میں سکون واطمینان کی دولت ایجاد کرتاہے اس لئے کہ اس کا مذہب اسی عقیدہ کا تفصیلی پرتوہے۔
مختصر یہ ہے کہ اسلام میں احکام کے نفاذ کی ضمانت،اعمال کا ایمانی رنگ و روپ اور سکون واطمینان وہ خصوصیات ہیں جو اسلامی اقتصادیات کو عقیدہ کی برکت سے حاصل ہوئے ہیں۔اب اگر اقتصادیات کو عقیدہ سے الگ کر دیاجائے تو اس کے جملہ خصوصیات کا خون ہوجائے گا اور اس کا صحیح نقشہ ذہن میں نہ آسکے گا۔
(2)اقتصادیات ومفاہیم
کھلی ہوئی بات ہے کہ کائنات کے موجودات کے بارے میں اسلام نے جن مفاہیم کو اختیارکیاہے ان کا اثر اس کے اقتصادیات پر بھی پڑے گا۔
مثال کے طور پر اس نے انفرادی ملکیت کو سلطنت مطلقہ کے بجائے ایک خاص مسئولیت اور ذمہ داری کا رنگ دیاہے۔
فائدہ کے مفہوم کو عام عادی مفاہیم سے نکال کر روحانیت اور آخرت کا رنگ دیاہے جس کی بناپر عام نقصان بھی فائدہ بن سکتاہے۔
اس طرز فکر کا لازمی نتیجہ یہ ہوگاکہ انفرادی ملکیت کا مالک اپنے تصرفات میں ایک مسئولیت کا احساس رکھے گا اور اس طرح اس کی آزادی محدود ہوجائے گی۔
فائدہ کا طالب اپنا مطمح نظرصرف مادی فائدہ کو نہیں قرار دے گا بلکہ وقت ضرورت
ان مادی فوائد کو قربان بھی کردے گا اور اس طرح اقتصادیات ان مفاہیم واقدار سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے لیکن اگر دونوں کو الگ الگ کر دیاجائے گا تو پھر رنگ ہی دوسرا ہوجائے گا اور مذہب کا مکمل فائدہ حاصل نہ ہوسکے گا۔
(3)اقتصادیات وجذبات
یہ ایک بالکل واضح حقیقت ہے کہ اسلامی مفاہیم سے وجود میں آنے والے جذبات واحساسات بھی اس کے اقتصادیات پربڑی اچھی طرح سے اثرانداز ہوں گے۔
ایک جذبۂ اخوت کا حامل مسلمان جب ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کرے گا تو اقتصادی زندگی میں کفالت وضمانت کے اصول بڑی آسانی سے رواج پاسکیں گے اور ان کے لئے کسی جبری اور قہری طاقت کی ضرورت نہ ہوگی۔
(4)اقتصادیات اور مالی سیاست
دین اسلام نے اپنی مالی سیاست کو اقتصادیات سے الگ حیثیت نہیں دی۔اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کو کسی نہ کسی طرح مال ملتارہے اور وہ اس میں خاطر خواہ تصرف کرتی رہے بلکہ اس نے اس سیاست کو اقتصادی اغراض ومصالح کے حاصل کرنے کا وسیلہ وذریعہ قرار دیاہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان مالیات سے باہمی کفالت اور اجتماعی
توازن کی ایجاد کی جائے اور معاشرہ کو اس کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچادیاجائے۔ظاہر ہے کہ ان حالات میں اقتصادیات کو سیاست سے الگ کرکے محل بحث میں نہیں لایاجاسکتاہے۔
(5)اقتصادیات اور سیاسی نظام
دین اسلام نے حکومت کو جس قدر اقتصادی اختیارات دیئے ہیں اگر ان کو سیاست سے الگ کر لیاجائے تو وہ ایک ظلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔لیکن انہیں اختیارات کو اگر سیاست کے آئینہ میں دیکھا جائے اور یہ اندازہ کر لیاجائے کہ اسلام ہر کس وناکس کو عوامی قسمت کا مالک نہیں بناتابلکہ اس کے لئے عصمت یاکم از کم عدالت کو شرط قرار دیتاہے(جیسا کہ بعض مسلمانوں کا خیال ہے)تو یہ اعتراض رفع ہوجائے گا اور انسان سمجھ لے گاکہ عدالت وعصمت کے بعد ظلم کا تصور مہمل ہے۔
(6)سودخوری اور اجتماعی عدالت
اسلامی احکام میں اگر سودکی حرمت اورممانعت کو تمام احکام سے الگ کرکے دیکھاجائے تو اس سے بہت سے ایسے مشکلات پیدا ہوتے ہیں جن کا حل کرنا بظاہر ناممکن ہے لیکن اگر اس ایک حکم کو باقی احکام کے ساتھ منضم کرلیاجائے اور یہ دیکھاجائے کہ اسلام نے ان تمام مشکلات کو باہمی کفالت اور اجتماعی توازن اور مضاربہ(1)مضاربہ کامطلب یہ
ہے کہ انسان کسی شخص کو سرمایہ دے کر اس سے اس شرط پر تجارت کرائے کہ فائدہ میں دونوں افراد کسی ایک مقررہ نسبت سے شریک رہیں گے۔خواہ وہ آدھی ہویاچوتھائی یا کچھ اور)جیسے معاملات میں حل کر لیاہے تو پھر کوئی دشواری باقی نہ رہ جائے گی۔
رہ گیا یہ سوال کہ ان مشکلات کو کہاں اور کس طرح حل کیاگیاہے؟تو اس کے جواب کا انتظار کیجئے۔
(7)انفرادی ملکیت اور جہاد
اسلام نے معرکۂ جنگ میں ولی امر کو یہ اختیار دیاہے کہ وہ اسیروں کو غلام بناکر مال غنیمت کی طرح مجاہدین پر تقسیم کر دے۔
مسیحیت پرست، اسلام دشمن افراد نے یہ خیال کرلیاکہ اسلام بھی انہیں غلام پسند مذاہب میں سے ہے جو تاریخ کے تنگ وتاریک دور میں حکومت کررہے تھے اور انسانیت کو ذلت ورسوائی کی زندگی گذارنے پر مجبور کر رہے تھے۔جن کے پنجۂ استبداد سے صرف یورپ نے نجات دلائی ہے ورنہ وہ آج تک اسی تحقیر وتذلیل کا شکار رہتے۔
حالانکہ انہیں اسلام کے اس حکم پر تنقید کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے تاکہ اس کی نظرمیں مال غنیمت کیاہے؟اور ولی امر کو اسیروں کوغلام بنانے کے اختیارات ماحول میں دئے گئے ہیں؟اور پھر وہ حاکم اور ولی امر کون ہے جسے اتنے اہم اختیارات دے دئے گئے ہیں۔
جب یہ تمام گوشے نظرآجائیں گے تو اسلام پر صحیح تنقید کا حق حاصل ہوگا اور غنیمت کے بارے میں اس کا واقعی موقف معلوم ہوسکے گا۔
غنیمت کے بارے میں اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صرف جائز قسم کے جہاد اور عقائدی جنگ میں حاصل شدہ مال کا نام ہوتاہے۔اگر جنگ کو عقائد سے کوئی تعلق نہ ہواور وہ غارتگری ،ملک گیری کا وسیلہ ہوتواس میں ھاصل شدہ مال کو غنیمت نہیں کہاجاسکتا۔
یعنی مال کے غنیمت میں داخل ہونے کی دوشرطیں ہیں:
(1) جنگ ولی امر کے حکم سے اسلام کی دعوت کے سلسلہ میں ہو۔جاہلیت کی طرح لوت مار اور غارت گری کو اسلامی جہاد نہیں کہاجاسکتاجیساکہ سرمایہ دارممالک میں آج بھی رائج ہے۔
(2) اسلامی قائد پہلے دلائل وبراہین کی روشنی میں اپنے عقائد کو پیش کرکے فریقِ مخالف کو ان کے قبول کرنے کی دعوت دے اور جب اتمام حجت ہوجائے اور مقابل منطقی جوابات سے عاجزآکر برسرپیکار ہوجائے تو پھر مادی قوت سے کام لے کر ان مفسد عناصر کا استیصال کردے جن کے پاس عنادوتکبر،جہالت وغرور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ایسے وقت میں معرکہ جہاد سے جو مال حاصل ہوگااسے غنیمت کہاجائے گا۔
مال غنیمت میں جو لوگ گرفتار ہوکر آئیں گے ان کے ساتھ تین قسم کے برتاؤ کئے جائیں گے:
(1) انہیں بالکل معاف کرکے آزاد کر دیاجائے۔
(2) ان سے فدیہ لے کرانہیں چھوڑدیاجائے۔
(3) انہیں غلام بنالیاجائے۔
ظاہر ہے کہ غلامی تین صورتوں میں سے صرف ایک صورت کا نام ہے جس پرعمل صرف انہیں حالات میں ہوگا جب ولی امر کی نظرمیں یہ صورت باقی دونوں صورتوں سے زیادہ مفید اور صالح ہو(جیساکہ علامہ حلی اور شہید ثانی وغیرہ نے فتویٰ دیاہے)اور پھر ولی امر بھی وہ شخص ہوگا جو زیورعصمت وطہارت سے آراستہ وپیراستہ ہو۔
اس کا کھلا ہوامطلب یہ ہے کہ اسیر باقی دونوں صورتوں کے نامناسب ہونے کی صورت میں ایک معصوم اور بے خطا انسان کی صوابدید کے مطابق عمل میں آئے گی اور اس طرح ان تمام اوہام واشکالات کا دفعیہ ہوجائے گا جو اسلام کی اسیری کے بارے میں پیش کئے جارہے ہیں۔
سوال یہ رہ جاتاہے کہ غلام بناناکن حالات میں زیادہ مناسب ہو سکتاہے۔
اس کا ایک مختصر جواب یہ ہے کہ جب فریقِ مخالف ان افرادمیں سے ہو جواپنے اسیروں کے ساتھ یہی سلوک کرتارہاہو اب اسے بھی غلام بنایا جائے تاکہ اسے اپنے عمل کی زشتی اور قساوت کا صحیح احساس ہوسکے۔اس کے علاوہ اسلام نے دستوری طور پر ان تفاصیل کو صرف اس لئے واضح نہیں کیاکہ اس نے ان تمام باتوں کا ذمہ دار ایک معصوم شخص کو قرار دیاہے اور ظاہر ہے کہ معصوم اپنی فکر ونظرمیں خطاکار نہیں ہوسکتا۔اس کی صوابدید ہمیشہ حق و واقع کے مطابق ہی رہے گی۔لہٰذا اس کے واسطے مزید ہدایات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اس کے علاوہ اگر اسلامی احکام کا وہ دور بھی دیکھیں جس میں یہ احکام انطباق کی منزلوں سے گذررہے تھے اور اسلام واقعی جہاد میں مشغول تھا تو ہمیں یہی نظرآئے گا۔
اسلام نے غلامی کا حکم صرف ان افراد پر منطبق کیاہے جو خود اپنے اسیروں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے ظاہر ہے کہ ایسے افراد کے حق میں ان کے عناد و تکبر کے بدلے میں اس سے زیادہ مناسب سلوک کیاہوسکتاہے؟
(8)اقتصادیات اور تغریرات
اسلامی اقتصادیات کے قانون''باہمی کفالت''اور''اجتماعی توازن''پر باقاعدہ نظرکرلینے کے بعد بہت سے وہ اعتراضات رفع ہوجاتے ہیں جن کا تعلق اسلامی تغریرات سے ہے،سرمایہ داری کی نظرسے چورکا ہاتھ کاٹ دینا ایک بہت بڑاسنگ دل اور تشدد آمیزا اقدام ہے اس لئے کہ وہاں اکثریت اپنے مقدر پر گریاں اور سرمایہ داری سے دست وگریباں ہے لیکن وہ ماحول جہاں اجتماعی عدالت کی بناپر ہر شخص کی زندگی کے متوازن اسباب مہیا کردیئے گئے ہوں اس میں ایسے بدکار انسان کے ساتھ اس سے بہتر اور کیا سلوک ہوسکتاہے؟
(3)اسلامی اقتصاد کا عمومی اسلوب
اسلامی اقتصاد اپنے دینی رنگ کی بناپر تمام دیگر نظام ہائے زندگی سے ایک ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھتاہے دین اس کی نظرمیں زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی اور اس کے تمام مشکلات کا معالج ہے۔اسلام جب کسی بھی شعبۂ زندگی کی اصلاح کرے گاتو اس کو دینی سانچے میں ڈھال کراللہ اور روز آخرت سے مربوط کردے گا۔
اس کا یہی دینی رنگ ہے جو اس کے اجتماعی مصالح کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کے بغیر ان مصالح کا حاصل کرناناممکن اور غیر معقول ہے۔
اس اجمال کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ دیکھنا پڑے گاکہ انسانی زندگی کے اجتماعی
مصالح کیاہیں اور ان کی کس حدتک ضمانت لی جاسکتی ہے تاکہ اسی تحقیق کی روشنی میں یہ دیکھاجائے کہ اس ضمانت کے اسباب کیاہوں گے؟اور پھرہم یہ ثابت کرسکیں کہ دین کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔
انسانی مصالح کو دوقسموں پر تقسیم کیاجاسکتاہے:
(1) وہ مصالح جن کا انتظام عالم طبیعت کے ذمہ ہے جیسے طبی ادویہ ظاہر ہے کہ ان مصالح کا کوئی تعلق اجتماعی نظام سے نہیں ہے بلکہ یہ انسان کا ذاتی مسئلہ ہے جو اسے خودہی حل کرناہے۔وہ اپنے اندرجراثیم رکھتاہے یہ جراثیم مرض پیداکرتے ہیں۔اب اس کافرض ہے کہ ان طبی ادویہ کا انکشاف کرکے انہیں استعمال کرے چاہے اسکی زندگی کسی اجتماع میں ہویا اجتماع سے باہرتن تنہازندگی کے دن گذاررہاہو۔
(2) وہ مصالح جن کی ذمہ داری اجتماعی نظام کے سرہے صرف اس بناپر کہ انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے وہ دوسروں سے تعلقات رکھتاہے اور ان تعلقات سے کچھ مشکلات پیداہوتے ہیں جن کا حل کرنا ضروری ہے جیسے وہ مصالح جنہیں انسان اجناس کے تبادلہ سے حاصل کرتاہے یاوہ مصالح جو بیکار اور عاجز افرادکی کفالت سے متعلق ہوتے ہیں۔پہلی قسم کانام ہے طبیعی مصالح اور دوسرے کا نام ہے اجتماعی مصالح۔
اب اگرانسان ان تمام طبیعی اور اجتماعی مصالح سے استفادہ کرناچاہتاہے تواس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان مصالح کا انکشاف کرے اور کوئی ایسی طاقت پیداکرے جو اسے ان مصالح کی ایجاد کی دعوت دے۔
ٹی، بی کی دواانسان اسی وقت معلوم کرتاہے جب اسے یہ اندازہ ہوجائے کہ اس مرض کی ایک دواہے اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور پھر اس تحصیل کا کوئی محرک بھی ہو۔
بیکاروں کی معیشت کی ضمانت بھی اسی وقت ہوسکتی ہے جب انسان اس کے فوائد
سے واقف ہو اور اس کی ایجاد کے محرکات اپنے نفس کے اندر پاتاہو۔
ان دونوں شرطوں کے بغیر ان مصالح سے استفادہ کرنا غیر ممکن ہے۔
انسانی مصالح کے بارے میں اس کے دوفرائض ہیں:
(1) ان مصالح کے ادراک کے طریقے معلوم کرے۔
(2) ان کی ایجاد کے اسباب پیداکرے۔
طبیعی مصالح کا تجزیہ بتاتاہے کہ انسان ان کی طرف سے بالکل مطمئن پیداہواہے وہ اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتاہے کہ ان مصالح کا علم حاصل کرسکے۔اس کی فطرت تجربات کی طرف راغب ہے اور تجربہ ہمیشہ بلند پروازی سکھاتاہے جیسے جیسے تجربات بڑھتے جائیں گے وہ اپنے مقصد سے قریب ترہوتاجائے گا۔
اسی صلاحیت کے ساتھ وہ ایک نفسیاتی جذبہ بھی رکھتاہے۔جو اسے ان مصالح کی ایجاد پر آمادہ کرتاہے۔اس لئے کہ طبیعی مصالح نفسانی محرک کے ساتھ ہمیشہ ہم آداز ہوتے ہیں۔
ٹی،بی کی دواکاایجاد کرنا کسی ایک آدمی کی مصلحت سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس میں ہر شخص کی مصلحت ہے اور انسان فطری طور پر ان مصالح کی تحصیل پرمجبور ہے یہی وجہ ہے کہ سارے انسان ہمیشہ ان مصالح کی فکر میں رہتے ہیں۔
اجتماعی مصالح بھی طبیعی مصالح ہی کے مانند ہیں یہاں بھی ادراک کے لئے محرکات اور ان کی ایجاد کے لئے عوامل کی ضرورت ہے لیکن سوال یہ پیداہوتاہے کہ کیا انسانی فکر میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان اجتماعی مصالح کا ادراک بھی کرے او رپھر ان کی ایجاد کی طرف متوجہ بھی ہو۔
عام طور سے یہ مشہور ہے کہ انسان ایک ایسی اجتماعی تنظیم کے ادراک ہی سے قاصر ہے جو اس کے اجتماعی مصالح کی ذمہ داراور اس کی افتاد طبع سے ہم رنگ ہو اس لئے کہ
یہ ادراک انسان کے تمام اجتماعی خواص کے علم وعرفان پر موقوف ہے اور تنا وسیع علم انسان کے اختیار سے باہر ہے۔
اس بیان سے ان حضرات کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی نظام انسان کے لئے مافوق طاقت کی طرف سے بننا چاہئے وہ خود اپنی محدود معرفت کی بناپر اس کے اسرار ورموز معلوم کرنے سے عاجز ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے دین کی ضرورت کا آغاز ہوتاہے اور انبیاء ومرسلین کی احتیاج ثابت ہوتی ہے۔
انبیاء ومرسلین وحی والہام کے ذریعہ اجتماعی مصالح کی تحدید کرتے ہیں اور ربوبی اشارے سے انسان کے نظام حیات کو تشکیل دیتے ہیں۔
لیکن ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ان مکمل اجتماعی مصالح کی طرح انسان طبیعی مصالح سے بھی ناواقف نہیں تھا؟تو کیا ان مصالح کے انکشاف کے لئے بھی انبیاء ومرسلین کی ضرورت تھی۔
نہ جانے کتنے افراد سل دوق کا شکار ہوکر چل بسے۔
نہ جانے کتنی مدت تک انسانیت اپنی لاعلمی کی بناپر ان مصائب وآلام میں مبتلا رہی۔
نہ جانے کتنے عرصہ کے بعد انسان میں یہ صلاحیت پیداہوئی کہ وہ ان امراض کی دواؤں کا انکشاف کرکے اپنی نوع کا تحفظ کرسکے تو کیا ان سابق ادوارمیں کوئی ایسا انتظام ہواتھا۔
ظاہر ہے کہ نہیں ہواتھا اس لئے کہ خالق کائنات نے انسان کو جس صلاحیت اور استعداد سے نوازاتھا اس پر اعتماد کرکے اسے اس معرکۂ زندگی میں ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر تجربہ کرتے کرتے ایک دن اپنے امراض کی صحیح دوادریافت کرلے گا اس کے لئے نہ کسی نبی کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی مرسل کی۔
یہی حال اجتماعی مصالح کا بھی ہے ۔انسان فی الحال ان صحیح تنظیمات کے ادراک
سے قاصر ہے جو اس کے واقعی مصالح کے حصول میں مددگار ثابت ہوسکیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی عملی طاقت صرف کرکے مسلسل تجربات کرے اور پھر ایک ایسے نظام تک پہنچ جائے جو اس کے حق میں صالح اور مناسب ہو، انسان کا موجودہ نقص واضح ہے کہ اس کے نظام آئے دن بدلتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا مستقبل اتنا تاریک نہیں ہے اور اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ طبیعی مصالح کی طرح ایک دن ان مصالح کو بھی معلوم کرلے گا اور اس طرح انسانیت خیر وسعادت اور فلاح وبہبود کے ساحل تک پہنچ جائے گی۔
اس بیان کی روشنی میں یہ کہاجاسکتاہے کہ انسان طبیعی مصالح کی طرح اجتماعی مصالح کے ادراک کی بھی صلاحیت رکھتاہے۔اور اسے اس ادراک کے لئے کسی نبی ومرسل کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ ہر اعتبار سے ناقص تھا اور رفتہ رفتہ کامل ہوتاگیا، کسی منزل کو حاصل کرچکاہے اور کسی منزل کو مستقبل میں حاصل کرسکتاہے۔لہٰذا دین کی احتیاج کی یہ بنیاد بالکل بے بنیاد ہے۔
حقیقت امریہ ہے کہ انسانیت کے لئے اجتماعی مصالح کے بارے میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ ان کے علم وادراک سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اس عامل ومحرک سے ہے جس کی بناپر وہ صالح نظام عالم وجود میںآئے گااور انسانیت اس کے برکات سے استفادہ کرے گی اور یہی وہ نکتہ ہے جہاں طبیعی اور اجتماعی مصالح میں فرق ہوجاتاہے۔
طبیعی مصالح ہمیشہ اس کے ذاتی مفاد سے متعلق تھے اس لئے ان کی تحصیل کے لئے وہ خود کوشش کیاکرتاتھا اس کے لئے کسی خارجی محرک کی ضرورت نہ تھی لیکن اجتماعی مصالح کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے وہ کبھی اس کے ذاتی مفاد کے خلاف ہوجاتے ہیں۔ایسے حالات میں سوال یہ پیداہوگاکہ ان کا محرک کون ہوگا۔نفسانی جذبات تو مخالفت
ہی کریں گے ان کی ایجاد کی کوشش نہ کریں گے۔اس لئے کہ یہ غیر ممکن ہے کہ فقیروعاجز افراد کی ذمہ داری کے قانون وہ لوگ نافذ کریں جن کے پاس سرمایہ ہے اور انہیں کے سرمایہ سے ان کا رزق مہیاکیاجاتارہے گا؟یازمین کی قوی ملکیت کی حمایت وہ افراد کریں جو انفرادی ملکیت کے دلدادہ اور اپنی ممتاز شخصیت کے خواہاں ہیں؟
سوال پھر سامنے آئے گاکہ ایسے اوقات میں ان مصالح کی ایجاد کا وسیلہ کیاہوگااور کن اسباب کی بناپر انہیں معاشرے میں رائج کیاجائے گا؟انسان کی نفس پرستی اور خودپسندی کا خاتمہ کیونکر ہوگا؟اس میں اجتماعی مفاد کی صلاحیتیں اور ایثار کے جذبات کیوں کرپیداکئے جائیں گے۔
انسان کے اجتماعی مصالح ایک ایسے عظیم محرک کے محتاج ہیں جو انہیں عالم وجود میں لے آئے اور ہر شخص کو ان کے ایجاد کی ذمہ داری محسوس کرائے خصوصاًان ناخوشگوار حالات میں جب ان میں اور ذاتی مفاد ومصالح میں تضادپیداہوجائے اور وہ ان کی مخالفت پر آمادہ ہوجائیں۔
طبیعی علوم اس مسئلہ کے حل کرنے سے قاصر ہیں
بعض زبانوں پریہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں کہ جس علم نے یہ بے پناہ ترقیاں کرلی ہیں۔
جس نے فکروحیات وکائنات کے میدانوں میں ایسے ایسے اقدامات کئے ہیں جن کی بناپر وہ اسرار کائنات کی گہرائیوں میں اترگیاہے۔
جس نے عالم کے پیچیدہ سے پیچیدہ معموں کو حل کر لیاہے۔
جس نے ذرہ کاشکم چاک کرکے اس میں سے طاقت نکال لی ہے۔افلاک کو اپنی زدمیں لاکر ان پر راکٹ اڑادیئے ہیں۔جہاز ایجاد کرکے فضاؤں کومسخر کرلیاہے اور طبیعت پرقابو حاصل کرکے ہزاروں میل کی آوازوں کواپنے سامنے حاضر کرلیاہے۔
جس نے اتنی قلیل مدت میںاتنے زیادہ فتوحات کرلئے ہیں کیا اس کے امکان میں یہ بات نہیں ہے کہ اپنے وسیع معارف اور محیط معلومات کی بنار ایک ایسا معاشرہ ایجاد کردے جو عالم بشریت کے لئے صالح اور اس کے اجتماعی مصالح کے لئے مناسب ومفید ہو۔اور اگر ایسا ممکن ہے تو پھر کیاوجہ ہے کہ وہ تمام معرکے تواپنے دست وبازو کی قوت سے سرکرے اور صرف اس میدان میں دوسرے افراد کا دست نگر ہوجائے؟
حقیقت یہ ہے کہ یہ ناقص خیال علوم کی ذمہ داریوں سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔علم ہزار ترقی کے بعد بھی انکشاف ہی کا ایک ذریعہ ہوتاہے اس کا کام اسرار ورموز کا ظاہر کر دینا ہوتاہے۔
اس کا فرض یہ ہے کہ وہ کائنات کے ہر مسئلہ کی بہتر سے بہتر تفسیر اچھے سے اچھے پیرایہ میں کرے۔وہ یہ بہتر بتاسکتاہے کہ سرمایہ دار نظام کیسے رائج ہوتاہے۔وہ یہ بخوبی اظہار کرتاہے کہ فلاں کیمیاکے استعمال سے کیسے مہلک امراض پیداہوں گے۔لیکن اس کی ذمہ داری اسی اعلان کے ساتھ ختم ہوجائے گی۔
اب اس کا فرض یہ نہیں ہے کہ انسان کا ہاتھ پکڑکراسے کیمیاکے استعمال سے روک دے توسوال یہ پیداہوگا کہ پھر وہ کون سی طاقت ہے جو ایسے سرمایہ دار نظام کو توڑدے یا انسان کو اس کیمیاسے پرہیز کرنے کے طریقے سکھائے۔
کیمیاکے بارے میں تویہ کہابھی جاسکتاہے کہ انسان اپنی ذات سے محبت کی بناپر ذاتی طورپر اس سے اجتناب کرے گا اور اپنی نجات کے اسباب مہیا کرے گا لیکن سرمایہ
داری کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاسکتی اس لئے کہ علم اس کی برائی کا اظہار کرکے الگ ہو چکا ہے۔اب ایسے محرکات کی ضرورت ہے جو اس کی مخالفت پر آمادہ کریں۔ظاہر ہے کہ وہ انسان کانفس نہیں ہوسکتااس لئے کہ بسااوقات سرمایہ دارانہ اندازہی نفسانی مفاد کے موافق ہوتاہے۔ایسی حالت میں نفس کی طرف سے اس کی مخالفت کی توقع بالکل غلط اور بے جا ہے۔ لہٰذا ایک ایسے محرک کی تلاش ضروری ہے جو اس مقصد کو حاصل کراسکے۔یہ بات نہ نفس انسانی کے بس کی ہے اور نہ علم طبیعیہ کے۔
مادیت تاریخ اور مشکل
مارکسیت کا خیال ہے کہ اس مشکل کو تاریخی مادیت کے حوالے کردیاجائے وہ خودہی ایک دن اس کا کوئی معقول حل تلاش کرلے گی، اس لئے کہ اس مشکل کی بنیاد صرف یہ ہے کہ انفرادی مصالح بسااوقات اجتماعی مصالح سے متصادم ہوجاتے ہیں اور ایسے وقت میں نفس پر ست انسان اپنے ذاتی مفادکو مقدم کردیتے ہیں اور اس طرح اجتماعی مفاد کا خون ہوجاتاہے۔
لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی جدید مشکل نہیں ہے بلکہ یہ صورت ابتدائے تاریخ سے چلی آرہی ہے ہر دورمیں انفرادیت پرست افراد نے معاشرہ سے بغاوت کرکے طبقاتی نظام قائم کیاہے اور پھر ذرائع پیداوار سے ملکیت کی بناپر میدان اقتصاد کے فاتح بھی قرار دپائے ہیں اور آخر کار تاریخ نے وہ منظر بھی پیش کر دیاہے جب ان کی انفرادیت کا جنازہ نکل گیا، ایک غیر طبقاتی نظام قائم ہو گیا اور ہر شخص اجتماعی مفاد پر جان دینے لگا۔
ہم نے اس مادیت کا تجزیہ کرتے وقت ہی ظاہر کردیاتھا کہ اس قسم کے الہام کی کوئی بظاہر دلیل نہیں ہے اور نہ اس کو اس اہم مسئلہ کا حل قرار دیاجاسکتاہے۔مسئلہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے اور معاشرہ پر خواہشات کی حکومت قائم ہے۔اب کامیابی اس کے ہاتھوں ہے جو اپنے خواہشات کے مطابق درآمد کرسکے اور جو شخص اپنے دست وبازو میں طاقت نہیں رکھتا اس کی قسمت میں بڑے طبقہ کی زیردستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
فطرت تڑپ رہی ہے کہ ایک قانون بن جائے جو انسانیت کے اجتماعی مفاد کا تحفظ کرے اور پھر اسی قانون کی حکومت ہو۔
ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ خیال کرے کہ قانون کو نافذ کرنے کے لئے حکومت کافی ہے لہٰذا مسئلہ کو اقتدار اعلیٰ کے حوالے کردینا چاہئے۔لیکن میراکہنا یہ ہے کہ یہ خیال بالکل ہی مہمل ہے اس لئے کہ حکومت کے افراد خودبھی سماج کے باہر سے نہیں آتے ہیں بلکہ وہ بھی اسی سماج کی پیداوار ہوتے ہیں۔انہیں بھی اپنے نفس سے محبت ہوتی ہے ان کے بھی ذاتی مصالح ہوتے ہیں۔ان حالات میں اس بات کی ذمہ داری نہیں لی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے انفرادی مفاد سے قطع نظرصرف اجتماعی مصالح کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔
توکیا انسانیت کے مقدرمیں یہی لکھاہے کہ وہ اس قسم کے مشکلات کا شکاررہے اور اپنی بدبختی پرنوحہ پڑھتی رہے؟کیاوہ کائنات جسے ارتقاء وتکامل کے صلاحیات اور کمال کے جذبات سے نوازاگیاہے انسان اس سے الگ کوئی مخلوق ہے۔
یہی وہ بھیانک منظرہے جہاں دین کا حسین چہرہ چمکتاہوانظرآتاہے اور وہ اعلان کرتاہے کہ اس نازک مسئلہ کے لئے اگرکوئی داقعی حل ہوسکتاہے تو وہ مذہب ہے۔
مذہب ہی وہ روحانی طاقت ہے جو انسان سے انفرادی مفاد کو ترک کراسکتی ہے اس لئے کہ اس کی نظرمیں اس سے بلند فائدے بھی ہوتے ہیں۔
یہی وہ قوت ہے جو انسان سے اس کے وجود کو بھی قربان کراسکتی ہے صرف اس
تصور میں کہ اس کے بعدایک جاودانی زندگی ہاتھ آئے گی۔
یہی وہ زاویۂ نظرہے جو اپنے مفاد کے مقابل دیگر مصالح کا احساس پیداکرسکتا ہے۔
یہی وہ طرز فکر ہے جہاں ہر نقصان فائدہ اور ہر زحمت لذت معلوم ہوتی ہے۔ دوسروں کا خسارہ اپنا خسارہ اور دوسروں کا فائدہ اپنا ذاتی مفاد معلوم ہوتاہے۔انفرادی واجتماعی مصالح کا تفرقہ ختم ہوجاتاہے اور انسان آفاق عالم میں سیر کرتاہوانظرآتاہے۔
قرآن کریم نے فائدہ ونقصان اور حیات وموت کے اسی جدید مفہوم کی وسعت اور ہمہ گیری کے اعلان کے لئے حسب ذیل بیانات دیئے ہیں:
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾
جو مردوعورت باایمان رہ کر عمل صالح کرے گا اس کا مقام جنت ہوگا وہ اپنی منزل اعلیٰ میں بلاحساب داخل ہوگا۔ (غافر/40)
مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ﴿٤٦﴾
جو شخص اچھا کرے گا وہ اپنے لئے اور جو براکرے گا وہ بھی اپنے نفس کے اوپر۔ (فصلت46)
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾
قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کا انجام دیکھنے کے لئے قبروںسے نکالے جائیں گے اگر ذرہ برابر خیر کیاہے تو وہ بھی دیکھیں گے اور اگر بقدر ذرہ برائی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ (زلزلہ6تا8)
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾
راہ خدا کے شہیداء کو مردہ نہ خیال کرو،یہ زندہ ہیں اوراپنے پروردگار
کے پاس رزق پارہے ہیں۔ (آل عمران169)
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّـهِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾
مدینہ اور اس کے اطراف والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول(ص) سے الگ ہوجائیں اور اپنے نفس کو ان کے نفس پر مقدم کردیں اس لئے کہ راہ خدا میں انہیں بھوک،پیاس وغیرہ جو تکلیف بھی ہوتی ہے وہ دشمنوں کے لئے جو قدم بھی اٹھاتے ہیں اور ان سے جواذیت بھی اٹھاتے ہیں سب کے عوض میں انہیں عمل صالح کا اجر ملتاہے اس لئے کہ اللہ حسن عمل والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔یہ لوگ راہ خدا میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں یا جس قدر مسافت بھی طے کرتے ہیںیہ سب لکھ لیاجاتاہے تاکہ انہیںبہترسے بہتربدلہ دیاجاسکے۔ (توبہ20،21)
یہ وہ حسین نقشہ ہے جس میں ذاتی اغراض اور خیرکے راستوں کو متحد بناکے پیش کیا گیاہے تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے ذاتی اور اجتماعی مفاد میں یگانگت اور یک رنگی پائی جاتی ہے۔
دین ہی وہ واحد طاقت ہے جو اس مشکل مسئلہ کو حل کر سکتی ہے اس انداز سے کہ ذاتی مصالح کے عوامل ومحرکات بھی اجتماعی مصالح کے محرک بن جائیں۔
یہی انسان کی وہ فطری ضرورت ہے جو فطرت ہی سے پیداہونے والے مشکلات کو حل کرتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جب قدرت نے انسان کو تحصیل کمال کے جذبات دیئے ہیں
اور اسے ارتقاء وتکامل کی راہیں دکھائی ہیں تو اس کا فرض تھاکہ اس کی فطرت سے پیداہونے والے مشکلات کا حل اسی فطرت میں ودیعت کرتی۔چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور فطرت میں ایسی دورنگی پیداکر دی کہ وہ ایک طرف ذاتی اغراض کو ابھارکر اجتماعی مشکل پیداکرتی ہے اور دوسری طرف انسان کو دین کے سانچے میں ڈھال کر اس عظیم مشکل کا حل بھی پیش کرتی ہے۔
وہ اگر مشکل کو ابھارکر خاموش ہوجائے تو انسان تاقیامت اس سے نجات نہ پا سکے اور ہمیشہ اسی مصیبت میں گرفتار رہے اس لئے مشکل کو ابھارنے کے ساتھ ہی فوراً اس کے حل کی طرف بھی متوجہ کردیتی ہے۔
قرآن کریم نے اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیاہے:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
اپنا رخ دین حنیف کی طرف رکھو،یہی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر لوگوں کو خلق کیاہے اور اس کی خلقت قابل تبدیلی نہیں ہے۔یہی محکم دین ہے لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ (روم30)
اس آیۂ کریمہ سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے:
(1) دین ایک فطری شے ہے جسے لے کر انسان دنیا میں آتاہے اور اس خلقت میں کسی طرح کا تغیر غیر ممکن ہے۔
(2) انسان کو جس دین پر پیداکیاگیاہے وہ دین حنیف یعنی خالص توحید کا دین ہے۔ یہی اپنے واقعی فرائض کو ادا کرسکتاہے اور یہی انسان کو اجتماعی تنظیم اور عملی معیار پر متحد بناسکتاہے۔اس کے علاوہ ادیان شرک یعنی متفرق خداؤں کے دین اس مشکل کو حل
کرنے سے قاصر ہیں کہ ان کا وجود ہی اس مشکل کا نتیجہ ہوتاہے۔جیساکہ جناب یوسف ـنے فرمایا تھا:
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّـهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ
تم لوگ تو صرف ان ناموں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے مل کر مقرر کرلیاہے اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔ (یوسف40)
مطلب یہ ہے کہ یہ خود نفسیاتی محرکات کی پیداوار ہیں جنہوں نے انسان کو اپنے انفرادی مصالح کے لئے ان ادیان شرک کا درس پڑھایاہے تاکہ وہ اس طبیعی رجحان کا مقابلہ کریں جو انسان کو دین حنیف کی طرف کھینچ رہاہو۔
(3) وہ دین حنیف جس پر عالم بشریت کی تخلیق ہوئی ہے اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ محکم دین ہے اور انسانیت کو اپنے سانچہ میں ڈھال سکتاہے اس لئے کہ جو دین انسان کی صحیح قیادت نہ کر سکے وہ اس اجتماعی مشکل کو حل کرنے سے قاصر ہے۔
ہمارے ان بیانات سے دین وحیات کے بارے میں اسلام کے مختلف نظریات سامنے آجاتے ہیں:
(1) انسانی زندگی کی بنیادی مشکل خود اس کی فطرت سے پیداہوتی ہے جو نفس پرستی اور خودپسندی کا جذبہ لے کر دنیامیں آئی ہے اور پھر اس مشکل کا علاج بھی اسی فطرت سے ہوتاہے اور یہ علاج صرف دین حنیف ہے جو انسان کے ذاتی اور اجتماعی مفاد میں مطابقت پیداکراسکتاہے
(2) اجتماعی زندگی کو ایک محکم دین کی ضرورت ہے
(3) زندگی کے مختلف شعبوں کی اجتماعی تنظیم دین کے زیر سایہ ہونی چاہئے۔یہی اس کے
جملہ امراض کا معالج اور تمام مشکلات کا واحد حل ہے
اسلام کا اقتصادی نظام اجتماعی تنظیم کا ایک جزء ہونے کی حیثیت سے دین کے ضمن میں زیر بحث آناچاہئے۔وہی اس کی بنیاد اور اس کے قوانین کا سرچشمہ ہے۔اقتصاد کا دین سے الگ کرلینا اس کے واقعی رنگ کو تباہ کردینا اور اسے اس کی واقعی منزل سے معزول کر دیناہے۔
اسلامی اقتصادکوئی علم نہیں ہے
کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر اقتصادی تنظیم کسی مکمل نظام کا ایک جزء ہوتی ہے۔جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہوتاہے۔مثال کے طورپر اسلامی اقتصاد مذہب اسلام کا ایک شعبہ ہے ،سرمایہ دار اقتصاد،ڈیموکریسی سرمایہ داری کا ایک جز ہے۔اشتراکی تنظیم مارکسی نظام کا ایک پہلو ہے اور یہ تمام مذاہب اور نظام اپنے بنیادی اصولوں میں شدید اختلاف رکھتے ہیں اور انہیں اصولوں کی بنیاد پر ان کا ٹائٹل قائم ہوتاہے۔
مارکسی اقتصاد اپنے لئے علمی رنگ اختیار کرتاہے اس لئے کہ وہ اشتراکیت کو علمی اور تاریخی قوانین کا حتمی نتیجہ قرار دیتاہے۔
سرمایہ دار اقتصاد اپنے کو تاریخ سے الگ کرکے چند مخصوص افکار واقدار کا نمونہ قرار دیتاہے۔
اور اسلام ان دونوں سے الگ ایک راستہ اختیار کرتاہے۔وہ نہ تو اپنے کو تاریخ کا حتمی نتیجہ قرار دیتاہے اور نہ حیات وکائنات کے مفاہیم سے الگ قدروں کا قائل ہے۔ وہ
اپنے اقتصادی نظام کو اسی مذہب کا ایک جز سمجھتاہے جس کی بنیاددینی عقائد پر ہے اس کے علمی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی اقتصادیات کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ایک عقائدی تنظیم کا شعبہ ہے جس کے تمام شعبے ایک مرکز پر جمع ہوجاتے ہیںاور ان کے مجموعہ کانام دین ہوتاہے۔
دین ایک انقلابی تحریک ہے جو فاسد عناصر کو ختم کرکے صالح معاشرہ کی تشکیل کرتاہے اس کا کام عمل ہوتاہے۔
وہ معاشرہ کے حوادث وقائع کی فنی توجیہیں نہیں کرتااور نہ اسے اس فکری تگ ودو سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔
وہ انفرادی ملکیت کو تاریخ کے کسی دور کا حتمی نتیجہ نہیں سمجھتابلکہ انسانیت کے حق میں صالح اور مناسب خیال کرکے اس کی ایجاد کے اسباب فراہم کرتاہے اور اس اعتبار سے کسی حد تک سرمایہ دار نظام سے مشابہت رکھتاہے اس لئے کہ وہاں بھی انقلاب کا کام ہوتاہے تاریخی ضرورت اور حادثاتی تفسیر کا نہیں۔
اسلامی اقتصادیات کے بارے میں عمل کا فریضہ یہ ہے کہ تشریع اسلام کی روشنی میں اقتصادیات کی مکمل تنظیم کو معلوم کرکے ان افکار ومفاہیم کا اندازہ لگائے جو اس تنظیم کی پشت پر کارفرماہیں اور علم کا فریضہ یہ ہے کہ ان واقعات وحوادث کی تفسیر کرکے ان کے باہمی ربط کو تلاش کرے۔
اس لحاظ سے بھی اسلام کی شکل سیاسی اقتصاد کی سی ہوگی جہاں مذہب کے نشانات معین کرنے کے بعدعلمی قوانین کاا نکشاف کیاجاتاہے۔
ظاہر ہے کہ اسلامی اقتصاد کے لئے یہی ایک بات ممکن ہے کہ اسلامی معاشرہ کے حالات کو دیکھ کر اس لئے ایک علمی قانون بنالیاجائے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام اسلامیات کے سلسلہ میں کب اور کیسے ہوسکتاہے۔
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اقتصادی زندگی کے حالات کی توجیہ وتفسیر کے دو طریقے ہواکرتے ہیں:
(1) کسی ایک معاشرہ پر اس نظام کو منطبق کرکے اس کے تجربات کو جمع کرلیاجائے اور پھر انہیں واقعات کے درمیان سے اس امر کا استنتاج کیاجائے کہ ان کی پشت پرکون سے قوانین کام کررہے تھے۔
(2) چند مسلم قوانین فرض کرلئے جائیں اور پھر انہیں کی روشنی میں ان پر مرتب ہونے والے نتائج کا اندازہ کیاجائے تاکہ اس طرح ایک مکمل علم تشکیل پاسکے۔
پہلی صور ت حال سرمایہ داری کے لئے توممکن ہے کہ وہ نظام عالم پر منطبق بھی ہوئی ہے اور اس کے تجربات بھی حاصل ہوئے ہیں۔لیکن اسلام کے لئے یہ بات غیر ممکن ہے۔
اس لئے کہ اس کا رواج دنیاکے کسی گوشے میں نہیں ہے۔اس کے قوانین واصول کہیں بھی حکومت نہیں کرتے۔معاشرہ کے حالات سے اس کے علمی قوانین کا تجزیہ کرنا غیر ممکن ہے۔
البتہ دوسری صورت ممکن ہے اس لئے کہ اس میں کسی ایسے خارجی تجربہ کی ضرورت نہیں ہے جس سے اسلام کو محروم فرض کیاجائے بلکہ صرف چند مفروضات کی ضرورت ہے اور انہیں کی روشنی میں تاریخی حوادث کی تفسیر کرنی ہے۔
اس بنیاد پر یہ ممکن ہے کہ مسلمان نقاد اس بات کا دعویٰ کردے کہ اسلامی نظام میں اہل تجارت اوربینک والوں کے مصالح میں وافقت ومطابقت ہوگی اس لئے کہ اسلام میں بینک سودخوری کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتابلکہ اس کی بنیاد مضاربہ پرہوتی ہے اور مضاربہ میں منافع کی تقسیم دونوں کے درمیان فیصدی نسبت سے ہوتی ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہوتی۔
ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں دونوں کے مصالح میں کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا اسلامی نظام کے انطباق سے پہلے اس بات کا اندازہ صرف اس امر سے ہوگیاکہ اسلام نے سود کو حرام قرار دیاہے جس طرح کہ اسی ایک قانون سے یہ بھی معلوم ہوگیاکہ اسلامی معاشرہ میں وہ مصائب ومشکلات بھی نہ پیداہوں گے جن میں سرمایہ داری مبتلا ہوئی ہے۔اس لئے کہ سودی نظام میں ہر شخص دولت جمع کرنے کی فکر کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سود حاصل کرسکے۔اس طرح نہ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور نہ مال ہی تقسیم ہوسکے گا۔معاشرہ ایک کساد بازاری کا شکار ہوجائے گا۔لیکن اگر سود کو حرام کرکے ذخیرہ اندوزی کو بھی حرام کردیاجائے اور اس پر کوئی ٹیکس لگادیاجائے تو اس کا لازمی اثریہ ہوگاکہ لوگ دولت کو صرف کریں گے اور ان تمام مشکلات سے نجات مل جائے گی جو سرمایہ داری کے زیر اثر پیداہوتے ہیں۔
ان طریقوں سے یہ بات توممکن ہے کہ اسلام کے لئے ایک معاشرہ فرض کرکے اس کے قوانین کے نتائج معلوم کرلئے جائیں لیکن ظاہر ہے کہ اسے علمی استنتاج نہیں کہاجاسکتاہے اس لئے کہ فرضی معاشرہ واقعی سماج سے مختلف ہواکرتاہے جیساکہ سرمایہ داروں نے دیکھاہے کہ انہوں نے اپنی تنظیم کے لئے جو نتائج فرض کئے تھے انطباق کے وقت وہ سب بدل گئے اور اس کے برعکس نتائج برآمد ہوئے۔
دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسلامی معاشرہ کا روحانی مزاج بھی اقتصادی حالات پر بڑی حدتک اثرانداز ہوتاہے اور چونکہ اس مزاج کا کوئی درجہ معین نہیں ہے اس لئے اس کے نتائج بھی حتمی نہیں ہوسکتے۔
مقصد یہ ہے کہ اسلام کا علم الاقتصاداس وقت تک مرتب نہیں ہوسکتاجب تک کہ اس نظام کو کسی ایک معاشرہ پر منطبق کرکے اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لئے جائیں۔
(5)تقسیم پیداوار سے الگ شکل میں
انسان اپنی اقتصادی زندگی میں دوقسم کے اعمال انجام دیتاہے ایک پیداوار اور ایک تقسیم،وہ ایک طرف اپنے معلومات بھرذرائع پیداوار سے مسلح ہوکر عالم طبیعت کا مقابلہ کرتاہے اور اس سے طبیعی نعمتیں حاصل کرتاہے اور دوسری طرف باہمی تعلقات قائم کرکے مختلف شئون زندگی کے لحاظ سے انسانی روابط کی تحدید کرتاہے،انہیں باہمی تعلقات کا نام اجتماعی نظام ہے جس میں ہرقسم کے اجتماعی تعلقات مع تقسیم ثروت کے داخل ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان پیداوار کے مسئلہ میں عالم طبیعت سے منافع حاصل کرتے ہیں اور نظام اجتماع کے اعتبار سے ان منافع کو اپنے اجتماعی تعلقات کی بنیاد پر تقسیم کر لیتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ پیداوار کا کام علمی ترقیوں کے ساتھ روبہ ارتقاء ہے۔ایک زمانہ تھا جب انسان بیلچے سے کام لیاکرتاتھا اور ایک زمانہ ہے کہ جب ایٹم کی طاقت سے کام لیا جارہاہے لیکن یادرکھئے کہ اجتماعی نظام کے باہمی تعلقات بھی جامدوساکت نہیں ہیں بلکہ ان میں بھی حالات اور ادوار کے اعتبار سے تغیر ہوتاچلا جارہاہے کل کے تعلقات اور تھے اور آج کے تعلقات اور ہیں۔یہ ضرور ہے کہ اس مقام پر ایک سوال یہ پیداہوجاتاہے کہ ان دونوں قسم کے تغیرات میں کوئی بنیادی رابطہ ہے یا نہیں؟
اور یہی وہ عمیق مسئلہ ہے جہاں آکر اسلام اور مارکسیت کی راہیں بدل جاتی ہے۔ مارکسیت اپنے بنیادی اصولوں کی بنا پر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ذرائع پیداوار کے ساتھ اجتماعی تعلقات اور طریقۂ تقسیم کا بدل جانا ضروری اور قہری ہے۔یہ غیر ممکن ہے کہ ذرائع پیداوار ترقی کر جائیں اور اجتماعی نظام اپنی حالت پر باقی رہے۔
ایک اجتماعی نظام تاریخ کے مختلف ادوار میں کارآمد نہیں ہوسکتااور نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جاسکتاہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ پیداوار کی شکلیں تیزی کے ساتھ بدلتی جارہی ہیں یہاں تک کہ اب ایٹم والیکٹرک تک نوبت پہنچ چکی ہے۔لہٰذا آج کے نظام کو دستکاری کے نظام سے الگ ہونا چاہئے۔آج کا دستور کل کے دستور سے جداگانہ حیثیت کا حامل ہونا چاہئے اور یہی وجہ تھی کہ مارکسیت نے اشتراکیت کو تاریخ کے اس دور کا حتمی نظام قرار دیاہے۔
ظاہر ہے کہ اسلام حتمی اتحاد کو تسلیم نہیں کرسکتا۔وہ اپنے ایک نظام کو مختلف ادوار تاریخ پر منطبق کرناچاہتاہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ پیداوار اور تقسیم دو مختلف میدان ہیں۔ ایک میں انسان کا مقابلہ طبیعی مواد سے ہوتاہے اور وہ ان سے استفادہ کرتاہے اور دوسرے کاتعلق دیگر افراد نوع سے ہوتاہے اوروہ ان سے اتصال وارتباط قائم کرتاہے۔
پہلی قسم کا نتیجہ پیداوار کی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتاہے اور دوسری قسم کا اثرنظام زندگی کی مختلف صورتوں میں۔
تاریخ نے دونوں قسموں کی ترقی کا تذکرہ کیاہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان ایک حتمی اور یقینی رشتہ تسلیم کر لیاہے۔ اس لئے کہ اسلام اپنے اجتماعی نظام کو ایٹم کے دور میں اسی طرح صالح خیال کرتاہے جس طرح وہ دستکاری کے دور میں تھا۔
اسلام اور مارکسیت کے اس اختلاف کی برگشت ایک دوسرے نقطہ کی طرف ہے اور وہ ہے اجتماعی نظام کی تحدید وتعریف، مارکسیت کے نزدیک اجتماعی زندگی ذرائع پیداوار کی پیداکردہ ہوتی ہے۔لہٰذا ان کے تغیر کے ساتھ اس کا متغیر ہوجانا ضروری ہے۔ذرائع پیداوار تاریخ کے محرک اور قافلہ بشریت کے قائدہیں۔ان کے چشم وابرو کے اشاروں پہ اجتماعی نظام کا گردش کرنا ایک ضروری اور لازمی امر ہے۔جس کا مکمل تجزیہ تاریخی مادیت کی بحث میں ہوچکا ہے اور حتمی اتصال واتحاد کے تاروپود بکھیرے جا چکے ہیں لہٰذا اب دوبارہ
بحث کرنا غیر ضروری ہے۔
اسلام کی نظرمیں اجتماعی زندگی پیداوار کی تابع نہیں ہے بلکہ ذرائع پیداوار خود بھی انسانی ضروریات کے تابع ہیں۔اس کے نزدیک تاریخ کا محرک اقتصادنہیں بلکہ انسان ہے۔وہی اپنی ضروریات کے مطابق تاریخ کو حرکت دیتاہے اور وہی اس قافلہ کی قیادت کرتاہے۔
اس کی فطرت میں اپنی ذات سے محبت داخل ہے۔وہ اس محبت کی خاطر ہر شیء کو اپنا خادم بناکر اس سے استفادہ کرنا چاہتاہے۔ہر شخص دوسرے شخص سے اپنا کام نکالنا چاہتاہے وہ اپنے اندر اتنی سکت محسوس نہیں کرتاکہ اپنے جملہ ضروریات تنہافراہم کرسکے اور یہی ضرورتیں وہ ہوتی ہیں جن سے اجتماعی تعلقات پیداہوتے ہیں اور پھر انہیں کے ساتھ ترقی بھی کرتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی زندگی ضرورتوں کی تابع ہے اور صالح نظام وہی ہے جو زندگی کو ضرورت کے مطابق منظم کر سکے۔
جب ہم انسانی ضروریات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ نظرآتاہے کہ اس کے بعض ضروریات ہر دور کے اعتبار سے ثابت وجامد ہیں اور بعض ضروریات ادوارکے اختلاف کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔
انسان کی جسمانی ترکیب،اس کا نظام ہضم وتولید، اس کا قانون احساس وادراک ایسا مشترک امر ہے جو ہردور میں انسانی ضروریات میں اتحاد کا خواہاں رہاہے اور یہی وہ عمومی ضرورتیں ہیں جن کی بناپر تمام انسان ایک امت شمار کئے جاتے ہیں۔جیساکہ قرآن کریم کاا علان ہے:
إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾
یہ تمہاری امت سب ایک ہی ہے اور میں سب کا ہی رب ہوں۔لہٰذا
میری ہی عبادت کرو۔ (انبیائ92)
اسی کے مقابلہ میں بہت سے ایسے ضروریات بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً انسانی زندگی میں داخل ہوتے جارہے ہیں اور پھر معلومات اور تجربات کے ساتھ بڑھتے بھی جارہے ہیں۔
دوسرے لفظوں میں یوں کہاجائے کہ بنیادی ضروتیں ثابت وجامد ہیں اور خارجی ضرورتیں متغیر ومتطور۔
جب یہ بات واضح ہوچکی ہے کہ اجتماعی نظام ضرورتوں سے تشکیل پاتاہے اور یہ بھی معلوم ہوگیاہے کہ صالح نظام کے لئے تمام اجتماعی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو اب یہ کہاجاسکتاہے کہ اجتماعی نظام نہ ثابت ہوسکتاہے اور نہ متغیر۔اس لئے کہ انسان کی ضرورتیں دونوں قسم کی ہیںاور نظام صالح کے لئے لازم ہے کہ اس کے دوپہلو ہوں۔ایک پہلو ثابت ہو جولازمی اور بنیادی ضروریات کا علاج کرے اور ایک پہلو متغیر ہوجو روز افزوں نوزائیدہ مشکلات کو حل کرے۔
اسلام نے اسی طریقۂ تنظیم کو اختیار کیاہے اس نے ایک طرف اپنے قانون کو ثبات کارخ دیاہے اور نبیادی ضرورتوں کے علاج کے لئے تقسیم ثروت،نکاح،طلاق، حدود، قصاص جیسے احکام وضع کئے ہیںاور دوسری طرف تغیر کا پہلو بھی باقی رکھاہے اور اس میں ولی امر کو مصلحت وقت کے مطابق فیصلہ کرنے کا موقع دیاہے۔اس نے مارکسیت کی بنیاد کو ٹھکراکر یہ ثابت کر دیاہے کہ صالح نظام تاریخ کے مختلف ادوار کے لئے کارآمد ہوسکتاہے وہ کسی وقت بھی پیداوار کی زنجیروں میں نہیں جکڑاجاسکتا۔
یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ تاریخ میں تقسیم ثروت کے جتنے بھی طریقے بیان کئے گئے ہیں ان سب کے بارے میں نظریہ مارکسیت سے مختلف ہے۔
مارکسیت صرف ان طریقوں کوپسند کرتی ہے جو ذرائع پیداوار کے مطابق ہوں
اور ہر اس طریقہ کو مسترد کردیتی ہے جو اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائے یا پیچھے رہ جائے۔
اور یہی سبب ہے کہ دستکاری کے دور کے لئے اس نے غلامانہ نظام زندگی کو ممدوح قرار دیاہے اور اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس دور میں اکثریت کے سروں پر تلوار کا علم کرنا، ان کا کوڑوں سے اذیت دینا ضروری ہوگیاتھا اس لئے کہ ذرائع پیداوار اور زیادہ مشقت کے طالب تھے اور لوگ اس کے تحمل کے لئے تیار نہ تھے۔
ایسے وقت میں اس شدت اور ظلم کو ترقی اور اس عمل کے انجام دینے والے کو ''بیدار مغز انقلابی''انسان کہاجائے گااور اس کی مخالفت کرنے والے کو ہر اس لقب سے یادکیاجائے گاجو اشتراکیت کے دورمیں سرمایہ دار کو دیاجاتاہے۔
اسلام اس کے بالکل برعکس نظام زندگی کی صلاحیت کو ذرائع پیداوار سے الگ کرکے ضروریات کے معیار پر رکھتاہے اگر وہ نظام انسانی ضرورتوں کی تکمیل کرسکتاہے تو صالح ومناسب ہے ورنہ فاسد۔پیداوار کی حالت ایک ہی رنگ پر ہویامختلف ہوجائے۔
اسلام اس مارکسی اتحاد کو فقط نظری اعتبار سے باطل نہیں قرار دیتابلکہ اس پر تاریخی شواہد بھی پیش کرتاہے اس نے خود اپنے تجربہ میں وہ کامیابی حاصل کی ہے جو اس کی حقانیت کی دلیل اور مارکسیت کے بطلان پر برہان ہے۔اس نے اپنے وجود سے یہ ثابت کر دیاتھاکہ معاشرہ میں ذرائع پیداوار کے جمودوسکوت کے باوجود اجماعی نظام میں انقلاب لایاجاسکتاہے اور اس کو نئی شکل دی جاسکتی ہے۔
چنانچہ اسلام کا وہ خارجی وجود جس میں وہ ایک مخصوص سماج پر منطبق ہواتھا اور اس نے ایک ایسا انقلاب برپاکردیاتھا جو آج تک تاریخ میں ثبت ہے۔اس نے ایک نئی امت پیداکرکے ایک جدید تمدن کی بنیاد ڈال کرتاریخ کی رفتار بدل دی اور یہ ثابت کردیاکہ ذرائع پیداوار کے اس دور میں اتنا عظیم انقلاب مارکسی فکر کے تصورمیں بھی نہیں آسکتاتھا۔
حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نظام کے اس مختصر دور نے مارکسی منطق کو ہراعتبار سے
چیلنج دے دیاتھا۔
مساوات کے بارے میں مارکسیت کا خیال تھاکہ یہ اس وقت تک نہیں پیداہو سکتی جب تک بورژوائی طبقہ نہ پیداہوجائے اور یہ اس وقت ہوگا جب صنعتی نظام بر سرکار آجائے گا لیکن اسلام نے اپنے موقف میں اس فکر کو ہنسی میں اڑادیا۔اس نے علم مساوات بلند کیا، انسان میں صحیح شعور وادراک پیدا کیا،ا جتماعی تعلقات کو مساوات کے سانچہ میں ڈھالا اور یہ سب اس وقت کیاجب بورژوایت کو خطۂ ارض پر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہ ملی تھی اور اس کی پیدائش کو ہزار سال باقی تھے۔اسلام کا کھلاہوا اعلان تھا:
تم سب آدم سے ہواور آدم مٹی سے ہیں۔
لوگ کنگھی کے دندانوں کے مثل برابر ہیں۔
عرب کو عجم پر تقویٰ کے علاوہ کسی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔
کیا اسلام نے یہ خیالات ان بورژوائی ذرائع پیداوار سے حاصل کئے تھے جو ایک ہزار سال بعد پیداہونے والے تھے۔ یہ سب ان ابتدائی ذرائع معیشت کے دور میں ہورہاتھا جس سے حجازی معاشرہ گزررہاتھا۔
اس وقت توعرب تمام عالم سے بدتر حالت میں تھے پھر اس مساوات کی بنیاد حجاز کے پسماندہ خطہ میں کیوں رکھی گئی۔اس فکر کی ابتداء یمن، حیرہ اور شام کے ترقی یافتہ معاشروں سے کیوں نہیں ہوئی۔
اس کے بعد اسلام نے تاریخی مادیت کو چیلنج کیااور یہ بتایاکہ ایک عالمی نظام پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرسکتاہے اور اس نے اس فکر کے لئے بھی ایک ایسے خطہ کو اختیار کیاجہاں قبائلی جنگوں کی بھرمارتھی اور ایک قوی حکومت کا بھی تصورنہ تھا لیکن اس نے سب کو انسانیت عظمیٰ کی منزلت پرلاکر متحد کر دیا اور مسلمانوں کو اس قبائلی فکر سے بلند وبالا کر دیا۔جس کی بنیاد خون،قرابت،ہمسائیگی وغیرہ پر تھی۔اس نے انسان کو وہاں پہنچادیاجہاں
ان عناصر کا وجود بھی نہ تھا۔بلکہ اسلام کے فکری قوانین کی حکومت تھی۔
اب آپ بتائیں کہ جس قوم میں قوی اجتماع کی بھی صلاحیت نہ تھی اسے عالمی اجتماع کی امامت کن ذرائع پیداوار نے سپرد کی تھی؟
اسلام نے اس کے بعد تاریخی منطق کو چیلنج کیا او رتقسیم ثروت کے وہ اصول وضع کئے جو مارکسیت کی نظرمیں ایک عظیم صنعتی انقلاب کے بغیر ناممکن تھے۔اس نے انفرادی ملکیت کی تحدید کرکے اس کے مفہوم کو پاکیزہ بنایا۔اس کے حدود قائم کرکے فقراء ومساکین کی کفالت کا انتظام کیا۔
اجتماعی عدالت وتوازن کی ذمہ داریاں وضع کیں اور یہ سب اس دور میں کیاجب مادی شرائط کے وجود کے آثار دور دور تک نظر نہ آتے تھے اور اٹھارہویں صدی میں یہ کہا جارہاتھاکہ :
سوائے احمقوں کے ہر شخص جانتاہے کہ پست طبقہ کو فقیر رہنا چاہئے تاکہ عمل میں زحمت ومحنت کریں۔ (ارثریونج کاتب قرن ہیچدہم)
انیسویں صدی کا یہ قول تھاکہ:
جو شخص ایسے عالم میں پیدا ہوجہاں ملکیت طے ہوچکی ہواسے وسائل معیشت کے نہ ہونے کی صورت میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔وہ سماج میں ایک طفیلی کی حیثیت رکھتاہے جس کا وجود بالکل غیر ضروری ہے اس لئے کہ عالم طبیعت کے دسترخوان پر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔طبیعت اسے بھگانا چاہتی ہے اور اس کے حکم میں سستی مناسب نہیں ہے۔
(ماتس کاتب قرن نوزدہم، ولادت 1766ء ،وفات 1834ء :مترجم)
آج عالم صدیوں کے بعد اس ضمانت کی فکر کررہاہے جس کا اعلان اسلام نے برسہابرس پہلے کردیاتھا:
جو شخص اپنے لاوارث بچے چھوڑدے گا میں اس کا ذمہ دارہوں،جو شخص
مقروض مرے گامیں اس کا ضامن ہوں۔
اسلام واضح لفظوں میںا س بات کا اعلان کرتاہے کہ فقروفاقہ عالم طبیعت کے بخل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ غلط طریقۂ تقسیم اور صالح نظام سے انحراف کا نتیجہ ہے۔جہاں فقیر کو غنی سے الگ کر دیا گیا ہے اس کا قول ہے کہ:
کوئی شخص اس وقت تک بھوکا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پہلو میں کوئی آسائش پسند نہ ہو۔
ظاہر ہے کہ اجتماعی عدالت کے بارے میں اسلام کے یہ ترقی پسند اور بلند پایہ افکار اور اس دور کے بیلچہ وکدال،کاریگری اور دستکاری کا نتیجہ نہیں ہوسکتے۔
کہایہ جاتاہے کہ یہ بلند فکر، یہ اجتماعی انقلاب اور یہ جاذبیت سب کے سب مکہ کی اس بڑھتی ہوئی تجارت کا نتیجہ ہیں جو ایک بڑی حکومت کے متقاضی تھے۔ایک ایسی حکومت جس کے اجتماعی احکام اس ترقی یافتہ تجارت کے لئے سازگار ہوں۔
کیاخوب! پوری انسانی زندگی کا وبالا ہوجانا اس ایک تجارت کا نتیجہ ہے جو جزیرۂ عرب کے شہروں میں سے ایک معمولی شہر میں ترقی کر رہی تھی ۔میں نہیں سمجھ سکتاکہ فقط مکہ کہ تجارت نے اتنا زور کیسے دکھایاکہ دیگر عرب وغیرعرب ترقی یافتہ متمدن شہر اس کے پیچھے رہ گئے۔آخر ترقی پسند مہذب ممالک کہاں سورہے تھے؟
کیا جدلیاتی منطق کا تقاضہ یہ نہ تھا کہ یہ انقلاب ایسے ہی کسی بڑے ترقی یافتہ شہر سے اٹھے؟
پھر اس انقلاب کے جراثیم مکہ میں کیسے بڑھے جوان تمام شہروں سے زیادہ پست اور فلاکت زدہ تھا؟
اگر مکہ کے تجارتی حالات فقط شام ویمن کے سفر کی بناپر خوشگوار تھے تو نبیطوں کے حالات تواور بھی بہتر رہے ہوں گے اس لئے کہ انہوں نے بطر(بحیرۂ لوط اور بحر احمر کے
درمیان نبیطوں کی مملکت کا پایۂ تخت عرب اس کو ملع کہتے ہیں۔مترجم) کو تجارتی اڈہ قرار دے کر وہاں ایسی شہریت قائم کردی تھی جس کی اس وقت میں نظیر بھی نہ تھی۔ان کا نفوذہمسایہ ممالک تک پہنچ چکا تھا۔انہوں نے وہاں تجارتی قافلوں کے لئے حامیات قائم کرکے کانوں پر قبضہ کرنے کے اڈے جمادیئے تھے۔چنانچہ یہ شہریت ایک عرصۂ درازتک برقرار رہی اور تجارت روز افزوں ترقی کرتی رہی،یہاں تک کہ اس کے آثار سلوقیہ، شام اور اسکندریہ میں بھی پائے جانے لگے،یہ لوگ تجارتی سلسلے میں یمن سے افادیہ(ایک خوشبوکانام ہے۔مترجم)،چین سے ریشم، عقلان سے حنا،صیدادصور سے شیشہ رنگ، خلیج فارس سے موتی، روم سے خرف وغیرہ خریدتے تھے اور اپنے یہاں سوناچاندی، تارکول،تل وتیل وغیرہ پیداکرتے تھے، تعجب یہ ہے کہ ان تمام مساوی ترقیوں کے باوجود ان کا اجتماعی نظام اپنی حالت پر باقی تھا اوررِحْلَةَ الشِّتَائِ وَالصَّیْفِ پر گذر کرنے والی قوم انقلاب سے کھیل رہی تھی۔
اس کے علاوہ مناذرہ(حیرہ کے بادشوہوں کا لقب ہے۔مترجم) کے عہد میں حیرہ( کوفہ کے قریب ایک مقام ہے جہاں عہدقدیم کے آثارخود مترجم نے مشاہدہ کئے ہیں۔مترجم) کی بے پناہ ترقی جہاں لباس ،اسلحہ، خرف اور مٹی کے برتنوں کا زوروشور تھا اور ان کا تجارتی نفوذ جنوب وغرب جزیرہ عرب تک پہنچ چکا تھا۔ان کے قافلے ہر بازار میں کلی سامان لئے حاضر رہتے تھے۔اس طرح تدمر(دمشق کے شمال مشرق میں ایک شہر تھا جس کانام PALMYRE ۔مترجم) کی ترقی جو صدیوں قائم رہی جس میں تجارت عالمی پیمانہ پر ہوتی رہی۔چین،ہند،بابل، فینقیہ (ساحل لبنان کے قدیم شہروں کا نام ہے PHENICIE ۔مترجم) اور جزیرہ کے ممالک سے تجارت ہوتی رہی۔خودیمن کی شہرت تاریخ کاایک اہم واقعہ ہے۔کیا ان تمام حالات میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ کسی انقلاب سے آشنا ہوتے؟یہ بات صرف مکہ کے لئے رہ گئی تھی کہ اس کی تجارت بابرکت ثابت ہوتی اور اسلام انقلاب عظیم
برپاکردیتا۔
حقیقت یہ ہے کہ ان گوناگوں حالات کے بعداسلام کو یہ حق پہنچتاہے کہ وہ پورے وثوق واطمینان کے ساتھ تاریخی مادیت کے حتمی فیصلوں کا انکار کرے اور یہ اعلان کر دے کہ اجتماعی تعلقات کو پیداوار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔دونوں کی رفتارجداگانہ اور دونوں کاراستہ الگ الگ۔لہٰذا یہ قطعی طورپرممکن ہے کہ پیداوار سے جداگانہ سلوب سے ثروت کو تقسیم کیاجائے اور اس طرح سے کوئی غلط نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔
(6)اقتصادی مشکلات اور ان کا حل
مسئلہ کیاہے؟
اقتصادیات کے بارے میں دنیا کے جملہ نظریات اس بات پرمتفق ہیں کہ معاشی زندگی میں بعض اہم مسائل ومشاکل پیش آتے ہیں اوران کا علاج بھی ممکن ہے لیکن اختلاف اس نقطہ پر ہے کہ یہ مشکلات کیاہیں؟اور کیوں؟
سرمایہ داروں کا عقیدہ ہے کہ یہ مشکل طبیعی مواد کی قلت کی بناپر پیداہوتی ہے عالم کی روزافزوں آبادی کے لئے زمین کا یہ محدود رقبہ اور خام مواد کی یہ قلیل مقدار کافی نہیں ہے۔لہٰذااس قلت کی بناپر عالم اقتصادکو ایک اہم مشکل سے دوچارہونا پڑتاہے۔
مارکسیت کا خیال یہ ہے کہ یہ مشکل پیداوار اور تقسم کے اختلاف کی بناپر پیداہوتی ہے۔لہٰذا اگردونوں میں اتفاق واتحاد قائم کردیاجائے تو عالم میں سکون واطمینان پیداہو جائے گا۔
اسلام ان دونوں نظریات کا مخالف ہے۔وہ عالم طبیعت کو جملہ ضروریا ت کا کفیل تصور کرتاہے۔اس کی نظرمیں عالم امکان میں کسی قسم کا بخل یا قصور نہیں ہے۔وہ ان اقتصادی مشکلات کو طبقاتی نزاع کا نتیجہ بھی نہیں قرار دیتابلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مشکل صرف انسان سے پیداہوتی ہے۔
قرآن کریم نے اس امر کی صاف وضاحت کردی ہے:
اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّـهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾
اللہ نے تمہارے لئے زمین وآسمان کو پیداکیاپھر آسمان سے پانی برساکر میوے پیداکئے جو تمہارا رزق ہے،تمہارے لئے کشتیوں کو مسخر کردیاتاکہ حکم الٰہی سے سمندرمیں سیر کریں۔نہروں کو مسخرکیا،شمس وقمر کے حرکات مسخر کئے، لیل ونہارکو مسخرکیا اور وہ سب کچھ دے دیا جس کا تم نے سوال کیاتھا۔اب اگر اس کی نعمتوں کا حساب کرنا چاہوتونہیں کرسکتے ہو۔(لیکن اسے کیا کیاجائے کہ)انسان بڑاظالم وناشکراہے۔(ابراہیم32تا34)
ان فقرات سے صاف ظاہر ہوتاہے کہ خالق کائنات نے عالم کی اس وسیع فضا کو مصالح ومنافع سے پرکردیاہے۔اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں پیداکردی ہیں لیکن انسان نے ان مواقع کو اپنے ہاتھ سے دے دیاہے اور وہ ظالم ومنکربن گیاہے۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اقتصادی مشکلات کا سرچشمہ یہی عملی زندگی کا ظلم اور نظرحیات کا انکار ہے۔اگر ظلم کے ذریعہ غلط تقسیم اور کفران نعمت کے ذریعہ پیداوار میں سستی
اور کاہلی نہ برتی جائے تو کوئی معنی نہیں کہ انسان اقتصادی مشکلات میں گرفتار ہو۔ اسلام نے اسی نقطۂ نظر سے ظلم وجود کے خاتمہ کے لئے تقسیم وتبادلہ کے احکا م وضع کئے اور کفران نعمت کے علاج کے لئے پیداوار کے احکام ومفاہیم مقررکئے۔ہماری بحث اس مقام پر صرف ظلم سے متعلق ہوگی۔کفران نعمت کے بارے میں ہماری تفصیلی گفتگو دوسری جلد میں ہوگی۔
طریق تقسیم (تقسیم میں عمل کا حصہ)
دولت کی تقسیم کے بارے میں انسانیت ہردور میں کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار رہی ہے۔کبھی افراد کی بنیاد پر تقسیم ہوئی تومعاشرہ پر ظلم ہوا،کبھی اجتماع کی بنیاد پر تقسیم ہوئی تو افراد پر ظلم ہوا۔
اسلام نے تقسیم کا ایک ایسا عادلانہ انداز اختیار کیاہے جہاں فردواجتماع دونوں کے حقوق کی رعایت ہو۔نہ فرد کے خواہشات کا درمیان حائل ہواجائے اور نہ اجتماع کی کرامت واہمیت کا انکار ہو اور اس طرح تقسیم کے جملہ طریقوں سے امتیاز پیداہوجائے۔
اسلام نے اپنے نظام تقسیم کو دواسباب سے مرکب کیاہے۔''عمل اور ضرورت'' اور دونوں کے معاشرہ میں مخصوص آثار ونتائج قرار دیئے ہیں۔ہمارا موضوع سخن بھی یہی ہوگاکہ ان اسباب کو تقسیم میں کیادخل ہے؟ اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب نے ان اسباب کو جودرجہ دیاہے اسلام نے اس سے کس قدر اختلاف کیاہے؟
تقسیم میں عمل کا حصہ
اس سلسلہ میں ہمیں سب سے پہلے اس اجتماعی تعلق کو دیکھنا ہوگا جوعمل اور ثروت کے درمیان قائم ہوتا ہے۔یہ تو معلوم ہے کہ عمل مختلف طبیعی مواد پر صرف ہواکرتاہے۔یہی زمین سے معدنیات نکالتاہے،یہی درخت سے لکڑیاں قطع کرتاہے،یہی دریاسے موتی حاصل کرتاہے،یہی فضاسے طائروں کا شکار کرتاہے،یہی طبیعت کے جملہ منافع مہیا کرتاہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمل سے ان تمام خام مواد میں کیارنگ پیداہوتاہے؟ اورعامل(کارکن) کا اس ثروت سے کیارشتہ ہوتاہے جو اس کی محنت سے پیداہوتی ہے؟
بعض حضرات کا خیال ہے کہ عمل اور عامل میں کوئی اجتماعی تعلق نہیں ہوتااسے بقدر حاجت ثروت مل سکتی ہے۔خواہ پیداوار کی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ا س لئے کہ محنت اور مشقت اس کا اجتماعی فریضہ تھا اس نے ادا کردیا۔اب اس کے ضروریات کا پورا کرنا معاشرہ کا فرض ہے لہٰذا اسے بھی اداہونا چاہئے۔
یہ خیال اشتمالیت سے بڑی حد تک متحد ہے اس لئے کہ وہ معاشرہ کو ایک ایسی مخلوق فرض کرتی ہے جس میں سارے افراد فنا ہوچکے ہوں اور ان کی حیثیت کا خاتمہ ہوچکا ہو، یہاں ہر فرد انسانی نطفہ کے ایک کیڑے کی حیثیت رکھتاہے جو باہمی جنگ وجدل سے ایک کیڑے کی شکل میں آتے ہیں۔
گویا افراد کی حیثیت کو ''کل حکمت''کرکے پگھلادیاگیاہے اور اس سے ایک ''انسان اکبر''تشکیل پایاہے جس کا نام ہے معاشرہ اور سماج، اب یہی معاشرہ پوری ثروت کا مالک ہے اور یہی افراد کی معیشت وزندگانی کا ذمہ دار، یہ افراد ایک کارگاہ میں ایک مشین کے پرزوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔
جس طرح پرزے مالک نہیں ہوتے بلکہ انہیں بقدر ضرورت تیل دے دیاجاتا ہے اسی طرح بنی نوع انسان کو بقدر حاجت غذامہیا کردی جائے گی اور انہیں مالک نہیں فرض کیاجائے گا۔
اس طرزفکر کی بنیادیہ ہے کہ انسان ذریعۂ پیداوار ہے لیکن وسیلۂ تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم کی میزان میں فقط ضرورت کا حصہ ہے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اشتراکی اقتصاد کا خیال ہے کہ عمل وعامل میں ایک بڑاعمیق ربط ہے۔عامل ہی اپنے عمل سے مواد کی قیمت پیداکرتاہے ۔اسی کی وجہ سے خام مواد میں جان آتی ہے۔لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے اس کے نتیجۂ عمل سے محروم کردیاجائے، تقسیم کا معیار حاجت وضرورت کو نہ ہونا چاہئے بلکہ اس کا تمام تردارومدار عمل پر ہوناچاہئے جو جس قدر عمل کرے اسی قدر حقدار ہو۔
اسلام ان دونوں نظریات سے الگ عقیدہ کا حامل ہے وہ اشتمالیت کی طرح عامل کو اپنے نتیجۂ عمل سے الگ کرکے معاشرہ کو اس کی دولت پر قابض نہیں بناناچاہتا۔اس لئے کہ اس کی نظرمیں معاشرہ کسی مستقل شیء کا نام ہے بلکہ انہیں افراد کے اجتماع کی ایک تعبیر ہے لہٰذا افراد کو بے حیثیت قراردے کر معاشرہ کی ہمدردی ایک بے معنیٰ شے ہے۔
وہ اشتراکیت کے مانند عامل کو خلاقِ قیمت بھی تعلیم نہیں کرتابلکہ قیمت کی تخلیق میں خام مواد کو حقدار قرار دیتاہے اور اس کی قدروقیمت کا معیار اجتماعی رغبت ومیلان کو سمجھتا ہے۔اس کی نظرمیں عامل کو اپنے عمل کے نتائج سے استفادہ کرنے کا پورا پورا حق ہے۔اس لئے کہ ایہ انسان کی فطری خواہش ہے اور انسان چاہتاہے کہ جس طرح اس نے اپنی زحمت سے عمل کیاہے اسی طرح اپنی خواہش کے مطابق اس کے نتائج پر تصرف کرے۔وہ اس انفرادی شعور سے کسی وقت بھی الگ نہیںہوسکتاخواہ اس کی زندگی تمام تر مارکسی ماحول میں کیوں نہ گذری ہو۔
یہی وجہ ہے کہ مارکس ماحول میں ابتداسے کام ہی معاشرہ کے لئے کیاجاتاہے تاکہ انفرادیت کی رگ حمیت نہ پھڑکنے پائے ورنہ اگرانسان اپنے نام پرکام کرے گا تو یہ برادشت نہیں کرسکتاکہ اس کے ثمرات ونتائج دوسرے شخص کے زیر تصرف آجائیں۔
اس بیان سے واضح ہوجاتاہے کہ اسلام ملکیت کے بارے میںعمل کو خاطر خواہ اہمیت دیتاہے اور عامل کو اپنے نتائج عمل سے پوراپورا استفادہ کرنے کا موقع دیتاہے۔وہ انفرادیت کے شعور کو پامال نہیں کرناچاہتااور نہ اس کا مقصد انسان کی داخلیت سے نبرد آزمائی ہے۔
مختصر یہ ہے کہ عمل کے بارے میں تین مسلک ہیں:
اِشْتِمَالِیَّتْ اس کا خیال ہے کہ عمل کے نتائج سماج کی ملکیت ہیں افراد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اِشْتِرَاکِیَّتْ اس کا خیال ہے کہ عمل بنیاد قیمت ہے لہٰذا پوری قیمت عامل کو ملنی چاہئے۔
اِسْلَام اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عمل موجب ملکیت ضرور ہے لیکن خلاق قیمت نہیں، قیمت دیگر عناصر سے بھی پیداہوتی ہے۔
موتی اپنی آب وتاب ذاتی طور پر رکھتاہے اور وہ ایک قدر وقیمت رکھتاہے۔دریا سے نکالنے والا اسے یہ قدروقیمت نہیں دے سکتا۔
تقسیم میں ضرورت کا حصہ
نظام تقسیم میں جس طرح عمل ایک اہم عنصر ہے۔اسی طرح ضرورت بھی ایک بڑا درجہ رکھتی ہے۔اسلامی معاشرہ میں یہی دونوں عنصر ایسے ہیں جن کی اجتماعی کار گذاری سے نظام تقسیم کی تشکیل ہوتی ہے۔اس اجتماعی کار گذاری کی تفصیل کے لئے معاشرہ کو تین حصوں میں تقسیم کرناپڑے گا۔
(1) وہ لوگ جو اپنی فکر اور فطری صلاحیتوں کی بناپر اپنی معیشت کے اسباب مہیا کرنے پر پوری پوری قدرت رکھتے ہیں۔
(2) وہ لوگ جو صرف بقدرشکم سیری کام کرسکتے ہیں اس سے زیادہ محنت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔
(3) وہ لوگ جو بدنی کمزوری یا عقلی مرض کی بناپر کسی کام کے کرنے سے عاجزہیں اور سماج کی گردن پر ایک بار ہیں۔
اسلامی نظام اقتصادمیں پہلا گروہ اپناپوراحصہ اپنے عمل کی بنیاد پر حاصل کرے گا اس لئے کہ اس نے کام کیاہے اور کام ہی ملکیت کا وسیلہ ہے۔ اس کے بارے میں ضرورت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا بلکہ اسلامی حدود کے اندر پوری مشقت کا پورا ثمر قرار دیاجائے گا۔
دوسرا فرقہ بقدر ضرورت خود ہی کسب کرسکتاہے لہٰذا اس کی بنیادی ملکیت کا دارو مدار عمل پرہوگا لیکن چونکہ دیگر ضروریات کے اعتبارسے عاجز ہے لہٰذا اس سلسلے کی املاک کا معیار ضرورت کو قرار دیاجائے گا۔
تیسرے فرقہ کی تمام تر ذمہ داری معاشرہ پر ہے وہ کسی قسم کے کام پر قادر نہیں ہے لہٰذا اس کی ساری ملکیت حاجت وضرورت کی ممنون کرم ہوگی۔
یہیں سے یہ بھی واضح ہوجائے گاکہ اسلامی اقتصاد میں ضرورت کا کیامرتبہ ہے اور اس کو نظام تقسیم میں کس قدر دخل اندازی کا حق ہے؟
ضرورت اسلام واشتمالیت کی نظر میں
اشتمالیت اپنے مخصوص نظریہ کی بناپر ضرورت کو نظام تقسیم کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ اس کی نظرمیں کسی شخص کو بھی اپنی ضرورت سے زیادہ املاک کا استحقاق نہیں ہے خواہ اس کے عمل کی مقدار کسی قدر زیادہ کیوں نہ ہو لیکن اسلام عمل کو بھی ذریعۂ تقسیم قرار دیتاہے اور اس کی اہمیت کا قائل ہے۔اس لئے کہ اس کے ذریعہ انسان کی صلاحیتوں کا اظہار ہوتاہے۔مقابلہ اور سبقت کے جذبات کام کرتے ہیں۔ہر شخص اپنے پورے امکانات کو صرف کرتاہے اور نظام اشتمالیت کی طرح اس کے فطری محرکات پسپا نہیں ہوتے۔اس کے عملی جذبات کو فنا نہیں کیاجاتا۔ضرورت بھر ملکیت پر اکتفا کرنے کی پابندی لگاکر عملی قوتوں کومشلول نہیں بنایا جاتااور ہمت شکنی کے ذریعہ اقتصادی زندگی کو تباہ نہیں کیاجاتا۔
ضرورت اسلام واشتراکیت کی نظر میں
اشتراکیت اپنے مخصوص طرز فکر کی بناپر عمل کو قیمت کی بنیاد قرار دے کر ضرورت کو بالکل مہمل وعبث تصور کرتی ہے۔اس کی نظرمیں اگر عامل نے اپنی ضرور ت سے زیادہ پیداکر
لیاہے تو وہ بھی اسی کا ہے اور اگر کم پیداکیاہے تو بھوکا رہنا بھی اسی کا حصہ ہے سماج اس کی ضرورت کا ذمہ دار نہیں ہے۔
اسلام نے اس کی شدید مخالفت کی ہے۔وہ بااستعداد عامل کو اس کے نتائج عمل سے محروم نہیں کرتالیکن اسی کے ساتھ ساتھ بے استعداد اور عاجز انسان کی زندگی کی بھی ذمہ داری لیتاہے۔
اشتراکیت صرف اپنے نتیجۂ عمل پر اکتفار کرنے اور بالائی طبقہ کے امتیازات پر صبر کرنے کی دعوت دیتی ہے اور اسلام عمل کے ساتھ ضرورت کو معیارقرار دے کر اس کی معیشت کے اسباب مہیاکرتاہے،اس نے نہ تو صاحب استعداد کی صلاحیت کو ضائع کیاہے اور نہ عاجز ومسکین کی زندگی کو۔ اسلام واشتراکیت جہاں دوسرے فرقہ(بقدر ضرورت کام کرنے والا گروہ)کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں وہاں تیسرا فرقہ بھی ان کے درمیان محل نزاع بناہواہے۔میرا مقصد یہ نہیںہے کہ میں آج کے اشتراکی سماج پر تبصرہ کروں اور ان اخبار کو نقل کروں جو مخالفین اشتراکیت نے درج کئے ہیں اور جن میں اس طبقہ کے لئے موت کے حتمی ہونے کا اظہار کیاگیاہے۔اس لئے کہ میراکام نظریات پر تنقید کرنے کا ہے۔
مجھے خارجی ماحول سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ میراکہنا یہ ہے کہ اشتراکیت اپنے نظریات کی بناپر اس فرقہ کو زندگی کا حق نہیں دے سکتی،اس لئے کہ اس کے یہاں تقسیم ثروت پیداوار کے اعتبار سے ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فرقہ اپنی بے لیاقتی کی بناپر ہر قسم کی پیداوار سے عاجز ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے قدیم معاشروں میں غلاموں کی موت اور ان کی نتائج اعمال سے محرومی کو ممدوح ومستحسن شے قرار دیاہے اس لئے کہ وہ طبقاتی نزاع کا نتیجہ تھی اور جب طبقات ہی معاشرہ کی جان ہوں تو یہ غریب فرقہ تو کہیں کا نہ رہے گا۔یہ نہ سرمایہ دار کہے جانے کا مستحق ہے اور مزدور۔اسے نہ سرمایہ ملے گا اور نہ اجرت اور ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں موت کا حتمی ولازمی ہونا ایک یقینی امر ہے۔
لیکن اسلام نے اپنے طریقۂ تقسیم کو طبقات سے الگ کرلیاہے اور اسے اپنے اعلیٰ اقدار ومفاہیم کی روشنی میں مرتب کیاہے اس کے یہاں قادر وعاجز، بااستعداد و بے لیاقت سب کو جینے کا حق ہے۔
یہاں تیسرے فرقہ کی زندگی کا بھی تحفظ کیاجائے گا اس لئے کہ وہ بھی انسانوں ہی کا ایک جز ہے اور اسی سماج کا ایک حصہ ہے۔
یہاں اچھے معاشرہ کا تصور اسی وقت مکمل ہوگاجب اس عاجز ومسکین فرقہ کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری لے لی جائے۔
ان کے اموال میں سائل اور محروم دونوں کا حق ہے۔(قرآن کریم)
ضرورت اسلام وسرمایہ داری کی نظر میں
سرمایہ دار اقتصاد ضرورت کے سلسلہ میں اسلام کا بالکل مخالف ہے۔وہ تقسیم ثروت میں ضرورت کوکوئی مرتبہ نہیں دیتا۔اس کے یہاں ضرورت کی زیادتی مزید محرومی کاباعث بن جاتی ہے یہاں تک کہ اکثر افراد تقسیم کے میدان سے الگ کردیئے جاتے ہیں اور وہ ہلاکت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور اس کا رازیہ ہے کہ ضروریات زندگی کی زیادتی کے ساتھ سرمایہ دار بازار میں کاریگروں اور مزدوروں کی زیادتی ہوجاتی ہے اور چونکہ مزدور عام جنس کے بھاؤبکتے ہیں۔اس لئے جنس کی زیادتی سے کم قیمت ہوجاتے ہیں۔یہاں تک کہ جب بازار کوجنس کی ضرورت نہیں رہی تو اکثر صاحبان ضرورت بیکاری کا شکار ہوجاتے ہیں اب یہ لوگ یاتو محالات کو ممکن بناکر جئیں گے یا پھر موت کی آغوش میں آرام کریں گے۔
اس نظام میں ضرورت کوئی شے نہیں ہے۔بلکہ اس کا معاشرہ پر غلط اثرپڑتاہے۔ اس کی وجہ سے اکثر بااستعداد افراد کو بھی محرومی ہوجاناپڑتاہے اور ان کی اجرت میں بھی کمی واقع ہوجاتی ہے۔
انفرادی ملکیت
اسلام جب انسان کے طبیعی رجحان کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اس کے نتیجۂ عمل کا حقدار قرار دیتاہے تو اس سے دواہم نکات واضح ہوتے ہیں:
(1) اقتصادیات میں انفرادی ملکیت کا تصور صرف اس بناپر ہے کہ انسانی عمل ملکیت کا باعث ہوتاہے اور یہ ہرشخص کا ایک فطری رجحان ہے کہ جس طرح عمل کو اپنی ذاتی محنت ومشقت سے انجام دیتاہے اسی طرح اس کے ثمرات ونتائج سے بھی خود ہی استفادہ کرے۔ اسی انفرادیت کی خواہش کو علم الاجتماع کی اصطلاح میں ملکیت کہتے ہیں۔اسلام دین فطرت ہونے کے اعتبار سے انسان کے اس جذبہ کا احترام کرتے ہوئے اس کی انفرادی ملکیت کا اعتراف کرتاہے لیکن اس ملکیت میں مختلف تصرفات کو علم الاجتماع کے حوالے کردیتاہے۔ اس کے حدود وقیود اجتماعی نظام کی طرف سے مقرر ہوں گے اس لئے انفرادی ملکیت کی مطلق آزادی معاشرہ کے حق میں انتہائی مضر ہے یہ مسئلہ اجتماعیات ہی سے حل ہوگاکہ انسان کو اپنے املاک میں مطلق تصرفات کا حق ہے یا نہیں؟وہ اسے تبدیل کرے یا اس سے تجارت کرنے کا بھی حق رکھتاہے یا نہیں؟وغیرہ
اسلام نے خودبھی ان حدود وقیودکا اہتمام کیاہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کے جملہ حدود، مفاہیم واقدار کی بناپر ہیں جن پر اس کے سارے نظام کی بنیاد ہے اور اسی لئے اس نے اسراف کو حرام کیاہے اور باقی مصارف کو جائز رکھاہے،سودی تجارت کو ممنوع قرار دیاہے اور باقی طریقوں کو جائز رکھاہے۔
(2) اسلام کی نظرمیں انسان کی انفرادی ملکیت عمل سے پیداہوتی ہے لہٰذااسے عمل ہی کے دائرہ تک محدود رہناچاہئے جہاں انسانی محنت کی دسترس نہ ہو وہاںاس ملکیت کا سوال بھی نہ اٹھنا چاہئے ۔گویا عالمی اموال کی دو قسمیں ہیں۔عمومی ثروت اور خصوصی دولت۔
خصوصی دولت سے مراد وہ مال ہے جو انسانی محنت سے تخلیقی یاصناعتی منزلیں طے کرتاہے جیسے غلہ،کپڑاوغیرہ یا انسانی عمل کو اس کے استخراج میں دخل ہوتاہے۔جیسے الیکٹرک، پٹرول کی برآمد کہ ان کا وجود انسانی محنت کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ انسانی صنعت نے انہیںکوئی خاص شکل دی ہے۔محنت کاکام صرف یہ ہے کہ انہیں استفادہ کے قابل بنادے۔
اسی قسم کی دولت میں انفرادی ملکیت کی بحث اٹھتی ہے اوریہیںاسلام نے ملکیت اور حقوق کے احکام وضع کئے ہیں۔
عمومی ثروت سے مرادوہ اموال ہیں جن میں انسانی عمل کوکوئی دخل نہ ہوجیسے زمین کہ اس کی تخلیق میں انسانی اعمال کو کوئی دخل نہیں ہے۔
یہ بات اور ہے کہ بعض اوقات یہی عمل اس سے استفادہ کے لئے ضروری ہوجاتاہے لیکن یہ صورتیں محدود معین قسم کی ہیں۔عام طور پر ایسا نہیں ہوتالہٰذا یسے اوقات میں زمین کا حکم معدنیات کا ہوجائے گا جن کی تخلیق خالق طبیعت کے ہاتھ سے ہوتی ہے لیکن استفادہ انسانی اعمال کے ہاتھوں۔
ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پر اس ثروت کو کسی کی ملکیت نہیں ہوناچاہئے۔اس لئے
کہ اس کی تخلیق میں انسانی عمل کو دخل نہیں ہے بلکہ تمام امت کے لئے مباح اور حلال ہونا چاہئے جس طرح کہ زمین کا حال ہے کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔عمل اس کی اصلاح میں حصہ لیتاہے اور وہ بھی محدود اوقات میں،لہٰذا اس عمل کو موجب ملکیت نہیں قرار دیاجاسکتا بلکہ اس سے صرف اتنا فائدہ ہوتاہے عمل کرنے والا اس سے استفادہ کرسکے اور دوسروں کو روکنے کا حق نہ ہو، اس لئے کہ زحمت اسی نے کی ہے،حق بھی اسی کا مقدم ہونا چاہئے۔یہ صریحی ظلم ہے کہ محنت کرنے والے کو بیکار لوگوں کے برابر بنادیاجائے۔لیکن اس خصوصیت کا تعلق صرف ان اوقات سے ہے جن میں محنت کرنے والا زمین سے استفادہ کرتارہے۔ اب اگر اس نے ہاتھ کھینچ لیاتو اس کا حق ختم ہوجائے گا اور زمین اپنی اصلی حالت کی طرف پلٹ جائے گی۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملکیت کا قانون صرف خصوصی دولتوں سے متعلق ہوتاہے عمومی ثروت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے اس لئے کہ ملکیت عمل سے پیدا ہوتی ہے اور اس ثروت میں کسی قسم کا عمل ہی صرف نہیں ہوتا۔اب اگر اس قانون میں کسی وقت کوئی استثناء ہوجائے تو اس کو قانون سے کوئی تعلق نہ ہوگابلکہ اس کوولی امر کے مصالح ومفاد کے حوالے کر دیا جائے گا جس کی تفصیل آئندہ آرہی ہے۔
ملکیت بھی ذریعۂ تقسیم ہے
عمل اور ضرورت کے بعدعالم تقسیم میں ملکیت کادور آتاہے۔اس لئے کہ اسلام نے انفرادی ملکیت کو جائز قرار دینے کے بعد مالک کے حقوق میں بھی اشتراکیت اور
سرمایہ داری نظریات سے اختلاف کیاہے۔اس نے نہ توسرمایہ دارانہ نظام کی طرح دولت بڑھانے کی مطلق آزادی دے دی ہے اور نہ اشتراکیت کی طرح فائدہ کے طریقوں کا گلا گھونٹ دیاہے بلکہ ایک معتدل موقف اختیار کیاہے۔تجارتی قوائد کو حلال کیاہے اور سودخوری کو حرام۔
سودخواری کی تحریم سرمایہ داری سے مقابلہ ہے اور تجارتی فوائد کے جواز میں اشتراکیت سے۔
ظاہر ہے کہ جب تجارتی فائدہ جائز ہوگا اور اسے مارکسی اصلاح کے مطابق ''زائد قیمت''کا درجہ حاصل نہ ہوگا تو انسان کے مال میں اضافہ ہوگا اور جب ملکیت سے فائدہ حاصل ہونے لگے گاتو تقسیم میں بھی اس کی دخل اندازی ضرور ہوگی۔اس لئے کہ دولت کے لئے اسلام میں اجتماعی عدالت کی ذمہ داریاں مقررکردی گئی ہیں۔فرق صرف یہ ہے کہ عمل اور ضرورت کا درجہ اولیٰ ہوگا اور ملکیت کا مرتبہ ثانوی۔ان مباحث کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ آرہی ہے۔
اسلامی تقسیم کامکمل نقشہ مختصر صورت میں یوں پیش کیاجاسکتاہے:
(1) عمل ملکیت کی بناء ہونے کی حیثیت سے تقسیم کااساسی ذریعہ ہے۔
(2) ضرورت وحاجت انسانی زندگی کا حق ہونے کی حیثیت سے تقسیم میںعظیم حصہ رکھتی ہے۔
(3) ملکیت بھی تقسیم کاایک ثانوی ذریعہ ہے ان تجارتی منافع کی بناپر جنہیں اسلام نے چند خاص قیود وشرائط کے تحت جائز قرار دیاہے۔
تبادلہ
اقتصادی زندگی کا ایک عام رکن جو تاریخی وجود میں پیداوار اور تقسیم سے متاخرہونے کے باوجود اہمیت میں ان سے کچھ کم نہیں ہے''تبادلۂ اجناس''ہے۔ انسان نے جب سے اجتماعی میدان میں قدم رکھاہے پیداوار اور تقسیم کے مسائل نے بھی اسی وقت سے جنم لیاہے اس لئے کہ سماج میں زندگی کے لئے عمل ضروری ہے اور عمل کے لئے تقسیم منافع کے اصول لازم ہیں گویا کہ پیداوار اور تقسیم کے مسائل اتنی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے بغیر اجتماعی زندگی کا ہونا محال ہے۔تبادلہ کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے اس لئے کہ ابتدائی معاشروں میں ضروریات زندگی کی قلت کی بناء پر لوگ باہمی پیداواراور باہمی تقسیم کی بناپر کام چلا لیاکرتے تھے اور کسی تبادلہ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی لیکن جب سے انسانی ضروریات زندگی نے ترقی کی ،اموال کی نوعیت نے مختلف رنگ اختیار کئے اور ایک انسان اس بات پر قادر نہ رہاکہ اپنے تمام ضروریات کا انتظام کر سکے تو اس وقت اس امر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تمام افراد باہمی طورپراعمال کوتقسیم کرلیں اورہر شخص اپنی مہارت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی شے ایجاد کرے اور اس کے بعددیگرضروریات کے لئے اپنی پیداکردہ جنس کا تبادلہ کرے گویا کہ یہ تبادلہ پیدوار اور خرچ کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ہر ایجاد کرنے والا اپنے مال کو نکالتاہے تاکہ دوسرے اموال کو درآمد کرسکے۔
لیکن افسوس کہ وہی ظلم جس نے قرآنی بیان کے مطابق انسان کو عالم طبیعت کے خیروبرکت سے محروم کر دیا یہاں بھی آڑے آگیا اور انسان نے تبادلہ جنس کے صحیح مفہوم کوفراموش کرکے اسے ذخیرہ اندوزی اور پس اندازی کا ذریعہ بنالیا اور اس طرح سماج ان تمام مشکلات سے دوچار ہونے لگاجو اشتراکیت کے اصول تقسیم سے سامنے آرہے تھے۔
تبادلہ کے بارے میں اسلام کی رائے معلوم کرنے سے پہلے معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلام کی نظرمیں تبادلہ کے غلط استعمال کا سبب کیاہے اور اس غلطی کے اثرات ونتائج کیاہیں؟تاکہ یہ بھی معلوم ہوسکے کہ اسلام نے اس مشکل کو کہاں تک حل کیاہے اور اس نے اپنا عادلانہ نظام کن اصولوں پر قائم کیاہے؟
اس مقام پر یہ بات بھی پیش نظررہنی چاہئے کہ تبادلۂ اموال کی دو قسمیں ہیں۔ تبادلۂ جنس، تبادلۂ نقد۔
تبادلۂ جنس:
تبادلہ کی وہ شکل ہے جہاں ایک جنس کو دوسری جنس سے تبدیل کیاجاتاہے۔ تبادلہ کی تاریخ میں سب سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ جب انسان اپنی ضرورت سے زائد جنس کو دے کر دوسرے شخص سے اس کی پیداوار کو حاصل کرلیاکرتاتھا۔اگر ایک شخص نے سوکیلو گیہوں پیداکیاہے تو پچاس کیلواپنی ضرورت کے لئے محفوظ کرکے باقی پچاس کیلو کو ایک معین مقدار میں روئی سے بدل لیاکرتاہے لیکن افسوس کہ یہ صورت حال زیادہ دنوں باقی نہ رہ سکی۔اس لئے کہ اس طرح انسانیت گوناگوں اقتصادی مشکلات میں گرفتار ہوگئی۔اب گیہوں کے مالک کو روئی اسی وقت مل سکتی ہے جب روئی کے مالک کو گندم کی ضرورت ہو اور روئی کے مالک کو گندم اسی وقت حاصل ہوسکتاتھا جب گندم کے مالک کو روئی کی ضرورت ہو۔
پھر قیمتوں کاتناسب بھی ایک مستقل مسئلہ بناہواتھا۔ظاہر ہے کہ گھوڑے کا مالک گھوڑے کو مرغی سے کبھی نہ بدلے گا۔اب نہ وہ گھوڑے کے ٹکڑے کرسکتاہے اور نہ حسب ضرورت مرغی حاصل کرسکتاہے ۔اس سے بڑی مشکل قیمتوں کے تعین کی تھی اس لئے کہ قیمت کا تعین دوسری جنس کے مقابلہ سے پیداہوتاہے اور یہاں تبادلہ ہی محل بحث ہواتھا۔
یہی وہ اسباب تھے جن کی بناپر ہرانسان کو ان مشکلات کے حل کرنے کی فکرہوئی اور وہ مختلف طریقے سوچنے لگا۔آخرکار یہ بات ذہن میں یہ راسخ ہوگئی کہ''تبادلہ''جنس کے بجائے نقد سے ہونا چاہئے اور اس طرح تبادلہ کی دوسری شکل وجود میں آگئی۔
تبادلہ نقد:
حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں نقد سکہ نے جنس کی وکالت کاکام انجام دیاہے۔ اب خریدار کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی جنس کو دے بلکہ نقد سکہ بھی دے کر مال خرید سکتاہے۔سابق مثال میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مالک گندم کومیووں کی ضرورت ہوتو وہ اس امر کا محتاج نہیں ہے کہ میوہ فروش کو گندم دے بلکہ یہ بھی ہوسکتاہے کہ گندم روئی والے کے ہاتھ بیچ کر نقد مال سے میوہ خرید لے۔
سکہ کی یہی وکالت تھی جس نے جنس کے تمام مشکلات کو حل کر دیا۔اب ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق جنس خرید سکتاہے۔طرف مقابل کو اس کی پیداوار کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔اسی طرح قیمتوں کے تناسب کا مسئلہ بھی صاف ہوگیا۔اس لئے کہ ا ب تناسب نقد کے معیار پر قائم ہوگا۔
اصل قیمت کے تعین کی شکل بھی آسان ہوگئی ہر شے کو اسی سکہ کے معیار پر پرکھ لیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ سکہ کی زندگی کا یہ پہلوجہاں اس قدرروشن اور حلال مشکلات تھا وہاں ایک دوسرا پہلو انتہائی تاریک اور موجب وحشت بھی تھااس لئے کہ سکہ نے فقط وکالت ہی کاکام نہیں کیا بلکہ انسان کی اقتصادی زندگی سے کھیلنا بھی شروع کردیاجس کا نتیجہ یہ ہواکہ سکے کے نتائج جنس کے نتائج سے بدتر ہونے لگے۔فرق صرف اتنا رہ گیا کہ جنس کہ مشکلات فطری اور طبیعی تھے اور سکے کے مشکلات انسان ہی کے مظالم کا نتیجہ تھے۔
اس دعویٰ کی مزید وضاحت کے لئے تبادلہ کے ان تغیرات کا جائزہ لینا ضروری
ہے جو جنس اور نقدکے مختلف ادوار میں پیش آئے۔
جنس کے تبادلہ کے دور میں خریدار اور بائع کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ہر شخص بائع بھی تھا اور مشتری بھی۔ایک جنس دیتاہے اور دوسری حاصل کرتاتھا اور اس طرح دونوں کی ضرورتیں ایک ہی معاملہ میں پوری ہوجاتی تھیں لیکن سکے کے دورنے یہ امتیاز بھی پیداکر دیا،اب صاحب جنس کو تاجر اور صاحب نقد کو خریدار کہتے ہیں۔اب روئی کے طالب کو ایک معاملہ میں روئی نہیں مل سکتی بلکہ ضرورت ہے کہ پہلے گندم کو نقد سے بیچے اور پھر اس نقد سے روئی خریدے اور اس طرح ہر معاملہ کے لئے دہرے معاملات وجود میں آئیں۔
اس تفرقہ کا ایک خطرناک پہلو یہ نکل آیاکہ خرید کا معاملہ فروخت سے موخر ہونے لگا اب ضرورت اس امر کی نہیں رہی کہ ہر بیچنے والا اسی وقت خرید بھی کرے بلکہ یہ بھی ممکن ہو گیاکہ ایک مال کو فروخت کرکے نقد محفوظ کرلے اور دوسرے مال کو پھر کسی وقت میں خریدے۔
در حقیقت اس ایک غنیمت موقع نے معاملات کی نوعیت ہی بدل دی،پہلے تاجر خریداری پر مجبور تھا اس لئے تجارت کے وقت کی قیمت سے خریدنا پڑتا تھا اب وہ خریداری میں مختارہوگیا لہٰذا مناسب قیمت کے وقت میں خریدے گاکہ ادھر دولت جمع کی جائے گی اور ادھر مال کی ذخیرہ اندوزی ہوگی۔
نقد کا ایک فائدہ یہ بھی ہواکہ ذخیرہ اندوزی کے تمام اموال ایک عرصہ کے بعد اپنی قدروقیمت کھوبیٹھتے ہیں اور ان کی حفاظت پربھی کچھ خرچ کرنا پڑتاہے لیکن سکہ ان تمام عیوب سے بری ہے اس کی قدرقیمت میں دوام وثبات اور اس کا تحفظ کم خرچ ہے اس سے ہر شیء بروقت مل بھی سکتی ہے۔
نتیجہ یہ ہواکہ سماج میں ذخیرہ اندوزی کی رفتار تیز ترہرگئی اور تبادلہ نے اپنا فریضہ ترک کردیا۔کل تک خرید وفروخت کاکام برابر سے ہورہاتھا اور آج مال فروخت ہوتاہے تو
سکہ کو داخل خزانہ کرنے کے لئے، غرض وطلب کی نسبت بدل گئی ہے اور احتکار کے جذبات کار فرما ہوگئے ہیں۔ہر ذخیرہ اندوزبازار کا سارا مال خریدکر جمع کرلیتاہے۔فروخت کرنے کے لئے؟نہیں قیمت کو بڑھانے کے لئے یا اس قدر کم کردینے کے لئے کہ دوسرے چھوٹے تاجر تباہ حال ہوجائیں اور سرمایہ دار کو مال ذخیرہ کرنے کے بہتر سے بہتر مواقع مل سکیں۔ سماج کا پورا سکہ اپنے خزانے میں جمع ہوجائے اور تبادلہ کی ابتری سے اکثریت افلاس وتنگدستی کا شکار ہوجائے۔
ظاہر ہے کہ اس افلاس سے پیداوار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گی اس لئے کہ جب خریداری کا بازار کساد ہوجائے گا اور بڑے سرمایہ دار کم سے کم قیمت پر خریدنے لگیں گے تو پیداوار والے افراد بھی سست پڑجائیں گے اور پوری اقتصادی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔
یادرکھئے کہ نقد کے مشکلات اسی حد پر ختم نہیں ہوتے بلکہ ابھی ایک منزل اور سامنے آتی ہے۔ اب تک یہ سکے ذخیرہ اندوزی کاکام دیتے تھے اور اب قرض دے کر اضافہ کے اسباب بھی مہیاکر رہے ہیں۔سودخوری کا بازار گرم ہورہاہے۔سرمایہ داروں کے صندوق اوربینکوں کی تجوریاں پرہو رہی ہیں ،کوئی تاجر کارخانہ کی طرف ا س وقت تک نہیں جاتا جب تک اسے اس بات کایقین نہیں ہو جاتاکہ تجارت کا فائدہ قرض یابینک بیلنس کے سود سے زیادہ ہوگا،نتیجہ یہ ہواکہ ہر شخص نے اپنامال بینک کے حوالے کرنا شروع کر دیا اس امید پر کہ اس میں اضافہ ہوگا اور بینک نے بھی عوام کی دولت گھسیٹنا شروع کر دی یہ دکھاکر کہ تمہارا مال روز بروز ترقی کرے گا۔اموال پیداوار پر صرف ہونے کے بجائے بینک میں جمع ہونے لگے۔ملک کی زمام بینکوں کے ہاتھ میں آگئی اور اجتماعی توازن کے مفاہیم پامال ہونے لگے۔
تبادلہ کے ان تمام مشکلات کو نہایت ہی جلدی میں ذکر کیاگیاہے پھر بھی اس سے
یہ واضح ہوگیاہے کہ اقتصادی زندگی کے تمام مشکلات نقد مال کے غلط استعمال اور اس کے ذخیرہ اندوزی اور پس اندازی کا شکار ہونے کا نتیجہ ہیں۔شاید اسی کی طرف رسول اکرم نے اشارہ فرمایاتھا:
زرددینار اور سفید درہم تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کردیں گے جس طرح تم سے پہلے والوں کو کیاہے۔
اسلام نے ان تمام مشکلات کا ایک مناسب علاج کیاہے اور تبادلہ کو اپنی اصلی حالت پرلانے کے لئے حسب ذیل طریقے اختیار کئے ہیں:
(1) خزانہ داری کی مخالفت: اس طرح کہ جمع شدہ مال پرزکوٰة واجب کردی۔اب اگر مال جمع ہی رکھاجائے تو چند سال کے بعد اس کا خاتمہ ہوجائے گا اور اگر نکالاجائے تو اقتصادیات کی ترقی ہوگی جو عین مقصود ہے۔
خزانہ داری کے اسی پہلوکو نظرمیں رکھتے ہوئے قرآن کریم نے اس پر جہنم کی تہدید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ عام طور سے حقوق سے کنارہ کشی کرتے ہیں ورنہ اتنی دولت کے جمع ہوجانے کا سوال ہی کیا ہے۔ارشاد الٰہی ہے:
جو لوگ سونا اورچاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور پھر انہیں خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، جہنم میں انہیں سکوں کو گرم کرکے ان کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغاجائے گا(ان کو بتادیا جائے گا)کہ یہ تم نے ہی جمع کیاہے لہٰذا اس کا مزہ چکھو۔
(2) سودخوری کو مطلق طریقہ سے حرام کردیا اور اس طرح ان تمام مشکلات کا علاج کیاجو سود سے پیداہورہے تھے اور جن سے اجتماعی توازن برباد ہورہاتھا اب نقد جنس کی وکالت کا کام کرے گا اور اسے غلط اندازی کا موقع نہ مل سکے گا۔
بعض سرمایہ دارانہ ذہنیت کے لوگوں کا خیال ہے کہ بینک کے سودپرپابندی لگادینے
کا نتیجہ یہ ہوگاکہ تمام بینک بندہوجائیں گے حالانکہ اقتصادی زندگی کی چہل پہل انہیں بینکوں سے وابستہ ہے۔
لیکن یہ خیال درحقیقت اس غفلت کا نتیجہ ہے جس نے نہ بینک کے مشکلات وخطرات کو سمجھنے کا موقع دیاہے اور نہ ان علاجوں پر غورکرنے کا موقع دیاہے جو اسلام نے اس سلسلہ میں مقرر کئے ہیں۔
(3) ولی امر کو ایسی صلاحتیں دیں جن کی بناپراسے تبادلہ کی رفتار کی کڑی نگرانی کاحق حاصل ہواور وہ ایسے تصرفات کا راستہ روک سکے جو اقتصادی زندگی کی تباہی کا باعث ہورہے ہوں یا بازار میں کسی ناجائز قبضہ کا ارادہ رکھتے ہوں۔
ہم انشاء اللہ آئندہ گفتگو میں ان نکات کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے اس لئے کہ اس وقت ہمارا موضوع کلام اسلامی اقتصادی ہوگا۔
٭٭٭