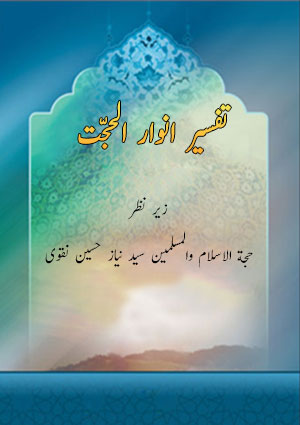تفسیر انوار الحجّت
زیر نظر
حجة الاسلام والمسلمین سید نیاز حسین نقوی
ناشر
موسسہ امام المنتظر قم ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
سورة الفاتحہ
مکی، سات آیات سورة الفاتحہ آیات: ۷ عدد الفاظ: حروف:
مقام مکہ، اور کہا گیا ہے کہ مدینہ میں بھی نازل ہوامگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف مدنی سورہ ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ یہ سورہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوا ہے اس سلسلے میں کافی ادلہ موجود ہیں لیکن اختصارکو مد نظر رکھتے ہوئے تین دلیلیں پیش کرتے ہیں۔
( ۱) جیسا کہ امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔
نزلت فاتحة الکتاب بمکة من کنز تحت العرش
سورہ فاتحہ الکتاب عرش کے نیچے سے ایک خزانے میں سے مکہ میں نازل ہوا (منہج الصادیقین ج ۱ ص ۸۶) ۔
( ۲) نماز چونکہ بعثت کے فورا بعد ہی واجب ہوئی اور سورہ فاتحہ اس کا لازمی جز ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ
لا صلاة الابا لفاتحة
سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی
لہذا یقینا یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے اورشروع ہی سے نماز میں پڑھا جاتا ہے۔
( ۳) یہ سورہ سبع مثانی ہے (سبع مثانی کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کی سات آیتیں ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھی جاتی ہیں۔) اور سبع مثانی کا ذکر قران میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے۔
( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) ( سورہ حجر کی آیت ۸۷)
سورہ حجر یقینا مکی سورہ ہے اسی بنا پر سورہ فاتحہ بھی مکی ہے
زمان نزول کے بارے اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ بعثت کے بعد بلکل ابتدائی ایام میں نازل ہوا اور اس کا سبب نزول نماز ہے چونکہ یہ سورہ نماز کا لازمی جز ہے۔( مناقب ابن شہر آشوب ج ۱ ، ص ۴۴)
اسمائے سورہ اور وجہ تسمیہ
سیوطی نے کتاب الاتقان میں اس سورہ کے پچیس تک نام گنوائے ہیں،ان میں چندمندرجہ ذیل ہیں۔
( ۱)فاتحةالکتاب ۔کیونکہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔
( ۲) حمد۔کیونکہ اس میں حمد الہی ہے۔
( ۳) ام الکتاب۔کیونکہ قرآن مجید کے بنیادی مفاہیم پر مشتمل ہے۔
( ۴) سبع المثانی۔کیونک یہ نام سورہ حجر میں ذکر ہوا ہے۔
( ۵) اساس۔کیونکہ یہ سورہ قرآن مجید کی بنیاد اور جڑہے۔
( ۶) شفاء۔ کیونکہ یہ ہر مرض کے لئے شفاء ہے۔
( ۷) کافیہ۔کیونکہ نماز میں اس کا پڑہنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور سورہ کفایت نہیں کرتا۔
( ۸) صلاة۔ کیونکہ یہ نماز کا لازمی جز ہے۔
( ۹) کنز۔کیونکہ یہ خدا کے خزانوں میں سے عظیم ترین خزانہ ہے۔
( ۱۰) دعاء۔ کیونکہ اس میں دعا کا طریقہ سیکھایا گیا ہے۔
ان میں سے پہلے چار نام مشہور ہیں۔
خصوصیات سورہ۔
اس مبارک سورہ کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔
( ۱) اجما ل قرآن۔
قرآن مجید میں ہر خشک وتر کا ذکر موجود ہے اور یہ سورہ اس کا اجمال چونکہ سنت الہی یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کو اجمال سے ذکرکیا جاتا ہے اور پھر تدریجا اسے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے یہ سورہ جن بنیادی اصولوں پرمشتمل ہے پورا قرآن ان کی وضاحت کرتا ہے۔
( ۲) قرآن کا مرادف۔
خود قرآن میں اس سورہ کو قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے جیساکہ ارشاد ربالعزت ہے۔
( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ )
اور ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطاء کیا ہے۔
چونکہ اس سورہ کا ایک نام سبع مثانی ہے اور اسے قرآن کے مرادف قرار دیا گیا ہے۔
( ۳) منفرد لب ولہجہ۔
اس سورہ کا لب ولہجہ اور انداز بیان باقی سورتوں سے بنیادی فرق رکھتا ہے قرآن مجید کی باقی سورتیں کلام خدا ہیں مگر اس سورہ میں خدا وند عالم مخلوق کے کلام کو بیان فرمارہاہے۔
( ۴) دعا اور گفتگو کے منفرد انداز کی تعلیم۔
اس سورہ میں خدا وند متعال اپنی ذات سے بلا واسطہ دعا مانگنے اور گفتگوکرنے کا طریقہ سکھلا رہاہے اور درس دے رہاہے کہ پروردگار عالم کے حضور کیا درخواست پیش کی جائے اور کس انداز سے التجاء کی جائے۔
( ۵) رسول اکرم کے لئے خصوصی اعزاز۔
یہ سورہ پیغمبر کے لئے عظیم اعزاز اور عطیہ الہی ہے جیسا کہ حضرت امیرالمومینین علیہ السلام پیغمبر گرامی سے یہ حدیث نقل کرتا ہیں کہ آپ نے فرمایا۔
ان الله تعالى افرد الامتنان على بفاتحة الکتاب و جعلها بازاء القرآن العظیم
خالق کائنات نے سورہ حمددے کر مجھ پر خاص طور پر احسان کیا ہے اور اس کو قرآن مجید کے برابر قرار دیا ہے۔
( ۶) شیطان کی فریاد کا موجب۔
قرآن کی سورتوں میں فقط یہ سورہ ہے جو شیطان کے فریاد ونالہ کا موجب بنا جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔
ان ابلیس اربع رنات اولهن حین اهبط الی الارض و حین بعث محمدصلی الله علیه وآله وسلم و حین انزلت ام الکتاب ۔
شیطان نے چار مرتبہ بلند آواز سے فریاد کی پہلی مرتبہ جب بار گاہ الہی سے لعنت کا مستحق ٹھرا دوسری مرتبہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مبعوث ہوئے چوتھی اور آخری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔
( ۷) نماز کا لازمی جز۔
نماز دین کا ستون ہے اور یہ اس کا لازمی جز ہے اور یہ اسی سورہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی باقی سورتوں میں یہ خصوصیت نہیں ہےلاصلواةالا بفاتحةالکتاب
( ۸) کتاب الہی کا آغاز۔
اس سورہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔
( ۹) قرآن میں نازل ہونے والا پہلا سورہ۔
یہ قرآن میں نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے۔
( ۱۰) آسمانی صحیفوں کا جامع۔
یہ سورہ تمام آسمانی صحیفوں کے علوم،برکات اور ثواب کا جامع ہے جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے خدا وند متعال نے آسمان سے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں سے چار کا انتخاب کیا، اور باقی سو کتابوں کے علوم کو ان چار کتابوں میں جمع فرمایا اور وہ چار کتابیں توریت، انجیل،زبور اور قرآن تھیں۔
پھر ان چاروں کے علوم و برکتوں پڑھنے اور جاننے کے ثواب کو قرآن میں رکھا اور پھر قرآن کے علوم اور برکتوں کو جمع کیا اور ایک مفصل سورہ میں رکھا اور پھر مفصل سورہ کے علوم اور برکتوں کو فاتحةالکتاب میں جمع کر دیا اور فاتحةالکتاب کا پڑھنے والا اس طرح ہو گا جیسے اس نے ایک سو چار کتابیں پڑھی ہوں۔
سورہ حمد کے فضائل
اس سورہ کے فضائل کا احصاء نا ممکن ہے البتہ ہم تبرکا پانچ کے تذکرہ پر اکتفاء کرتے ہیں۔
( ۱) اسم اعظم:
روایات میں اس سورہ کی فضیلت میں بیان ہوا ہے کہ اس میں یقینی طور پر اسسم اعظم موجود ہے جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔
اسم الله الاعظم مقطع فی ام الکتاب
قطعی طور پر سورہ حمد میں اسم اعظم الہی موجود ہے۔
( ۲) قرب الہی :
اس سورہ کی تلاوت قرب الہی کا موجب ہے اور اسی وجہ سے شیعہ وسنی روایات میں اسکی ارادے کو مظبوط کرتی ہے اور انسان کو گناہ اور گمراہی سے بچاتی ہے۔
( ۳) دو تہائی قرآن :
اس سورہ کی تلاوت کا ثواب دو تہائی قران کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے اسی وجہ سے پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے۔
ایما مسلم قراء فاتحة الکتاب اعطی من الاجر لانما قراء ثلثی القرآن اعطی من الاجر کانما تصدق علی کل مومن و مومنة
جو مسلما ن بھی سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے اسے قرآن کی دو تہائی پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا اور اس ے تمام مومنین اور مومنات کو صدقہ دینے کا بھی ثواب عطاہو گا۔
( ۴): شفاء :
یہ سورہ تمام جسمانی اور روحانی تکالیف کے لیئے شفاء ہے جیسا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول اکرم (ص) سے نقل کیا ہے۔
هی شفاء من کل داء الا السام والسام الموت ۔ (جوامع الجامع ج ۱ ،ص)
یہ سورہ موت کے علاوہ ہر مرض کے لئے دوا ہے۔
نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ
من لم یبرئه الحمد لم یبرئه شئی ۔ (اصول کافی جلد ۴ ص ۴۲۳ ح ۲۲)
جس کو سورہ حمد سے شفاء نہ ملے اسے کوئی چیز بھی شفاء نہیں دے سکتی۔
اسی وجہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔
لو قرئت الحمد علی میت سبعین مرة ثم ردت فیه الروح ما کان ذلک عجبا
اگر سورہ حمد کسی میت پر ستر مرتبہ پڑھی جائے اور اس کی روح پلٹ آئے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔
( ۵) تمام آسمانی کتب کی برکات وثواب۔
اس سورہ میں تمام آسمانی کتابوں کے جاننے اور پڑھنے کا ثواب رکھا گیا ہے جیسا کہ حدیث مین ہے جو بھی فاتحة الکتاب پڑھے گا ایسے ہی ہے جیسے ایک سو چار آسمانی کتابیں پڑھی ہوں۔
سورہ کے موضوعات۔
یہ سورہ قرآن مجید کے بنیادی نکا ت پر مشتمل ہے اس کے موضوعات کا احصاء وشمار نہایت مشکل ہے لہذا ہم چند اہم موضوعات کو فہرست وار ذکرکرتے ہیں۔ انکی تفصیل بعد کے صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔
( ۱) خداشناسی
( ۲) توحید و صفات الہی
( ۳) حمد الہی
( ۴) تربیت الہی
( ۵) جہان بینی
( ۶) وحدت کلمہ
( ۷) حاکمیت اعلی
( ۸) معاد
( ۹) عبادت
( ۱۰) استعانت
( ۱۱) خصوصی ہدایت
( ۱۲) دعا
( ۱۳) صراط مستقیم
( ۱۴) الہی نعمتیں
( ۱۵) مغضوبین کے راہ کی نفی
( ۱۶) ضالین کے راہ کی نفی
تفسیر آیات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سہارہ اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔
بسم الله الرحمن الرحیم میں مندرجہ ذیل چار موضوعات بیان ہوئے ہیں۔
۱ ۔خدا شناسی۔
اللہ کے نام سے شروع کرنا انتہائی بابرکت عمل ہے جو ہر کام کے احسن طریقہ پر انجام پانے کا موجب بنتا ہے پروردگار عالم اس آیت سے اپنے پاک کلام کا آغازکر کے یہ رسم قائم کر رہا ہے اور تربیت دے رہا ہے کسی بھی کام میں یاد خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو ہر کام میں خدا یاد رہے گا اس کا کوئی کام قانون خدا وندی کے خلاف نہ ہوگا اور اس کی زندگی گناہوں سے پاک رہے گی۔ جیساکہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و الہ وسلم کی معروف حدیث میں ہے۔
کل امر ذی با ل لم یزکر فیه اسم الله فهوابتر
کسی بھی اہم کام میں اگر خدا کے نام کا ذکر نہ ہو تو ناکامی ہو گی۔( بحار الانوار ج ۱۶ ، ب ۵۸)
اس حدیث نبوی کو حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے اور اس کے بعد
فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بھی کام انجام دینا چاہے تو لازم ہے کہ بسم اللہ کہے یعنی مین اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اورجوکام اللہ کے نام سے شروع ہو گا وہ مبارک ہو گا۔
نیز امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔
وینبغی الایتان بهاعندافتتاح کل امر عظیم او صغر لیبارک فیه ۔ (تفسیر عیاشی ج ۱ ، ص ۱۹)
بہتر یہ ہے کہ ہر چھوٹے یا بڑے کام کے آغاز پر بسم اللہ کہا جائے تاکہ وہ کام مبارک ہو۔
ب استعانت۔
اس آیت سے آغاز کر کے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مسلمان زندگی کے ہر قدم پر اللہ سے سہارا مانگیں تاکہ یہ احساس ہمیشہ قائم رہے کہ تنہا وہی برتر ذات ایسی ہے جو مدد دے سکتی ہے۔ہمیشہ اسی کے سامنے سرتسلیم خم کیاجائے اور اسی سے توفیق طلب کی جائے تاکہ بلند ہمتی سے امور انجام پائیں یہ عظیم مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تنہا قادر مطلق پر اعتماد کیا جائے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے۔
استعین علی اموری کلها بالله الذی لا تحق عباده الا له ۔( تفسیر الفرقان ج ۱ ، ص ۷۹)
میں اپنے تمام امور میں اسی خدا سے مدد اور سہارا طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی بھی بندگی کا استحقاق نہیں رکھتا۔
ج اسم خدا۔
خدا کا جامع ترین نام اللہ ہے اور یہی ایک نام خدا کے تمام اسماء و صفات کاجامع ہے اور اسی لیئے بسم اللہ کہا جاتاہے بسم الخالق، یا بسم الرازق نہیں کہا جاتا،چونکہ بقیہ تمام اسماء وصفات کو اسی
کلمہ اللہ کی صفت کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے دوسرے نام کسی ایک کمال اور صفت کو منعکس ہیں مثال کے طور پر غفور و رحیم سے خدا کی بخشش و رحمت کی طرف اشارہ ہے۔
لہذا جس طرح خدا اپنی ذات میں واحد ہے اسی طرح اپنے نام اللہ میں بھی
واحد ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی کا ذکر کیا گیا ہے یعنی ۲۶۹۷ دفعہ ذکر کیاگیا ہے۔
حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فر مان ہے۔
الله اعظم اسماء من اسماء الله وهوالاسم الذی لا ینبغی ان یسمی به غیر الله لم یتسم به مخلوق ۔( وہی ماخذ ص ۸۲ ۔تفسیر صافی ج ۱ ، ص ۸۱)
اللہ خدا کے ناموں میں سب سے عظیم نام ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی اس نام سے موسوم نہیں ہو سکتا اور مخلوق بھی یہ نام نہیں رکھ سکتی۔
جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے
والتسمیته فی اول کل سورة آیة منها وانما کان یعرف انقضاء السورةبنزولها ابتداء للاخری
بسم اللہ ہر سورہ کی ابتدائی آیت ہے اور ہر سورہ کی ابتداء اور انتہاء اسی آیت کے نزول سے معلوم ہوتی ہے (منہج الصادیقین ج ۱ ،ص ۹۹)
( ۶) نماز میں مکرر۔
یہ آیت ہر نماز میں لازمی طور پر کم از کم چار مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس طرح فقط فرض نمازوں میں ہی ۲۰ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور روزانہ کی نافلہ نمازوں میں کم از کم ۶۸ مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔
پہلی آیت کے فضائل
اس آیت کے فضائل کا احصی قوت بشری سے باہر ہے بہرحال مندرجہ ذیل تین فضائل ملاحظہ فرمائیں
( ۱) تمام اعمال پر غالب ہے۔
اس آیت میں ذات خداوندی کے تین ایسے باعظمت نام بیان ہوئے ہیں جو تمام ناموں اور صفات کے جامع ہیں اور یہ تین نام امت مسلمہ کی نجات کے موجب بن جائیں گے اور یہ نام بنی آدم کے تمام اعمال پر بھاری ہیں جیسا کہ حدیث نبوی میں وارد ہوا ہے کہ آپ(ص) نے فرمایا۔
جب میری امت کو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیئے لایا جائے گا اور ان کے اعمال کو میزان میں تولاجائے گا تو ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر غالب آجائیں گی۔
انبیاء سلف کی امتیں سوال کریں گی پیغمبراسلام کی امت کے اعمال بہت کم تھے لیکن ان کی نیکیوں کا پلڑا کیوں بھاری ہے تو انبیاء سلف جواب دیں گے۔کیونکہ یہ امت اپنے کلام کا آغاز خالق متعال کے تین ناموں سے کرتی تھی۔ اور اگر یہی تین نام میزان کے ایک پلڑے پر رکھے جائیں۔ بنی آدم کے تمام حسنات وسیئات دوسرے پلڑے پر رکھے جائیں تو یہ پلڑا بھاری ہوگا اور وہ تین نام بسم اللہ، الرحمن،الرحیم ہیں
( ۲) شیطان کی دوری کا موجب۔
جس کام میں بھی یہ آیت پڑھی جائے شیطان اس کام میں شریک نہیں ہوتامثلا کھانا کھاتے وقت اس آیت کے پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اہلیبیت اطہار علیہم السلام سے روایت منقول ہے۔جو شخص کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک نہین ہوتا اور اگر کوئی شخص بسم اللہ کے بغیر کھانا کھائے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔
( ۳) گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔
یہ آیت آخرت میں بھی نجات کی موجب ہے۔ اور دنیا میں بھی اس آیت کے تکرار کرنے سے جو عادت بن جاتی ہے یہی عادت آخرت میں گناہوں کے محو ہونے اور جہنم کی آگ سے دوری کا باعث ہو گی۔ جیسا کہ پیغمبر عظیم الشان اسلام کی ان تین روایتوں میں وارد ہو ہے کہ۔
قیامت کے دن جب انسان کو حساب کتاب کے لیئے لا یا جائے گا اوراس کا اعمال نامہ گناہوں اور برائیوں سے پر ہو گا جب یہ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنی دنیوی عادت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان پر جاری کرے گا تو وہ اعمال نامہ اسے سفید نطر آ ئے گا۔ فرشتوں سے سوال کرے گا کہ میرا اعمال نامہ تو سفید ہے اور اس میں کچھ نہیں لکھا ہو اتو وہ جواب دیں گے بسم اللہ کی برکت سے تمام سیئات و خطیئات محو ہو گئے ہیں۔( منہج الصادیقین ج ۱ ص ۱۰۱)
دوسری روایت، اور فرمایا جب قیامت کے دن کسی بندے کو حکم دیا جائے گا کہ وہ دوزخ میں جائے تو جب وہ کنارے پر پہنچے گا اوربسم الله الرحمن الرحیم کہے گا تو جہنم کی آگ اس سے ۷۰ ھزار سال دور ہو جائے گی۔( ۲)
تیسری روایت
انه اذا قال المعلم للصبی قل بسم الله الرحمن الرحیم فقال الصبی بسم الله الرحمن الرحیم کتب الله برائته لا بویه و برائته للمعلم
نیز فرمایا جب استاد بچے سے کہتا ہے کہبسم الله الرحمن الرحیم کہو اور وہ کہےبسم الله الرحمن الرحیم تو خداوند متعال، اس کے والدین اور استاد کو بخش دیتا ہے۔( جامع الاخبار،بصائر ج ۱ ص ۲۲۳ مجمع البیان ج ۱ ص ۹۰)
(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ )
تمام حمد وثناء اس خدا کے لیئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل چار موضوعات ہیں
( ۱) حمد الہی
( ۲) تربیت الہی
( ۳) جہاں بینی
( ۴) وحدت کلمہ۔
( ۱) الف حمد الہی
اختصاص حمد صرف خدا کے ساتھ ہے۔ خالق متعال الحمدللہ رب العالمین کہ کر اس حقیقت کو بشریت کے لیئے واضع اور آشکار کر رہا ہے کہ حمد الہی کا مفہوم اور اس کی حقیقت، ذات مقدس الہی سے مختص ہے کیونکہ اس کی ذات کمال مطلق ہے جو تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔
لہذا وہ ذاتی لیاقت رکھتا ہے کہ ہر قسم کی حمد صرف اسی سے مختص ہو حمد اختیاری عمل پر ہوتی ہے اور رب العالمین کے پاس اختیا رکل ہے لہذا حقیقی حمد کا استحقاق بھی وہی رکھتا ہے بلکہ وہ اپنی ذات،صفات،اور افعال کے حوالے سے ہر قسم کی حمد و تعریف کا حقدار ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسی تعریف کا حقدار نہیں ہے ہاں وہ خود کسی کو محمد بنا دے تو اور بات ہے۔
ب۔تعلیم حمد
بندوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کی معرفت حاصل کریں اور رب العالمین کی بے شمار اور لا متناہی نعمتیں ہی ہمیں اس کی شناخت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کیونکہ جب کسی انسان کو نعمت حاصل ہو تو وہ فطری طور پر عطا کرنے والے کا شکر گزار ہوتا ہے شکریے کا حق ادا کرنے کے لیئے منعم اور محسن کی پہچان ضروری ہے۔
جب ہمیں پہچان ہو جائے کہ خدا کی ذات ہی تمام نعمتوں اور رحمتوں کو عطا کرنے والی ہے توشکر ادا کرنے کا طریقہ سکھا رہی ہے کہ جب بھی تم میری عظیم نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہوتو میری حمد کرو اور جب حمد کرنا مقصود ہو تو کہو الحمد للہ رب العالمین اس طرح میری مکمل ترین حمد ہو جائے گی۔ اگر خداوند متعال حمدوشکر کی تعلیم کر دے تو انسان ذاتی طور پر اس کمال مطلق کی تعریف کے قابل نہیں ہو سکتا۔
( ۲) تربیت الہی:۔
الف خدائی پرورش
خداوند متعال ” رب العالمین “ سے یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تمام جہانوں موجودات کی تخلیق اور ایجاد کرنے والا قادر مطلق ہے اور چونکہ اسی نے وجود بخشا ہے لہذا وہی بہتر پرورش کر سکتا ہے وہی تمام موجودات کا رب اور پالنے والا ہے۔کائنات وجود پانے کے بعد بھی ہمیشہ رب العالمین کی محتاج ہے پرورش اور رشد کے تمام عوامل اسی نے پیدا کیے ہیں۔تربیت اور پرورش دو قسم کی ہوتی ہے۔
( ۱) تکوینی تربیت
( ۲) تشریعی تربیت
ہمارا خالق دونوں لحاظ سے رب ہے ہماری خلقت میں بھی ہمیں پالنے والا وہی ہے اور تعلیم وتربیت میں بھی وہی رب ہے اور راہ دکھلاتا ہے۔اور تمام مخلوقات کے تکامل اور ترقی کے تمام وسائل کا انتظام اسی نے کیا ہے اور پھر ان وسائل کے استعمال کا طریقہ بھی اسی نے سکھایا ہے۔
خالق متعال نے نہ صرف طبعیت اور جسمانی تربیت کا مکمل انتظام کیا ہے بلکہ اپنی مخلوق ناطقہ کے لیئے روحانی اور اخلاقی تربیت کا بھی پورا اہتمام فرمایا ہے۔اس امر کے لیئے فطرت بشری میں ھدایت کی راہ پرچلنے کا جوہر رکھا ہے اور صحیح راہ کی شناخت کے لیئے عقل جیسی ممتاز نعمت عطا فرمائی ہے۔ چونکہ بشریت کو ارتقائی منازل طے کرنے کے لیئے راہنما کی ضرورت تھی تو اس کا انتظام انبیاء الہی کو ہدایت بشری کے لیے مبعوث فرمایا اور آسمانی کتب نازل فرمائی جس سے رشد وتکامل کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔
(ب) دیگر ارباب کی نفی
خالق مطلق چونکہ ہر چیز کا مالک ہے اور ان کی تربیت بھی صرف وہی کر سکتا ہے اور رب حقیقی اور مطلق بھی وہی ہے تو کسی اور کا رب ہونا یا تربیت میں شریک ہونا اس حقیقت کے منافی ہے۔اس آیت کے ذریعہ کائنات کی ہر چیز کی تربیت کو صرف خدا وند متعال سے مختص کر دیا گیا ہے اور بقیہ تمام تخیلی ارباب کی نفی کر دی گئی ہے اور اس طرح توحید ویگانگی کی اساسی وجہ بیان کر دی ہے۔
( ۳) جہان بینی
عالم سے مراد وہ جہان ہے جو ایک شمسی نظام اور اس میں موجود تمام سیارات سے تشکیل پاتا ہے سا ئنسی ترقی سے انسان نے بہت سے کہکشاں اور ہر کہکشاں میں متعددشمسی نظام اور ہر شمسی نظام میں موجود مختلف سیاروں کا پتہ چلا لیا ہے البتہ سائنس کی ترقی سے بہت پہلے ہمارے معصومین علیہم ا لسلام نے اس کی خبر دے رکھی تھی جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ ا لسلام کا فرمان ہے۔
ان الله قد خلق الف الف آدم
بے شک اللہ نے ہزار ہزار (ایک ملین )جہان پیدا کیے اور ہزار ہزارآدم کو خلق فرمایاہے۔
اس سے عالمین یعنی بہت سے جہان کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات میں جتنے عالم ہیں ان تمام کا خالق اور رب صرف خدا کی ذات ہے۔
عالمین کے تذکرے سے مراد یہ ہے کائنات کی وسعت،جہانوں کے تعدد،ان کی خلقت اور ان کی تربیت پر غور کیا جائے اور ایک جہان بینی اور کلی نظر پیداہو کہ وہ ذات بر تر و جامع کمالات ہے اس کی خالقیت اتنی وسعت رکھتی ہے کہ انسان ان کے جزئیات کو نہیں پا سکتا اور صرف تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ تخلیق کے بعد ان کی تربیت کر نے والی ذات بھی وہی ہے۔
یعنی وہ ذات کائنات اور اس میں موجود تمام جہانوں،نظاموں،سیاروں ،آسمانوں،زمینوں،جمادات،نباتات،حیوانات اور ملائک،جن اور انس نیز دیگر مخلوقات کی ان کے مناسب حال تدریجی طور پر تربیت کرتا ہے اور کمال کی منزل تک پہنچاتی ہے۔
اس سے عالمین کی تربیت پر ایک کلی نظر پیدا ہوتی ہے کہ کتنا بڑا اور پھیلا ہوا عمل ہے کہ خالق کے علاوہ اس کام کو کوئی انجام نہیں دے سکتا اسی لیے تمام حمد اور تعریفوں کو اسی ذٓت سے مخصوص کر نا ضروری ہے۔
( ۴) وحدت کلمہ
جب ذات،صفات،خالقیت اور تربیت میں وحدانیت الہی معلوم ہو گئی اور ہر روز نئے خدا اور ہر کام کے لیے علیحدہ علیحدہ خدا نیز قبلہ کا الگ الگ خدا ہو نے کی نفی کر دے گئی اور یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آگئی کہ وہ اس ایک جہان ہی خالق نہیں بلکہ وہ ایسے بہت سے جہانوں کا خالق،مدبر اور پالنے والا ہے۔
اس سے ایک طرف سے ہر طرح کے شرکت کا سد باب کیا اور دوسری طرف اتحاد عالمی کی ایک مستحکم بنیاد قائم کر دی تاکہ سب لوگ وحدت کلمہ کے ساتھ ترقی وکمال کے مدارج طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچیں۔
اگرچہ ابھی تک انسانیت تہذیب وتمدن کین انتہائی ترقی کے باوجود اس بنیاد پر کوئی مضبوط عمارت قائم نہیں کر سکی اور جب تک اس اخوات کا سنگ بنیاد رکھنے والے دین اسلام اور کتاب (قرآن ) کو عمومی طور پر تسلیم نہ کر لیا جائے اس وقت تک یہ عظیم مقصد حاصل نہ ہو گا۔
اس سلسلے میں قرآن کا وعدہ ہے کہ
( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِۚ )
تا کہ اس دین کو ہر دین پر غلبہ عطاء کرے۔
یہ وعدہ حتمی ہے جو پورا ہو کر رہے گا جب حضرت حجت کا ظہور ہو گا اور دنیا کی تمام بے تابیاں اور پریشانیاں اس وقت ختم ہو جائیں گی۔اور ایمان۔نظم اور اتحاد عالم کی نہایت ہی شاندار عمارت بنے گی اور دنیا کے مضطربانہ اٹھتے ہوئے قدم آخر میں اس منزل پر پہنچ کر دم لیں گے اور اطمینان اور سکون کی فضا قائم ہو جائے گی۔
خصوصیات آیت
اس آیت کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔
( ۱) تمام انوع حمد کی جامع۔
یہ آیت حمدکی تمام انوع و مراتب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور خدا وند متعال کے جتنے اوصاف کمالات ہیں ہر کمال پر وہ لائق حمد ہے اس کی جتنی نعمتیں اور آثار ہیں سب کے سب حمد الہی کے موارد ہیں۔ کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ جس طرح وہ حمد کا حقدار ہے اس طرح حمد الہی بجا لائے اور اس آیت میں خدا کی جامع حمد ہے جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فر مایا۔
اگر خدا وند متعال میری سواری مجھے لوٹادے تو میں اس کی ایسی حمد کروں گا جو اسے پسند آئے گی سواری مل گئے اور اس پر سوار ہوئے تو آسمان کی طرف سر اٹھاکر فرمایا الحمد للہ اور اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا اور پھر فرمایا۔
ما ترکت ولا ابقیت شئا جعلت جمیع انوع المحامد لله عزو جل فما من الا و هو داخل فی ما قلت
میں نے خدا کی حمد سے کسی قسم کی چیز کو نہیں چھوڑاحمد کی اقسام اس جملے میں داخل ہیں۔
ہم تمام انوع حمد کی وضاحت میں چند جملے دعا افتتاح کے بیان کرتے ہیں امام زمانہ (عج)نے اپنے خاص نائب ابو جعفر محمد ابن عثمان کو تعلیم فرمائی تھی۔
الحمد لله بجمیع محامده کلها، علی جمیع نعمه کلهاالحمد لله الذی لا مضاد له فی ملکه،ولاس منازع له امرهالحمد لله الذی لا شریک له فی خلقه ولا شبیه له فی عطمته الحمد لله الفا شی فی الخلق امره وحمده،الظاهر بالکرم مجده،الباسط بالحوریده،الذی لا تنقض خزائنه ولا تزید کثرة العطاء الا حور ا وکرما انه هو العزیز الوهاب
حمد اللہ ہی کے لئے ہے اس کی تمام خوبیاں اور ساری نعمتوں کے ساتھ، حمد اس اللہ کے لئے ہے جس کی افرینش میں کئی اس کا ساجھی نہیں ہے اور اس کی بڑائی میں کوئی اس جیسا نہیں ہے،حمد اس اللہ کے لئے ہے جس کا حکمپوری مخلوق میں آشکار ہے اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہے۔یہ وہی ہے جس کے خزانے کم نہیں ہوتے اور کثرت کے ساتھ عطا کرنے میں اس کی بخشش و سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ وہ زبردست عطا کرنے والا ہے۔بہرحال پوری دعا ہی پروردگار عالم کی حمد پر مشتمل ہے اور ہر قسم کی حمد کو انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔
( ۲) نماز میں الحمدللہ رب عالمین پڑھنا
اس آیت کا حمد کے بعد نماز میں پڑھنا مستحب ہے یہ اس آیت کی خصوصیت ہے چونکہ باجماعت نماز میں سورہ حمد اور بعد والی سورہ کا پڑھنا صرف پیشنماز کے لیے ضروری ہوتا ہے اور مقتدی صرف سنتا ہے اور جب پیشنماز سورہ حمد کی قر ائت ختم کرتا ہے تو مقتدی کے لیے مستحب ہے وہ کہے الحمد للہ ر ب العالمین۔
جیسا امام جعفر صادق (ع) کا ارشاد ہے
اذا کنت خلف امام ففرغ من قرائةالفاتحهفقل انت من خلفه الحمد لله ر ب العالمین
جب آپ با جماعت نماز پڑھیں اور پیشنماز سورہ فاتحہ پڑھ چکیں تو کہیں الحمد للہ رب العالمین۔
اسی طرح فرادی نماز میں بھی حمد کے بعد اس آیت کو پڑھنا سنت ہے جیسا کہ امام علیہ ا لسلام کا اس بارے میں ارشاد ہے۔
فاذا قرائات الفاتحة ففرغ من قرائتها و انت فی الصلوة فقل الحمد لله رب العالمین
جب آپ سورہ الفاتحہ کو نماز میں قرائت کریں تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔البتہ آئمہ معصومین علیہمالسلام کے فرامین کے مطابق سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔
فضائل آیت دوم
شکر نعمت
خدا وند متعال کی بے پناہ نعمتوں پر شکر واجب ہے اور شکر الہی ادا کرنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں چونکہ کائنات کی وسعتوں میں موجود بے شمار نعمتوں کا وہ احصاء کرنے سے قاصر ہے تو پھر کیسے شکر ادا کرے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
ماانعم اللہ علی عبد بنعمة صغرت و کبرت فقال الحمد للہ الا ادی شکرھا۔( البیان ص ۴۵۵ اصول باب الشکر ص ۳۵۶)
خدا وند متعال نے کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی نعمت اپنے بندے کو عطا نہیں فرمائی
( الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ)
وہ سب کو فیض پہنچانے والا بڑامہربان ہے۔
اس آیت کی تفسیر پہلے بیان ہوچکی ہے لیکن ایک نکتہ کا یہاں ذکر کرنا مناسب ہے کہ رحمن سے مراد دنیا میں اسکی رحمت ہے اور رحیم سے اسکی اخروی رحمت مراد ہے۔
اسکا واضح برہان یہ ہے کہ لفظرحمانالحمدالله رب العالمین کیساتھ متصل ہے اور یہ دنیا میں اسکے رحمن ہونے کو بتاتا ہے اور لفظرحیم مالک یوم الدین کیساتھ متصل ہے اور یہ اسکی اخروی رحمت پر دلالت کرتا ہے، یہ دونوں صفات منشاء الہی کے فیضوض و برکات پر مشتمل ہے۔
خصوصیات۔
سب سے پہلا تکرار
یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے جس کے تمام الفاظبسم الله میں ذکر ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی بے فائدہ تکرار نہیں ہوا بلکہ خاص معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کیلئے تکراری الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور یہاں تکرار کی مندرجہ وجوہات ہیں۔
الف:استحقاق حمد
بسم اللہ میں رحمن اور رحیم کا تذکرہ امداد طلب کرنے کے ذیل میں تھا اور یہاں استحقاق حمد کے لیئے ہے کیونکہ وہ ذات سر چشمہ رحمت ہے اور اس نے ہمیں اپنی رحمت سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لہذا وہ ذات حق رکھتی ہے کہ اس کی حمد کی جائے گرچہ رحمت کے علاوہ اس کی عالمی تربیت اور دیگر تمام اوصاف کمال بھی اسی ذات کو مستحق حق گردانتی ہیں۔
ب:۔ تربیت کی دلیل۔
یہاں رحمن اور رحیم میں خدائی تربیت کی دلیل موجود ہے کیونکہ وہی کائنات کا خالق اور رب ہے لیکن یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ تخلیق اور تربیت کس بنیاد پر ہے؟ یہ واضع حقیقت ہے کہ وہ ذات ہر چیز سے بے نیاز ہے اور عالمین کی تربیت اپنی ضرورت کے لیئے نہیں کرتا۔
اس کی وسیع اور دائمی رحمت کا تقاضہ ہے کہ سب کو فیض پہنچائے اور اپنے لطف وکرم اور رحم سے ان کی تربیت کرے اور انہیں رشد وکمال کے راستے پر چلائے اور آخرت میں بھی اپنے دامن عفو ورحمت میں جگہ عطاء فرمائے ہماری تربیت اور بخشش سے اس ذات کو ذاتا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں نعمتیں عطاء فرماتا ہے اوررحمت کی وجہ سے ہماری تربیت کرتا ہے۔
(ج)حقیقی مالک اور مجازی مالک میں فرق
دینوی مالک کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں بلکہ حقیقی اور اصلی مالک ان کو وجود اور زندگی عطاکرنے والا پروردگار ہے لیکن یہ دنیاوی مالک اپنی اس جھوٹی مالکیت کو جتلانے کے لئے اور اپنی انا اور خواہشات نفسانی کے تحت پر قسم کے ظلم و ستم،قتل و غارت اور بے راہ روی کو اپناتے ہیں۔
لہذا رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو لانا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ حقیقی مالک ہونے کے باوجود اپنے بندوں پر مہربانی ولطف و کرم کرتا ہے،اور اپنی رحمت کے سائے میں تو بہ کرنے والے تمام خطاکاروں کو بخشش دیتا ہے۔اسی لئے ارشاد الہی ہے۔
قل یا عبادی الذین اسر فو ا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمتہ اللہ ان اللہ تغفرالذنوب جمیعا ھو والغفورالرحیم پیغمبر (ص) آپ پیغام پہنچا سیجیے کہ اے میر ے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ یقینا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
( مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ )
وہ خدا روز جزا کا ما لک ہے۔
حاکمیت اعلی۔
الف :۔
دنیا میں اقتدار اعلی خداوند عالم زمان ومکان کی تمام حالتوں پر حاکم ہے۔اور اس کی حاکمیت تمام جہانوں پر محیط ہے۔ہر چیز پر اس کا تسلط اور احاطہ ہے اور جہاں ہستی کے لیئے وہی ذات ہی حقیقی حاکم ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور علی الاطلاق وہی حاکم اعلی ہے خداوندمتعال کی تربیت اور پرورش فقط اس دنیا تک محدود نہیں ہے۔
ب :۔
آخرت میں اقتدار اعلی، یہاں خداوندمتعال مالک یوم الدین کہ کر روز جزا کی حاکمیت فقط اپنی ذات کے ساتھ ہی مخصوص کر رہا ہے اور آج تک کسی نے اس دن کی حاکمیت کا دعوی نہیں کیا۔ جیسا کہ اس دنیا میں بھی لوگوں کی تربیت اور تدبیر کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح آخرت کی تدبیر اور حساب کتاب بھی اسی ذات کے ہاتھ میں ہوگا جیسا کہ خداوندمتعال ارشاد فرماتا ہے۔
لمن الملک الیوم لله واحد القهار ۔
آج کس کی حکومت ہے (جواب دیا جائے ) صرف خدا یگانہ اور قہار کی حکمرانی ہے۔
معاد
الف:۔ آخرت پر ایمان
خلاق متعال کی ربوبیت اور رحمانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ جزا اور سزا کا ایک مکمل نظام ہو،خدا نے انسان کو ترقی اور کمال کے مراحل طے کرنے کے لیئے راہ دکھلائے اس کی تربیت کا انتظام کیا اسے شعور اور اختیا رعطا فرمایا اب اگر انسان صحیح راہ کا انتخاب کرے جو کہ اطاعت اور ایمان ہے،تو وہ جزا پائے گا۔
لیکن اگر بری راہ یعنی کفر ومعصیت کو اختیار کرے تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ اس آیت کے ذریعے خداوندمتعال انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمام لوگوں کا پلٹنا اسی کیطرف ہے اور یہی معاد ہے۔
ان کے تمام اعمال وامور،قیامت کے دن خدا وند متعال کی حکومت اور سلطنت میں پیش کیے جائیں گے اور وہیں سزا وجزا کا تعین ہو گا،تو اسی بنا پر فقط اسی سے امید رکھنی چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے اور اس ذات کی مخالفت اور نافرمانی سے بچنا چاہیے۔معاد پر ایمان انسان کو غلط راستے سے بچاتا ہے اور اس کے کردار اور اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے۔اس بنا پر دین کی ایک بنیادی اصل معاد اور قیامت ہے۔
(ب)روز حساب
قرآن مجید میں عالم آخرت کو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیاہے،یوم الدین،یوم حساب اور دوسری تعبیریں استعمال ہوئی ہیں اور یوم دین سے مراد روز حساب ہے جیسا کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مالک یوم الدین سے کیا مراد ہے۔آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مرادیوم الحساب ہے۔
یہ وہ دن ہے جس دن تمام پوشیدہ حقائق واضع ہو جائیں گے اور تمام الہی وعدے پورے ہو جائیں گے اور ہر چھوٹے بڑے عمل کو عدالت الہی کے ترازو میں پرکھا جائے گا ہر شخص کی نیکیوں اور اچھائیوں،اسی طرح گناہوں اور برائیوں کاحساب وکتاب ہو گا۔
حاکم مطلق کی بارگاہ میں ہر ظلم وذیادتی کے خلاف شکایت کی جائے اور حقدار کو اس کا حق ملے گا اور کسی کو مایوسی نہ ہو گی اور ہر عمل کا عدل وانصاف کے ساتھ حساب ہو گا جب نیک اور برے افراد علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو ان کا اجر وسزا معین ہو گا اور جو اجر پانے والے ہو نگے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو لوگ سزا اورعذاب کے مستحق ہونگے انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔
( إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ )
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں
( ۱) عبادت
الف:۔حق کی ادائیگی، گزشتہ آیات میں اوصاف خداوندی کا تذکرہ ہو ہے اس ذات(خدا وندی) کی شناخت اور معرفت کے مراحل سے گزرتے ہوئے یہ علم ہوا کہ وہ ذات ہماری خلقت کے بعد،ہماری تربیت اور ہدایت کے تمام اسباب مہیا کرتی ہے،اس دنیا میں اس کی رحمت اور لطف وکرم ہم پر سایہ فگن ہے اور آخرت میں اس کی حاکمیت مطلقہ کے باوجود اس کی رحمت مومنین کے شامل حال ہے۔
اس وجہ سے برتروبالا ذات کے بہت سے حقوق ہماری گردن پر ہیں اور جن کی صحیح معنوں میں ادائیگی ہمارے بس میں نہیں ہے،ان میں سے ایک منعم کا شکر ادا کرنا ہے،شکر کو حمد خداوندی کے ذریعہ ادا کیا جاتا ہے اسی طرح ایک حق یہ کہ ہم اپنے رحیم وکریم مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں اس کا واضع مظہر عبادت خداوندی ہے۔
مزید یہ کہ جب کسی سے کوئی حاجت طلب کی جائے تو اس کا لاذمہ یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور جو انسان اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا وہ اس کی عنایت کا حق دار نہیں ہوتا۔اس مقام پر بیان ہونے والی آیات بتاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح بارگاہ خداوندی سے حاجات طلب کرنی ہیں ان آیات میں اس کے حق کی ادائیگی کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے حاجات طلب کرتے ہیں۔
(ب)وہی ذات لائق عبادت ہے
خداوندمتعال بے پناہ کمالات کا مالک ہے اور اس کی ذات کمال مطلق ہے اور اس کی ہر صفت بھی کمال ہی کمال ہے،وہی رب بھی ہے اور مالک بھی اسی لیئے وہ ذات بندگی اور پرستش کی حق دار ہے یعنی اس کی عبادت کا موجب صرف اور صرف اس کی ذات ہے کوئی اور شیء نہیں ہے۔
اسی لیئے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔
،الهی وجدتک اهلا للعباده فعبدتک
بارالہا میں نے تجھے بندگی اور عبادت کے لائق پایا،اسی لیئے تیری عبادت کرتا ہوں۔
جب وہ ذات ہی بندگی کی لیاقت رکھتی ہے تو پھر عبادت بھی فقط اسی کی قربت کی نیت سے ہونی چاہیے۔
(ج)انحصار بندگی
ان آیات سے جب اس ذات کا عبادت کے لائق ہونا واضع ہو گیا تو اب ایک اور موضع کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عبادت فقط اسی ذات میں منحصر ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
عقل وفطرت کا بھی یہی تقاضا ہے جب وہی ذات خالق کل اور مالک حقیقی ہے تو پھر صرف اسی کی اطاعت کی جائے اور جب ہم اس کے بندے ہیں تو معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے۔لہذا خداوندمتعال کے علاوہ کسی کی عبادت سلب آزادی اور غلامی کے مترادف ہے لیکن اگر انسان دوسروں کی عبودیت اور نفس امارہ سے آزاد ہونا چاہے اور فقط اور فقط خدا کی عبادت پر انحصار کرے تو اس کا مستحق ہوگا کہ خود کو خدا کا بندہ کہے کیونکہ اس کی بندگی میں عزت ہے۔
دنیاوی طاقتوں اور طاغوتوں کے سامنے جھکنے میں ذلت ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ آیت صاحبان ایمان کے لیئے روحی لحاظ سے علو کو پیش کرتی ہے۔اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور اپنی احتیاج اسی کے سامنے پیش کرے اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اسی کے علاوہ کسی پر اعتماد اور توکل نہ کرے کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دے اور خدا کی سلطنت کے مقابلہ میں کسی کی حاکمیت کو محبوب نہ جانے کیونکہ خداوندمتعال کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ
( وَ قَضي رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ )
اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔
دین کا حکم بھی یہی ہے کہ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شرک در عبادت واطاعت بھی انسان کو دائرہ توحید سے خارج کر دیتا ہے۔ نیز اس مطلب کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز خداوندمتعال کی مطیع ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے اس مقام پر خداارشاد فرماتا ہے۔
( إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا )
زمین و آسمان میں ہر چیز خدا کا بندا اور (اسکی) فرمانبردار ہے۔
خداوندمتعال کی تمام مخلوقات میں صرف انسان اور جن ہی اس کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں حالانکہ انہیں عبادت کے لیئے خلق کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد خدا و ندی ہے۔
( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )
جن و انس کو صرف عبادت کے لیئے پیدا کیا گیا ہے۔
المختصر یہاں پر جب یہ واضع ہو گیا کہ عبادت و پرستش صرف ذات الہی کے ساتھ مختص ہے اور غیر اللہ کی عبادت جس صورت اور جس طرز فکر سے ہو،شرک ہے کیونکہ جو شخص غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اسے معبود سمجھ بیٹھتا ہے اور جو معبود حقیقی کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھے وہ کافر اور مشرک ہے۔خدا پرست اوراھل توحید اسی عقیدہ کی وجہ سے مشرک اور غیر موحد لوگوں سے ممتاز ہیں۔
خضوع و خشوع
اس بات میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ مخلوق کو خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ خضوع و خشوع بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ ذات اس قدر عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر چیز صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر اپنی ناچیزی کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی ذات اور بندگی کا اظہار ہمارے لئے ضروری ہے۔
یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس پر عقل اور شریعت دونوں شاہد ہیں اس کے علاوہ کسی استدلال اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔عبادات میں خضوع وخشوع انسان کے مقام کی بلندی کاموجب بنتا ہے بندہ کی اسی میں عزت ہے کہ بندگی میں کمال پیدا کرے اور یہ کمال صرف خشوع وخضوع میں مضمر ہے۔
اس سے بڑا فخر اور بڑی عزت کوئی نہیں ہے کہ انسان غنی مطلق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوجیسا کہ حضرت امیر علیہ ا لسلام ارشاد فرماتے ہیں۔
الهی کفانی فخراان تکون لی ربا وکفانی عزا ان کون لک عبدا
پروردگار امیرے لئے صرف یہ بہت بڑا فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میرے لئے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔
ھ۔ خدا کی مر ضی کے مطابق عبادت
عبادت خدا وند متعال کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے،اور عبادت تقرب خدا وندی کے لئے،ہو تی ہے تو اسے اس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے خواہ خاص حکم ہو یا عام،اسے اپنے وہم وگمان اور مرضی کے مطابق بجا لانا چاہیے، کیونکہ خدا وند متعال تمام مصالح اور نقصانات سے آگاہ ہے اور انسانی عقل اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔
لہذا عبادت اور اطاعت کا صحیح طریقہ وہی ذات معین کر سکتی ہے اور اس کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی عبادت خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی بلکہ وہ ھو وھوس اور تخیل کی عبادت ہوگی۔
اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔
قال ابلیس :رباعفنی من السجودلآدم وانا اعبدک عبادة لا یعبدکها ملک مقرب ولابنیمرس فقال جل جلاله لا حاجة لی فی عبادتک انه اعبادتی من حیث ارید لامن حیث ترید
جب شیطان نے کہا بارالہا اگر مجھے آدم کو سجدہ کرنے سے معا ف کر دو تو میں تمہاری ایسی عبادت کروں گا جو کسی مقرب فرشتے اور مرسل نبی نے نہ کی ہوگی۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے فرمایا مجھے تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے بلکہ میری عبادت وہ ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو نہ کہ تیری مر ضی کے مطابق ہو۔
عبادات کی شرائط اور اقسام
خدا کی عبادت تبھی خالص ہو سکتی جب انسان اس کی ذات پر یقین کامل رکھتا ہو اور دوسرے تمام اسلامی اصولوں کا بھی معترف ہو کیونکہ عبادت ان اصولوں کی فرع ہے خدا وند متعال کی حمد وثنا،اس کی ذات کی عظمت اور یوم قیامت کے حساب کتاب جیسے مفاہیم جب انسان کی روح میں سرائیت کر جائیں تو یہ انسان کے عقیدے کے استحکام کا موجب ہیں۔
عبادت کی تکمیل بھی اس مشروط ہے کہ انسان معرفت پروردگار،عقیدہ کی دوستی۔اخلاص و ایمان سے عبادت کو بجالائے اور مقام بندگی میں خود کو اس کے حضورمیں سمجھے اور خدا کا خالص بندہ
کر اس کی بار گاہ میں جائے اور دنیا،لذات، خواہشات وشہوات اور دنیا داروں سے بریدہ ہو کر فقط اس کی عبادت کرے۔
عبادت مختلف طرح سے کی جاتی ہے
( ۱) کبھی انسا ن اس لئے عبادت کرتا ہے تاکہ اسے اجر اور ثوا ب ملے یعنی خداکے احسان اور وعدہ کے لالچ میں عبادت کرتا ہے۔
جیسا کہ خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے۔
( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ )
جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہونگی
اور فرمایا۔
( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ )
اللہ نے صاحبان ایمان، نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور اجرعظیم ہے۔
( ۲) کبھی انسان جہنم کے عقاب و عذاب کے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ خدا وند عالم نے فرمایا۔
( إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )
اگر میں اپنے پروردگار کی نا فرمانی کروں،تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔
( ۳) کبھی انسان اللہ کی عبا ت اور پرستش اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہی لائق عبادت اور یہ عبادت اولیاء خدا کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ حضرت امیرالمومنین علیہ ا لسلا م ارشاد فرماتے ہیں
الهی ما عبداک خوفا من عقابک ولا طمعا فی ثوابک ولکن وحدئک اهلا لعبادة معبدئک
خدایا میری عبادت تیرے عذاب کے خوف،اور ثواب کے طمع و لالچ میں نہیں ہے بلکہ میں تیری عبادت اس لئے کرتا ہوں کہ تو اس کے لائق ہے۔
ہر شخص اپنی معرفت اور ظرف کے مطابق عبادت کرتا ہے جتنی معرفت ہو اتنی ہی عبادت کی تین قسمیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔
قوم عبدوالله عزوجل خوفا فتلک عبادة العبید،وقوم عبده الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادة الاجراء و قوم عبد و الله عز وجل حتی له فتلک عبادة الاجراره هی افضل العبادة ۔
ایک قوم اللہ تبارک وتعالی کی عبادت جہنم کے خوف کی وجہ کرتی ہے یہ غلاموں کی سی عبادت ہے اور ایک گروہ اللہ کی عبادت ثواب حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے اور یہ اجیر کی عبادت کار وباری عبادت ہے۔ ایک قوم خدا کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں یہی احرار لوگوں کی عبادت ہے اور یہی افضل ترین عبادت بھی ہے۔
اور جو لوگ اللہ کی محبت میں عبادت بجا لاتے ہیں ان کے لئے خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے۔
( قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبکُمُ اللهُ )
اے رسول کہہ دیجیے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔
احتیاج عبد
انسان ایک محتاج موجود ہے اور بذات خود کسی طرح کی کوئی احتیاج نہیں رکھتا ہے۔انسان نے اپنا وجود بھی اسی ذات سے حاصل کیاہے اور اس ذات کے علاوہ کوئی بھی وجود دینے کی قدرت نہیں رکھتا ہے انسان اپنی تمام زندگی میں خدا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔
لہذا تمام عمر ہر امر میں اس ذات کا محتاج ہے مادیات میں بھی محتاج ہے اور معنویات میں بھی خدا کی مدد اور توفیق کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اور عبادت بھی انسان کی ایک ضرورت ہے
چونکہ دین انسان کی فلاح و سعادت کے لئے ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہی یہ مقصد حاصل ہو گا
لہذا عبادت کو انسان اپنی ہی بہتری کے لئے انجام دیتا ہے اور خدا کی ذات کو عبد کی عبادت کا کوئی فائدہ اور ضرورت نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرمایاہے۔
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ )
اے لوگوتم سب خدا کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے اور قابل حمد و ثنا ء ہے۔
اب اس مقام پر انسان محتاج اپنی ذات اور تشخص کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں جمع کی ضمیر اس لیے استعمال کی ہے کہ مفرد ضمیر یعنی ”میں“ کہنے میں انائیت کا شائبہ ہوتا ہے اور مقام بندگی میں جب ”ہم“ کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے میں ناچیز اور محتاج ہوں اور اس قابل ہی نہیں کہ اپنی ذات کا اظہار کرسکوں اور مقام عبادت اور طلب میں ناداری اور نیاز مندی کا اظہار ضروری ہے۔
اللہ تعالی بے نیاز مطلق ہے اور کائنات کی کوئی چیز اس کی ضرورت نہیں بن سکتی ہے اور ضرورت اور احتیاج کمال کے منافی ہو تی ہے اور عبادت جن وانس کی خدا کو ذرہ بھر ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ اگر کائنات میں ایک فرد بھی خدا کو مانتا ہے اور اس کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر بھی خداکی خدائی میں فرق نہیں پڑتا اور اس کے کمال میں کوئی کمی پیدانہیں ہو سکتی۔
جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے۔
انسان عبادت بھی خدا کی مددکے بغیر انجام نہیں دے سکتا بندگی اور اطاعت کے تمام مراحل میں اس کا محتاج ہے۔
اسی لئے عبادت اور بندگی میں توفیق الہی اور استعانت طلب کی جاتی ہے عبادت کے شروع کرنے میں بھی خدا وند متعال کی استعانت ضروری ہے چونکہ شیطان انسان کو بندگی اور اطاعت کرنے سے روکتا ہے اور مختلف حیلوں سے موانع ایجاد کرتا ہے۔
اس وقت انسان مصمم ارادہ کے ساتھ خدا کی مدد طلب کرتا ہے اور جب الہی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے تو وہ عبادت کا آغاز کرتا ہے اس وقت شیطان ناکام ہونے کے بعد عبادت میں خلل ڈالنے اور بٹھکانے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کے لیئے عبادت کو بجا لانے اور اس میں اخلاص اور حضور قلب رکھنے میں خدا کی طرف محتاج ہے اوراس کی مدد کی ضرورت ہے لہذا عبادت کے آغاز،اس کے مال اور اس کی تکمیل فقط خدا کے لطف و کرم سے ہو سکتی ہے۔
نتیجہ یہ کہ انسان ہر سانس میں اس غنی مطلق کا محتاج ہے اور دنیاوآخرت کے تمام امورخداوندمتعال کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتے۔اور خداوندمتعال کسی بھی امر میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔
فاطرآیت ۱۵ نیز سورہ محمد کی آخری آیت میں بھی یہ مفہوم موجود ہے
(ج) عبادت اختیاری
یہ آیت اس بات کی طرف متوجہ کررہی ہے کہ عبادت بندہ کا اختیاری فعل ہے اور خداوند متعال نے انسانوں کو اختیارعطافرمایاہے کہ اگر بندگی اور فرمانبرداری سے خدا وند متعال کی اطاعت اور عبادت میں زندگی گزارے تو اس کی آخرت سنور جائے گی اور اگر وہ نافرمانی کرتے ہوے کفر کی زندگی اختیار کرے تو عذاب شدید کا مستحق ہو گا۔
لہذا مسلمان اپنی عبادت اختیار سے انجام دیتا ہے لیکن اس عبادت کے کمال اور تکمیل پر اس کا اختیار نہیں ہے کیونکہ ثواب اور اجر اخروی،صحیح اور کامل عبادت پر ہی عطا ہوتا ہے اسی لیئے استعانت طلب کی جاتی ہے۔
اس آیت کریمہ میں عبادت کو عبد کا فعل کہا ہے اور استعانت اور مدد کرنا خدا کا فعل ہے لہذا خدا کے فعل پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ہاں اگر انسان اطاعت اور بندگی میں ایسے عالی اور بلند مرتبہ پر فائز ہو جائے کہ قرب الہی کے عظیم درجہ کا حامل ہو جائے تو پھر وہ خود خدا کی مرضی بن جاتا ہے یہ مقام نہایت ہی خاص ہستیوں کا نصیب ہے۔
اگر انسان خدا کی اطاعت اور بندگی کو اختیار نہیں کرتاتو وہ اپنہ ہوی اور ہوس کا بندہ ہے اور ہوس اور ہوی نفس کی غلامی اختیار کرتا ہے وہ غیر خدا کی پرستش کرتا ہے اور جیسا کہ فرمان رب العزت ہے۔
( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ )
کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی ہوا وہوس کو اپنا خدا بناتا ہے۔ اور اگر انسان خدا کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کرے اور ” نعبد“ میں مخلص اور سچا ہو تو اس تکبر اور غرور کی نفی کرتا ہے۔ عبادت انسان کو اچھائی کی راہ دکھلاتی ہے اور تمام برائیوں سے دور کر دیتی ہے چونکہ جب انسان بندگی کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر سر اٹھانے اور نافرمانی کرنے کی نفی کرتا ہے اور راہ نجات پر گامزن ہوتے ہوئے سعادت اخروی کو پا لیتا ہے۔
اصل خدا ہے
ذات خداوند چونکہ اصل ہے اس لیئے ایاک کو مقدم کیا ہے اور نعبد و نستعین کو بعد میں ذکر کیا ہے چونکہ عبادت و استعانت ذات خدا پر فرع ہے اور اللہ ہر چیز سے پہلے اور مقدم ہے جیسا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔
ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله
میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ مگر یہ کہ خدا کو اس سے پہلے پایا۔
یعنی خدامتعال کی ذات ہر چیز پر مقدم ہے، لہذا عبادت پر بھی مقدم ہے اسی طرح استعانت پر بھی مقدم ہے نیز ایاک کو مقدم کرنے میں حصر عبادت اور حصر استعانت کا مفہوم بھی بیان ہو رہا ہے صڑف تیری ذات کی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ذات سے مدد مانگتے ہیں۔
عبادت کیوں مقدم ہے
عبادت کو استعانت پر اس لیئے مقدم کیا ہے کہ عبادت مطلوب خداوندی ہے اور استعانت عبد کی طلب ہے اور عبد کی طلب کا ذریعہ بھی عبادت ہے اور عبادت اور اطاعت واجب ہے اور اس کی تکمیل گرچہ استعانت ہی سے ہو گی لیکن اسے انجام دینا عبد کا اختیاری فعل ہے۔ لہذا عبد کہتا ہے کہ ” ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تم سے مدد چاہتے ہیں “ تاکہ ہماری عبادت تکمیل پائے اور عبادت کے ذریعہ تم سے مدد چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اس طرح سے تیرے قرب کے طلب گار ہیں اور تعلق اور تقرب عبادت ہی سے متحقق ہو سکتا ہے۔ نیز کلام کی ھماھنگی اور خوبصورتی بھی اسی میں ہے کہ ایاک نستعین بعد میں آئے تاکہ آیات کے اختتام میں یکسانیت پیدا ہو۔
لطف حضور
ادب کا تقاضا ہے کہاس بلند وبالا ذات سے تدریجا قرب پیدا کیاجائے اس سورہ میں نام سے آغاز کیا پھر ذات کا ذکر کیا اس کے بعد مختلف اوصاف کا تذکرہ کیا اور معرف خداوندی کے مراحل طے کیے اسطرح درجہ بدرجہ تعلق پیدا کیا جا رہا ہے اللہ، رب،رحمن،الرحیم اور مالک کہنے کے بعد اب عبد اپنا انداز گفتگو تبدیل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور اور اسکی بارگاہ میں محوس کر رہا ہے۔ اسی لیئے پہلے غیبت کے الفاظ استعمال کرتا رہا ہے اور اب مخاطب اور حاضر کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر جب بارگاہ میں گفتگو کا شرف پالیا تو اب عبد مزید قرب حاصل کرنے کے لیئے اپنی گزارشات کو پیش کرتے ہوئے استعانت کا طلب گار ہوتا ہے اور بعد والی آیات میں اپنی بنیادی دعا کو طلب کرتا ہے چونکہ حضور میں پہنچ کر درخواست جلدی قبول ہوتی ہے۔
نماز میں جب انسان اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے تو انسان روحانی پروازاور معراج کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتا ہے تو اس وقت اس کے لئے یہ نقطہ عروج ہے۔
اور یہاں تعلق اور قرب الہی کا مقام ہے لہذا اس کے بعد دعا کرتا ہے،یعنی پرواز روحانی حمد،تعلق وقرب،اور درخواست کے مراحل پر مشتمل ہے۔
( ۲) وحدت کلمہ
اس آیت مبارکہ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو وحدت اور یگانگی سے اپنے امور بجا لانا چاہیں اور اتحاد کے ساتھ خدا کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزاریں،اپنی عبادات میں بھی وحدت کو ملحوظ رکھیں جیسے اجتماعی عبادات مانند حج،نماز جماعت،نماز جمعہ جہاد وغیرہ میں ضروری ہے۔
سورہ حمد چونکہ نماز کا لازمی جز ہے اور جب بندہ نماز میں یہ جملہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو جماعت اور اجتماع میں شمار کرتے ہوئے نعبد و نستعین کہتا ہے ہر قسم کی انفرادیت، علیحدگی،گوشہ نشینی اور ہر قسم کی دوسری چیزیں قرآن اور روح اسلام کے منافی ہیں اور عبادت تو خاص طور پر اجتماعی پہلو رکھتی ہے اور مخصوصا نماز کی بہترین حالت جماعت کی صورت میں ہے۔
اذان اور اقامت سے لے کر اختتام نماز یعنی السلام علیکم و رحمة و بر کاتہ تک جماعت اور اجتماع کی ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے گرچہ انفرادی نماز بھی صحیح ہے لیکن یہ دوسرے درجے کی عبادت ہے اور اجتماعی عبادت اور دعا جلد قبول ہوتی ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔
استعانت
الف ضرورت استعانت
انسان دنیا میں بہت سی قوتوں سے نبرد آزما ہے کچھ بیرونی قوتیں ہیں اور کچھ انسان کی اندرونی قوتیں ہیں جو اسے تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں اور بندگی اور اطاعت میں بھی بہت سی قوتیں انسان کو انحراف،خود پسندی،ریاکاری،سستی اور ایسے دیگر امور میں مبتلا کرسکتی ہیں جیسا کہ شیطان نے بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کی کی قسم اٹھا رکھی ہے۔
نفس امارہ بھی برائیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے تو اس مقام پر عبد کو ایک طاقتور اور قادر مدد گار کی ضرورت کا ہوتا ہے تو وہ خدا سے مدد مانگتا ہے اور خود کو پروردگار کے سایہ حمایت کے سپرد کرتا ہے اور جو انسان نماز میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہو۔
اس کا ایمان بندگی کا اعتراف اور اسی سے مدد مانگتا ہو تو وہ پھر کسی طاقت سے نہیں گھبراتا، ثابت قدمی کے ساتھ اطاعت اور بندگی کے راستے پر گامزن رہتا ہے اور کسی دوسری قوت کے سامنے سر نہیں جھکاتا اور مادیات کی کشش سے دھوکا نہیں کھاتا ہے اور اپنی حیات و ممات کو خدا کے لئے قرار دیتا ہے۔
انحصار استعانت
خدا وند متعال چونکہ قادر مطلق ہے اور کائنات کی ہر طاقت اور قوت پر حاوی ہے لہذا صرف وہی ذات ہے جو ہر معاملہ میں مددگار ہو سکتی ہے لہذ ا صرف اسی ذات سے مانگنی چاہیے اور اس ذات کے علاوہ کسی دیگر قوت کی مدد ناقص ہوگی مگر یہ کہ خداوند متعال خود کسی کو خصوصی طور مدد گار کامل بنادے۔
اب اگر انسان اس سے مدد لے تو یہ بھی خدا کی عطا کردہ قوت کی مدد ہو گی خدا کی ذات” کن فیکون“ بلکہ اس سے بالا تر طاقت لہذا جب وہ کسی چیز کا اردہ فرمائے تو دنیا وی کسی طاقت کو ہر مارنے کی مجال نہ ہوگی اور ہر طاقت کی قوت دم توڑ دے گی اسی لئے انسان اپنے تمام امور میں اسی ذات سے مدد مانگتا ہے تکمیل ایمان وعبادت میں بھی اس کی مدد کا محتا ج ہے۔
اگر کوئی انسان غفلت میں زندگی گذار رہا ہو اور خدا کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گرچہ یہ بہت بڑی بد بختی ہے لیکن یہ انسان جب کسی بڑی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہو تا ہے اور دنیا کی ہر طاقت سے ما یوس ہو جا تا ہے تو پھر فقط اور فقط ایک ہی طاقت ہے کہ جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور وہ خدا وند متعال کی ذات ہے۔
خصوصیات آیت پنجم
اولین تکرار لفظ
اس آیت میں ایک لفظ ”ایال“ دو مرتبہ آیا ہے اس طرح یہ قرآن مجید کا ایک ہی آیت میں ہونے والا پہلا تکرار ہے یہ معنوی مفاہیم کے علاوہ لفظی خوبصورتی کا باعث ہے اس مقام پر یہ تکرار کلام میں لطافت بھی پیدا کرتا ہے اور محبوب سے گفتگو چونکہ شیرین ہو تی ہے تو الفاظ کے تکرار سے طویل کیا جاتا ہے۔
پہلا بلا واسطہ فعل
اس آیت مبارکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آسمانی کتاب میں عبد پہلی دفعہ اپنے مالک کو بلا واسطہ پکارا ہے اور اس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے گرچہ انسان گذشتہ آیات میں مختلف مرا حل میں یہ اعزاز حاصل کر رہا ہے کہ اپنے مالک اور خالق سے صرف ”تم“ کہہ کر گفتگو کا آغاز کرے جس میں اپنا ئیت پائی جا تی ہے۔
پہلی ضمیر
قرآن مجید میں استعمال ہو نے والی پہلی ضمیر ”ایاک “ ہے یہ اس آیت مبارکہ کی خصوصیت ہے کہ سب سے پہلی ضمیر اس آیت میںآ ئی ہے اور وہ بھی خدا کے لئے استعمال ہوئی ہے اور ضمیر بھی ضمیر مخاطب ہے اور یہ ضمیر ایک آیت میں دو مرتبہ آئی ہے۔
ضمیر کا استعمال عظمت مقام معبود کی وجہ سے ہے اور اس میں یہ مفہوم ہے معرفت اور شناخت کے مراحل طے ہو چکے ہیں لہذا اب اس ذات برتر کے لیئے ضمیر استعمال ہو رہی ہے اور ضمیر خطاب اس لیئے ہے کہ تعلق کا اظہار کیا جائے ہم تیرے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
( ۴) پہلا مطلوب الہی
مطلوب الہی اور عبد کا پہلا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ مقصد تخلیق بھی عبادت ہے اور خدا بھی چاہتا ہے کہ انسان عبادت کریاور اطاعت کی زندگی گزارے لہذا قرآن مجید میں پہلا مقام ہے کہ جہاں الہی طلب جو کہ عبادت ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم تیرے حکم کے مطابق صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
پس مرضی الہی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔اور پھر عبد اپنی طلب کا اظہار بھی کرتا ہے کہ بار الہی ہم تمام معاملات میں تم سے ہی مدد طلب کرتے ہیں لہذا یہ عبد کی پہلی طلب اور دعا قرار پائی کہ جو قران مجید کی اس آیت کا خاصہ ہے۔
( ۵) پہلا اظہار وجود
اس آیت مبارک میں عبد” نعبد “اور ” نستعین“ کے الفاظ سے اظار وجود کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے اور کہ رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور بندہ اپنے مالک سے اپنی ہی بھلائی کے دو کاموں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے کام اور ذمہ داری پوری کرتے ہیں اسی لیئے فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور (یہ قرآن مجید میں آنے والا پہلا فعل بھی ہے)۔
البتہ یہاں جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس میں اس امر کا اظہار ہے کہ ہماری عبادت مجموعی طور پر ( یعنی اولیاء انبیاء اور آئمہ کی عبادت سے ملکر )ہی عبادت کہلا سکتی ہے وگرنہ ایک بندہ عبادت خدا انجام دینے کو اپنی طرف نسبت دینے میں کاذب بھی ہو سکتا ہے۔
فضائل
( ۱) نماز حضرت امام زمانہ میں تکرار
اس آیت مبارکہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ہمارے موجودہ زمانہ کے امام آخرالزمان علیہ السلام کی مخصوصہ نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت ۱۰۰ مرتبہ تکرار ہوتی ہے۔
( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ )
ہمیں سیدھے راستے کی ھدایت فرما تا رہ
ھدایت، پروردگار عالم کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار،اسکی وحدانیت کی گواہی،اسے اس کائنات اور عالم آخر ت کامربی اور مالک ماننے اور اس سے طلب و استعانت کے مرحلہ تک پہنچ جانے کے بعد ہم بارگاہ خداوندی میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں دنیاکے اس بیابان میں راہ مستقیم پر گامزن رکھ اور یہی راستہ جنت کے لیئے ہمارا ہادی ہو،اس ہدایت کی دوصو رتیں ہیں۔
( ۱) ھدایت تکوینی
خالق کائنات نے اس ہدایت کے ذریعے تمام حیوانات، جمادات،نباتات کو رشد،نمو اور ترقی فرماتی ہے جس طرح پرندوں،چرندوں کا گرمی اور سردی کے مطابق انتظام کرنا، شھد کی مکھیوں کا پھولوں سے رس نکال کر شھد فراہم کرناہدایت تکوینی ہے جیسا کہ خداوندعالم نے ارشاد فرمایا۔
( رَبُّنَا الَّذِیْٓ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَه ثُمَّ هََدٰی )
(حضرت موسی نے فرمایا )ہمارا پروردگاروہ ہے جس نے ہر موجود کو لباس ہستی بخشا ہے اور پھر اس کی ھدایت اور رہبری کی ہے۔
( ۲) ہدایت تشریعی
اس کے ذریعہ سے خداوندعالم نے تمام افراد بشر کی ہدایت کی ہے انبیاء اور آسمانی کتب
کے بھیجنے کیساتھ خدا نے تمام انسانوں پر اتمام حجت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حق و باطل کی پہچان کے لیئے عقل جیسی قوت عطا فرمائی ہے اور انبیاء علیہم السلام نے احکام اور قوانین الہی کو ان کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس ہدایت تشریعی کی وجہ سے بعض لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے اور بعض لوگوں نے ضلالت وگمراہی کاراستہ اختیار کیا جیسا خداوندعالم نے فرمایا
( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا )
یقینا ہم نے انسان کو راہ(سعادت)کی ہدایت کی خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو۔
ہدایت سے کیا مرادہے؟جن لوگوں نے اس وجہ سے ہدایت حاصل کی ہے اب وہ بارگاہ خداوندی میں خصوصی ہدایت کی درخوا ست کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدہی راہ کی ہدایت فرما اور یہی اھدناالصراط المستقیم میں بھی مراد ہے۔ یہ عنایت ربانی ہے خداوندعالم اپنی حکمت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے خاص بندوں کے لیئے یہ ہدایت فرما رہا ہے۔بہرحال یہاں عمومی ہدایت مراد نہیں ہے یعنی جو خداوندعالمنے پوری کائنات کو عطا کی ہے۔ لہذا یہاں ہدایت سے مراد وہی اعانت ہے جس کی خواہش کا اظہار ایک نستعین میں کیا تھا یہ وہ توفیق خداوندی جو بندہ کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ اسی کی بدولت وہ خیر و فلاح کے قریب آجاتا ہے۔
دعا
مقام الہی کی معرفت رکھنے والے انسان کے لئے اہم ترین دعا ہے،صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی دعا ہے یعنی ہمیں دنیاوی امور جیسے عبادت،عتقاد، اخلاق، سیاست،معا ملات،لین دین اور دوسرے تمام امور جیسے قبر و برزخ،میدان حشر، پل صراط اور صر اط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے دعا حساب کتاب کے مشکل حالات سے نجات عطا فرمائے۔
یعنی انسان کی تمام دنیاوی اور اخروی میدانوں میں کامیابی اور سعادت کا ذریعہ ہے البتہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے میں ہم ہر آن اور لحظہ،خدا کے فضل و کرم اور توفیق کے محتاج ہیں جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ )
اے لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو
( ۳) صراط مستقیم
صراط مستقیم کی وضاحت قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہے بعض مقامات پر راہ اعتدال،اتحاد اور استقامت مراد ہے کیونکہ انسان کو ہر لمحہ لغزش اور کجروی کا خوف رہتا ہے۔اللہ تبارک وتعالی فرماتا ہے۔
( وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ )
یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں کی طرف نہ جاؤ کہ راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے۔
اسلام کا تربیتی راستہ معتدل اور درمیانی راہ ہے اس میں کوئی افراط وتفریط نہیں پائی جاتی ہے۔قرآن مجید نے صراط مستقیم سے آئندہ کا آئین،دین حق اور احکام خدا وندی کی پا بندی بھی مراد لی ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔
( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )
کہہ دیجیے کہ میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے جو کہ سیدھا دین ہے اور اس ابراہیم کا آئین ہے جس نے کبھی خدا نے شرک نہیں کیا۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا نام بھی صراط مستقیم رکھا ہے جیسا کہ فرمان خدا وندی ہے۔
( وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ )
اور میری ہی عبادت کرو کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔
صراط مستقیم تک پہنچنے کا راستہ اللہ سے تعلق و ربط کے ساتھ ممکن ہے اس سلسلے میں خدا وند والم رشاد فرماتا ہے۔
( وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّـهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ )
جنہوں نے اللہ تعالی کے دامن کو تھامے ر کھا انہو ں نے ہی صراط مستقیم کی ھدایت پائی۔
خدا پر اعتقاد رکھنے والے انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا ور اؤ لیا ء خدا کی راہ کا انتخاب کرے کیونکہ فقط یہی راہ ثابت ہے اور دوسری تمام راہیں تغیر وتبدل کا شکار رہنے کے ساتھ متعدد بھی ہیں لہذا انسان فقط خدا سے ہی سیدھی راہ ثابت قدم رہنے کا تقاضا کرے۔
اگر ہم ظلم اور راہ روی جیسے گناہوں ار تکاب کریں تو منبع ہدایت سے ہمارا رابطہ منقطع ہو جا ئے گا لہذا ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسے موانع پیش نہ آئیں تا کہ ہم انحراف اور تباہی سے بچے رہیں جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
یعنی ارشد نا للزوم الطریق المئودی الی محبتک والمبلغ الی جنتک والما نع من ان یتبع اهئوا نا فنعطب اوان نا خذبا را ئینا فنهلک
خدایا ہمیں ایسے راستے کی ہدایت فرما جو تیری محبت اور جنت تک لے جاتا ہے اور جو راستہ خواہشات کی اتباع اور اپنی آرا ئپر عمل کرنے سے ہلاکت میں پڑنے سے روکتا ہے اس آیت سے واضح طور ہر معلوم ہوتا ہے دین حق کی حقیقی معرفت ان اشخاص کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔
جنہوں نے اس دین کے اصولوں پر صحیح معنی میں عمل کیا ہے اور اس دنے کے لئے ایک بہترین نمونہ ہیں۔
لہذا صراط مستقیم پر پہنچنے کیلئے ان ہستیوں کی شناخت کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس کا اتم اور اکمل نمونہ صرف اورصرف اہلیبیت و طہارت وعصمت علیہم السلام ہی ہیں۔
جیسا کہ روایت میں بھی موجود ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
لیس بین الله و بین حجته حجاب ولا لله دون حجته ستر: نحن ابواب الله و نحن صراط المستقیم و نحن ملبسته علمه و نحن تراجمة وحیه و نحن ارکان توحیده و نحن مو صع سره
خدا اور اس کی حجت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے خدا کی شناخت کے لئے حجت کی شناخت ضروری ہے ہم ہی باب اللہ ہیں،ہم ہی صراط مستقیم ہیں،اور خدا کے علم کا خزانہ بھی ہیں ہم ہی خدا کی وحی کے ترجمان ہیں اس کی تو حید کے ستون ہم ہیں،اور اس کے اسرار کا خزانہ بھی ہم ہیں۔
اسی مطلب پر اور بھی بہت سی روایا ت ہیں جو بتاتی ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد محبت اہلبیت ہے اس مطلب پر ابن شھر آشوب نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ اھد نا الصراط المستقیم سے مراد اہلبیت اور محبت اہلبیت علیہم السلام ہے۔
اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
هی الطریق الی معر فته و هما صراطان صراط الدنیا، صراط الاخرة،فا ما الصراط فی الدنیا دهو الامام المعتر ض الطا عة من عرفه فی الدنیا واقتدی بهداه مر علی الصراط الذین هو حسر جهنم فی الا خراة ومن لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه فیالاخراة فتردی فی نار جهنم
صراط مستقیم خدا کی معرفت کا راستہ ہے اس مراد دو راستے ہیں صراط دنیا صراط آخرت، صراط دنیا سے مراد وہ امام ہیں جن کی اطاعت مخلوق پر واجب ہے۔ لہذا جس نے اس دنیا میں اس امام کی معرفت حاصل کی اور اس کی پیروی کی،قیامت والے دن وہ پل صراط کو با آسانی عبور کرے گا اور جس نے اس دنیا میں امام بر حق کی معرفت حاصل نہ کی قیامت والی دن اس کے قدم ڈگمگا جا ئیں گے اور جہنم کی آگ ہی اس کا ٹھکا نا ہو گی۔
پل صراط کے بارے میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اعظم( ص) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔
لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز
بہر الحال بعض مفسریں نے صراط مستقیم سے اسلام،بعض نے قرآن بعض نے انبیاء بعض نے حضرت رسول اعظم (ص) بعض نے معرفت امام بعض نے حضرت امیر المومنین اور بعض آئمہ بر حق مراد لئے ہیں۔
مرحوم طبرسی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو عموم پر حمل کرنا بہتر ہے تا کہ تمام موارد کو شامل ہو جائے یعنی صراط مستقیم وہ دین ہے جس کا خدا وند ولم نے ہمیں حکم دیا ہے اور توحید،عدل اور (نبوت امامت) اور ولایت کی اطاعت کو ہم پر واجب اور ضروری قرار دیاہے۔
( صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَالضَّالِّینَ )
جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تم نے نعمتیں نازل کیں ہیں،ان کا راستہ نہیں جن پر تم نے غضب نازل ہوا ہے جو گمراہ ہوئے ہیں۔
الہی نعمتیں
یہ آیت مبارکہ اس راہ حق اور سیدھے راستے کی وضاحت ہے جس کی پہلی آیت میں دعا مانگی گئی تھی بہر حا ل یہاں نعمت سے مرا د مادی اور دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں کیو نکہ دنیاوی نعمتیں خدا کا عمومی انعام ہیں ان کے لئے بقاء نہیں ہے لہذا یہاں وہ ابدی اور دائمی نعمت مراد ہے جس کے حصول کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور وہ نعمت ہدایت اور تو فیق ہدایت ہے۔
یہی انسان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتی ہے اور یہ نعمت صرف اور صرف ایمان،آئمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت کا اقرار،اور اطاعت اور پیروی میں مضمر ہے اور آخری دم تک اس ہدایت پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے اور جو لوگ نعمتوں کے حصول کے بعد ان پر ثابت قدم نہیں رہے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا جیسا کی اللہ رب العزت کا فرمان ہے
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ )
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت کے ساتھ تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا۔
لہذا جنہں نے جان بوجھ کر حق سے انحراف کیا ہے ان پر تو اللہ کا غذب ہو ہے اور جنہوں نے حق کو طلب کرنے میں کوتا ہی کی ہے وہی بھٹکے ہوئے ہیں اور جو اس ہدایت پر ثابت قدم ہیں وہ انعام یافتگان الہی ہیں اور انہی کے لئے سعادت ہے۔
حضرت فاطمةالزاھرا سلام اللہ علیہا نے بھی فدک کے مسئلہ پر اپنے تاریخی خطبہ مسجد نبوی میں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی کے اس فرمان کو تلاوت فرمایا۔
( وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )
مسلمان رہتے ہوئے اس دنیا سے مرنا۔
لہذا اس ہدایت پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے فقط اسلام کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ مرنے تک ثابت قدم رہنے سے ہی سعادت اور خوش بختی نصیب ہو سکتی ہے۔
تر بیت الہی
انسان اپنے آغاز لے کر انجام تک تربیت کا محتاج ہے یہی وجہ ہے کہ خدا وند عالم نے اس کی تربیت کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہیں۔
ان کے بعد ائمہ اطہار علیہم ا لسلام تا قیام قیامت انسانیت کے مربی ہیں اور انسان بھی یہی درخواست پیش کر رہاہے کہ مجھے ان انعام یافتہ لوگوں کی راہ کا مسافر بنا خدا وند عالم نے انعام یافتہ لوگوں کا قرآن مجید میں اس طرح تذکرااہ فرمایا ہے۔
( وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ )
جو لوگ خدا اور رسول کے احکا م کی اطاعت کرتے ہیں خدا نے انہیں ان لوگوں کے ساتھ قرار دے دیا ہے جنہیں نعمات سے نوازا گیا ہے اور وہ انبیاء،صدیقین،شھداء اور صالحین لوگ ہیں۔
اسی طرح معانی اخبار میں حضرت رسول اعظم (ص) سے روایت موجود ہے۔
انعمت علیهم شیعته علی یعنی انعمت علیهم بولایت علی ابن ابی طالب لم تغضب علیهم ولم یضلوا
انعام یافتگان الہی علی کے شیعہ ہیں کیونکہ انہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انعام دیاگیا ہے ان پر نہ تو غضب الہی ہو گا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں
مغضوبین کی راہ سے دوری
قرآن مجید میں مغضوبین کے عنوان سے مختلف افراداور امتوں کا تذکرہ موجود ہے جن پر خدا کا غضب ہو اہے ا ور ہم ہر روز نماز میں خدا وندعالم سییہی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان مغضوبین کے عقائد،اخلاق اور عمل سے دور رکھ یعنی ان کی راہ سے دوری اور ان سے نفرت کا اظہار ضروری ہے کیونکہ ان پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور انہیں جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہو گی اور جہنم کا ٹھکا نا ہو گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔
( الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ )
منافق اورمشرک مرد اور عورتیں جو خدا کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں ان سب پر عذاب نازل کرے،ان پر عذاب کی گردش ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے جہنم کو کو مہیا کیا ہے۔
بہر حال کفر کی راہ اختیار کرنے والے،حق سے دشمنی والے ہیں انبیاء مرسلین اور آئمہ اطہار کو اذیت دینے والے ہی مغضوبین ہیں جیسا کہ حضرت امام جعفر صاق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
ان المغضوب علیهم الضاب
بیشک مغضوب علیہم سے مراد اہلبیت سے عداوت کا اظہار کرنے والے (ناصبی) ہیں
لہذا مغضوبین کی راہ سے دوری اور ان سے نفرت کرنے والے ہی انعام یافتگان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔
گمراہوں کی راہ سے دوری
ہمیں گمراہوں کی راہ سے دوری اور نفرت کا اظہار کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بھی مغضوبین کی طرح ہی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ خود گمراہ ہیں جبکہ مغضوبین خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ خدا نے پہلے مغضوبین کی راہ سے دوری کا حکم صادر فرمایا ہے اور پھر بلا فاصلہ گمراہوں کی راہ سے اجتناب کا کہا ہے قرآن مجید میں دونوں گروہوں کے متعلق مختلف آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے مغضوبین کا مرحلہ،گمراہوں کی نسبت سخت اور بد تر ہے بعض مفسرین نے ضالین سے منحرف عیسائی مراد لئے ہیں اور مغضوبین سے یہودی مراد لئے ہیں اور بعض مفسرین نے اس کے عکس کو بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے مغضوبین اور ضالین دو عنوان ہیں چونکہ یہودی اور عیسائی ہر وقت اسلام سے دشمنی رکھتے تھے
لہذا یہ دونوں گروہ مغضوبین اور ضالین ہیں کیو نکہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسرں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جیسا کہ حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں۔
کل من کفر بالله فهو مغضوب علیه وضال عن سبیل الله
جو بھی حق خدا کو چھپاتا ہے وہ مغضوب علیہ اور سبیل خدا سے گمراہ ہے۔
حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں
الضالین اهل الشکوک الذین لا یعرفون الامام
ضالین سے مراد وہ اہل شکوک ہیں جو امام کو نہیں پہچانتے۔
لہذا ان دونوں گروہوں سے نفرت ان کی راہ سے دوری اور انعام یافتگان کی راہ پر ثابت قدم رہنا صراط مستقیم ہے۔
سورہ بقرہ
اسماء وجہ تسمیہ
( ۱) بقرہ
، اس سورہ مبارکہ کے چند نام بیان ہوئے ہیں ان میں مشہور ترین نام سورہ بقرہ ہے،بقرہ کا معنی گائے ہے چونکہ اس سورہ میں گائے کو ذبح کرنے کا قصہ بیان ہو اہے۔، یہ قصہ کسی اور سورہ میں بیان نہیں ہوا ہے اس لیئے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔
( ۲) سنام القرآن
اس سورہ کا نام سنام القرآن بھی ہے اور اسے سنام القرآن اس لیئے کہتے ہیں کہ سنام سے مراد بلندی ہے اور یہ سورہ بھی رفیع اور بلند ہے جیسا کہ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اعظم (ص)نے فرمایا۔
ان لکل شیء سناما،وسنام القرآن البقره
ہر چیز کے لیئے رفعت اور بلندی ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے
( ۳) فسطاط القرآن :
اس سورہ کا ایک نام فسطاط القرآن بھی ہے۔فسطاط کا معنی خیمہ ہے اور خیمہ کسی چیز کا جامع ہوا کرتا ہے اور اسے فسطاط القرآن اس لیئے کہتے ہیں کیونکہ یہ عظیم سورہ ایسے احکام کا جامع ہے جو احکام دوسری سورتوں میں مذکور نہیں ہیں جیسا کہ حضرت رسول اعظم (ص) نے ارشاد فرمایا
السورةاللتی یذکر فیها البقره،فسطاط القرآن
جس سورہ میں گائے کا تذکرہ موجود ہے وہ فسطاط القرآن ہے۔
( ۴) سید القرآن
حضرت رسول اعظم (ص) کے فرمان کے مطابق سورہ بقرہ سید القرآن ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے۔
قرآن سید الکلام ہے اور سید قران سورہ بقرہ ہے۔
( ۵) سورہ۔ا۔ل۔م:
اس سورہ کا ایک نام سورہ ا۔ل۔ م بھی ہے اور اس نام کی وجہ اس سورہ کے آغاز میں موجود حروف مقطعات ( ا۔ل۔م ) ہیں۔جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ بھی ہے۔
انها اسماء السوره و مفاتحها
یہ سورتوں کے نام اور آغاز پر دلالت کرتے ہیں۔
مقام نزول وتعداد آیات
اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے البتہ اس سورہ کی ایک آیت حجت الوداع کے موقع پر منی میں نازل ہوئی ہے اور وہ آیت واتقو یو ما تر جعون فیہ الی اللہ ہے۔اس سورہ مبارکہ کی کل ۲۸۶ آیات ہیں،یہی تعداد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے
شان نزول اس سورہ مبارکہ کا ایک شان نزول نہیں ہے کیونکہ اس سورہ کی مختلف آیات اہم مواقع پر نازل ہوتی رہی ہیں اسی مناسبت سے مختلف آیات کا مختلف شان نزول ہے اس کے متعلق آیات کے ضمن میں ہی تفصیلی بحث کریں گے جب بھی کوئی اہم واقع بیان ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اس کا شان نزول بھی بیان کر دیا جائے گا
خصوصیات سورہ بقرہ
( ۱) سب سے بڑا سورہ ہے۔
اس سورہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے جو تقریبا اڑھائی سپاروں پر مشتمل ہے۔
( ۲) مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی سورہ۔
یہ مدینہ میں نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے جیسا کہ سیوطی عکرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ۔
اول سورة نز لت بالمدینه،سورة البقره
مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہونے سورہ سورہ بقرہ ہے۔
( ۳) سب سے زیادہ احکام پر مشتمل۔
قرآن مجید کا یہ سورہ جتنے احکام پر مشتمل ہے اتنے احکام کسی اور سورہ میں بیان نہیں ہوئے ہیں جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہان فی البقره ضمس مئا ة حکم
سورہ بقرہ پانچ سو احکام پر مشتمل ہے۔
( ۴) سب سے زیادہ آیات
قرآن مجید کا یہ سورہ سب سے زیادہ آیات قرآنی پر مشتمل ہے جیسا کہ حضت امیر المومنین علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سورہ کی ۲۸۶ آیات ہیں۔
فضائل سورہ
( ۱) افضل ترین سورہ :
یہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے افضل سورہ ہے جیسا کہ حضرت رسول اعظم (ص)نے اپنے اصحاب سے پوچھا ای القرآن افضل :قرآن مجید کی کونسی سورہ افضل ہے۔
انہوں نے کہا
اللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں
حضرت نے فرمایا سورةالبقرة
افضل ترین سورہ،بقرہ ہے۔
( ۲) استحقاق رحمت :
اس سورہ مبارکہ کی تلاوت رحمت خدا وندی کی موجب ہے جیسا کہ ابی بن کعب کہتے ہیں حضرت
رسول اعظم (ص) نے ارشاد فرمایا۔
من قراء سورةالبقره فصلوات الله علیه و رحمته و اعطی من الاجر کا عرابط فی سبیل الله سنته لا تسکن روعته
جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کے درود و سلام اور لامتناہی رحمتوں کا مستحق ہو گا اور اسے ایک سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کاثواب عطا ہوگا اور کفار کا اس پر کوئی خوف و دبدبہ نہ ہو گا۔
اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا اے ابی مسلمانوں سے کہو کہ۔
ان یتعلموا سوره البقره فان تعلمها برکته و ترکها حسرةولا یستطیعها البطلة،قلت یا رسول الله ما البطلةقال السحره
سورہ بقرہ کو یاد کریں کیونکہ اسے سیکھنا برکت ہے اور اسے ترک کرنا ندامت ہے،جادو گر اس سورہ کو پڑھنے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔
( ۳) یاد کرنے کا انعام :
اس سورہ مبارکہ کو سیکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت رسول اعظم (ص)نے اپنے اصحاب کو کسی مقام پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور ان کے امیر کے انتخاب کے لئے ایک ایک صحابی کو بلا کر پوچھتے کہ قرآن کا کونسا سورہ یاد ہے یہ مختلف سورتوں کے نام بتاتے بالا خر ایک نو جوان آیا اور اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے تو حضرت نے فرمایا :
اخبر حوا و هذا علیکم امیرا ۔
یہی آپ کا امیر ہے اس کی سربراہی میں جاؤ ان لوگوں نے اعتراض کیا
يارسول الله هو احدثنا سنا قال معه سورة البقره
یا رسول اللہ یہ تو ہم سے کم سن ہے حضرت نے فرمایا لیکن اسے سورہ بقرہ یاد ہے۔
اس مبارک حدتث سے واضح ہو گیا کہ منصب امارت علم و حکمت کے ساتھ ہے زیادہ سن رسیدہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔
حضرت امیر المومنین علیہ السلام شریعت نبوی حکم متشابہ ناسخ منسوخ مجمل مبین اور پورے قرآن کے علوم پر حاوی مشکل کشاء اور غیب کے متعلق قرآنی آیات سے آگاہ کرنے والے اور پوری کائنات سے افضل تھے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام (ص)کے بعد آپ کی ہستی خلیفہ بلا فصل ہے۔
موضوعات
اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع تقوی ہے اور اس کے موضوعات کو مندجہ ذیل چھ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
( ۱) تقوی چاہنے والوں کی خلافت اور جنت کی طرف ہدایت :آیت ۱ ۔ ۲
( ۲) ہدایت قران کے مطابق مختلف گروہ،متقی،کافر،منافق،: آیت ۳ ۔ ۲۹
( ۳) خلافت آدم۔تقوی اور غیر تقوی کی نشانیاں۔آیت ۳۰ ۔ ۳۹
( ۴) بنو اسرائیل کی خلافت۔غیر تقوی کا نمونہ ظلم،فساد، ظلم،خون ریزی وکفر نفاق، ۴۰ ۔ ۱۲۳
( ۵) خاندان ابراھیم کی امامت،تقوی کا نمونہ،خلافت، امامت کی لیاقت،ظالموں سے عادلوں کی طرف خلافت و امامت کا انتقال،آیت ۱۲۴ ۔ ۱۵۷
( ۶) حدود تقوی الہی،احکام شرعیہ،مسائل فقہیہ آیت ۱۵۷ ۔
محور بحث،تقوی
کلمہ تقوی اس سورہ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور تقوی ہی تمام آسمانی کتب کا محور ہے جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے۔
( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ) (۱)
ہم نے تم سے پہلے اھل کتاب کو اور اب تمہیں یہ وصیت کی ہے کہ تقوی اختیار کرو۔
لہذا اگر تقوی کی نسبت کوئی اور جامع وصیت ہوتی تو یقینا خدا وند عالم اس کا ذکر کرتا دنیا وآخرت کی تمام اچھائیاں اسی لفظ تقوی میں مضمر ہیں انبیاء علیہ السلام بھی توحید کے بعد یہی وصیت کرتے ہیں۔
( أَلَا تَتَّقُونَ ) (۲)
____________________
۰۰۰ سورہ نساء آیت ۱۳۱ ۰۰۰ ۰۰۰ سورہ شعراء ۱۰۶،۱۲۴،۱۶۱، ۰۰۰۱۷۷
کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟
تقوی ہی قران مجید کا محور بھی ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( الم ﴿﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ )
یہ وہ کتاب ہے جس میں متقیوں کے کلئے ہدایت ہے
ھدی اللمتقین ہی سورہ بقرہ کا محور ہے تام موضوعات تقوی کے ساتھ ہی مربوط ہیں،جیسا کہ آپ تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں گے۔
متقین کی راھنمائی۔
یہ کتاب ( قران مجید)متقی لوگوں کی حقیقی راہنما ہے اس سورہ کا محور تقوی ہے اور تقوی کا لغوی معنی اپنی حفاظت کرنا ہے یعنی مضر چیزوں سے نفس کو بچانا اور مفید چیزوں کی طرف رغبت کرنا ہی تقوی کہلاتا ہے بالفاظ دیگر واجبات کا بجا لانا اور محرمات سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں تقوی
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔
ان لا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک
جہاں اللہ نے ھکم دیا ہے اسے بجا لانے کی کوشش کرواور جس چیز سے نہی فرمائی ہے وہاں نہ دیکھو۔
___________________
۰۰۰ سورہ بقرہ آیت ۲۰۰۰ سفینتہ البحار ج ۲ ص ۲۲۹ ومجمع البیان ج ۱ ص ۳۷ بحوالہ کاشف
مراتب تقوی
تقوی کے تین مراتب ہیں
( ۱) تقوی بدن،جسم کو نجاسات سے دور رکھنا تقوی بدنی ہے۔
( ۲) تقوی نفس،نفس کو شیطانی وسوسوں اور صفات رذیلہ و خبیثہ سے دور رکھنا تقوی نفس ہے۔
( ۳) تقوی قلب،دل کو حضرت حق تعالی کے لیئے علاوہ ہر چیز سے پاک و صاف کرنا تقوی قلب ہے جس جگہ یہ تینوں اقسام موجود ہوں وہ اللہ تعالی کی خاص عنائیت اورلطف کا مستحق ہے۔( عنوان الکلام ص ۱۲۵)
قران میں تقوی کی اہمیت۔
الف،قرآن مجید میں تقوی کو بہت اہمیت دی گئی ہے ایمان کا مرحلہ اسلام سے بلند ہے اور تقوی کا مرحلہ ایمان سے بھی بلند تر ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )
اگر تم مومن ہو تو تقوی اختیار کرو۔
اسی طرح ارشاد رب العزت ہے۔
( یَا أیُّهَا الّذِیْنَ آمَنُو اتَّقُوا اللّهَ )
صاحبان ایمان اللہ کے لیئے تقوی اختیار کریں۔
__________________
۰۰۰مائدہ ۵۔ ۵۷، ۰۰۰ ۰۰ال عمران ۳۔۱۰۲
ب، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اساس
تقوی انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں بنیادی مقام رکھتا ہے انبیا علیہم السلام خدا اور اس کی وحدانیت کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے تقوی کا فرماتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں حضرت محمد مصطفی (ص) کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔
( قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ )
(اے محمد ) ان سے کہ دیجئے کہ آپ تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔
اسی طرح باقی انبیاء نے اپنی تبلیغ میں توحید کے بعد تقوی کو بہت اہمیت دی ہے۔
تقوی و آئمہ علیہ السلام
آئمہ علیہم السلام کا کردار وہ گفتار، تقوی پر مشتمل تھا یہی وجہ ہے کہ جب ہماری نگاہ نہج البلاغہ پر پڑتی ہے تو اس کتاب مین تقوی ہی محور کلام ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام تقوی کو تمام اخلاقی مسائل کا سردار سمجھتے ہیں جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں۔
التقی رئیس الاخلاق۔
____________________
۰۰۰ مومنون ۲۳ ۸۷
ملاحظہ فرمائیں (۱)حضرت نوح،شعراء ۱۰۶،(۲) حضرت ھود،شعراء،۱۲۴(۳) حضرت صالح شعراء ۱۴۲(۴) حضرت لوط،(۵) حضرت شعیب، ۱۷۷ (۶)حضرت الیاس،صافات ۱۲۴(۷) حضرت ابراہیم،عنکبوت ۱۶(۸) حضرت موسی،اعراف ۱۲۸(۹) حضرت عیسی،ال عمران ۵ وغیرہ۔۰۰۰
تقوی اخلاق کا سردار ہے۔( ۱)
حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نظر میں وہی شخص حقیقی متقی ہے جس کے تمام اعمال ایک طشت میں رکھ کر پوری دنیا کو دکھائے جائیں،اور اس میں ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔( ۲)
حضرت امام باقر علیہ السلام اپنے سچے شیعوں کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔
فوالله ما شیعتنا الا من اتقی الله وطاعه ۔( ۳)
خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہی ہے جو تقوی اختیار کرے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہو۔
تقوی کی علامتیں
قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے والوں کی بہت سی علامتیں بیان ہوئی ہیں ان تمام کا احصی انتہائی مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ اختصار کا منافی ہے ان میں ایک علامت عزت وتکریم ہے جیسا کہ خداوندمتعال ارشاد فرماتا ہے۔
( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) ( ۴)
____________________
،۰۰۰نہج البلاغہ حکمت ۴۰۲۔ ۰۰۰ منہج الصادقین ج ۱ ص ۱۲۳۰۰۰ سفینة البحار،ج ۱،ص۷۳۳۔
۰۰۰سورہ حجرات آیت ۱۳،
بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیز گار ہو۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تقوی کی علامتیں ذکر فرمائیں ہیں۔
متقین کی صفات
قرآن مجید نے متقین کی بہت سی صفات بیان کی ہیں ہم انشاء اللہ تفسیر کے ضمن میں ان پر اچھی طرح روشنی ڈالیں گے۔
_____________________
۰۰۰۰ملاحظہ فرمائیں
(۱)تائید و نصرت الہی،بقرہ ۱۹۴،(۲) سختیوں سے نجات (۳)۲،رزق حلال میں اضافہ طلاق ۳،(۴)اصلاح عمل،احزاب ۷۰،(۵)گناہوں سے معافی،احزاب ۷۱،(۶)محبت الہی توبہ ۷،(۷)کاموں میں آسانی،لیل ۵،۷، (۸)حفاظت ال عمران ۱۲۰،(۹)قبولی اعمال مائدہ ۲۸،(۱۰)دینوی و اخروی بشارت یونس۶۴،(۱۱)جہنم سے نجات مریم ۷۲،(۱۲)اخروی بہشت ال عمران ۱۹۸،(۱۳)زمین وآسمان کی برکت اعراف ۹۶،(۱۴)فلاح ال عمران ۲۰۰، (۱۵)خدا سے ملاقات بقرہ ۲۲۳،(۱۶)اقتدار عدن اعراف ۱۲۸،(۱۷)علم و دانش بقرہ ۲۸۲،(۱۸) خدا سے دوستی جاثیہ ۱۹،
(۱)ملاحظہ فرمائیں
(۱)غیب پر ایمان بقرہ ۲،۳ (۲) ادائیگی نماز بقرہ ۳(۳) اتفاق بقرہ ۳(۴) حضرت کی نبوت پر ایمان بقرہ۴(۵)سابقہ انبیاء پر ایمان بقرہ ۴(۶) آخرت پر ایمان بقرہ ۴(۷) خط ہدایت بقرہ ۵(۸) فلاح بقرہ ۵(۹) عہد کی وفا بقرہ ۱۷۷(۱۰) مصائب میں صبر بقرہ ۱۷۷(۱۱) راست گوئی بقرہ ۱۷۷(۱۲) وقار وبرد باری فتح ۲۶(۱۳) تعلیم دعا ال عمران ۱۶(۱۴) عبادت وقنوت ال عمران ۱۷(۱۵) سہر خیزی اور گناہوں سے معافی ال عمران ۱۷(۱۶) غصہ پینے والے ال عمران ۱۳۴(۱۷) درگزر ال عمران ۱۳۴( ۱۸) جب گناہ کر بیٹھیں تو استغفار کرتے ہیں ال عمران ۱۳۵(۱۹) گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ال عمران ۱۳۵۔۰۰۰
تفسیر آیات
( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الم ) ( ۱)
سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے ا۔ل۔م
۔ ا۔ ل۔م کے متعلق مفسر ین نے تقریبا ۳۵ معانی بیان کیے ہیں ان میں چند ایک درج ذیل ہیں۔
( ۱) حروف قرآن
( ۲) معجزہ خداوندی
( ۳) قسم
( ۴) خدا اور اس کے رسول کے درمیان اسرار ورموز
( ۵) سورہ کا خلاصہ
( ۶) اسم اعظم
( ۷) ہر سورہ کا نام
( ۸) مخالفین کی خاموشی۔
قرآن مجید کی ۲۹ سورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات موجود ہیں جب کہ ۲۴ مقامات پر ان کے بعد قرآن اور معجزہ کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں ہے
( الم ﴿﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ )
( الم ﴿﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ )
( الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ )
( المص ﴿﴾ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ )
( طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ )
بہر حال انہیں حروف سے یہ با عظمت کتاب مرتب ہوئی ہے جیسا کہ حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
ان الله تبارک و تعالی انزل هذا القرآن بهذه الحروف التی تیدو ا لها جمیع العرب ثم قال قل التی اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوابمثل هذا القرآن
خداوند عالم نے قرآن مجیدانہیں حروف کے ساتھ نازل فرمایا ہے جنہیں اھل عرب بولتے ہیں پھر فرمایا ان سے کہیں کہ اگر جن و انس اس کی مثل لانے کے لیئے جمع ہو جائیں تب بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔
انہیں حروف مقطعات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
کذب قریش والیهود بالقرآن و قالواهذا سحر مبین تقوله قتال الله،الم ذلک الکتاب ای یا محمد
۰۰۰ توحید صدوق ص ۱۶۲ ، بحوالہ تفسیر نمونہ ۰۰۰
هذا الکتاب الذی انزلته الیک الحروف المقطعه التی منها،ا، ل،م،وهوا بلغتکم فاتوابمثله ان کنتم صادیقین
قریش اور یہودیوں نے یہ کہ کر قرآن مجید کی طرف غلط نسبت دی ہے کہ یہ جادو،اور خود ساختہ ہے اور اسے خدا سے منسوب کر دیا گیا ہے۔خدا نے انہیں خبردارکرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔
( الم ﴿﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ )
یعنی اے محمد جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے اور وہ انہی حروف پر مشتمل ہے جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل پیش کرو۔
یہ حروف بتاتے ہیں کہ قرآن مجید ایک با عظمت کتاب ہے اور ان حروف نے عرب و عجم کے تمام سخنرانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے حالانکہ یہ انہیں حروف کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے اختیار میں ہیں۔ اس کے باوجود علماء ومحقق اسے سمجھنے سے عاجز ہیں کیونکہ خدائی ترکیب نے اسے درجہ اعجاز تک پہنچا دیا ہے جس طرح اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے جان مٹی سے خلق کیا جب اس میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام وجود میں آئے اسی طرح قرآن مجید انہی الفاظ سے مرتب ہو اجب اسے خدائی ترکیب نصیب ہوئی تو ایسا معجزہ بنا کہ کوئی اس کا مثل نہیں لا سکتا
لہذا یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جسے حضرت نبی اکرم (ص) اور ان کے بعد ان کے حقیقی وارث ہی جانتے ہیں۔
( ذَلِکَ الْکِتَابُ لاَرَیْبَ فِیهِ هُدًی لِلْمُتَّقِینَ )
یہ وہ با عظمت کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ تقوی چاہنے والوں کی راہنما ہے۔
تعارف قرآن
الف،الکتاب :۔
ب،معجزہ:۔
ج،متقین کی ہدایت
کتاب
قرآن مجید کے ناموں میں سے پہلا نام کتاب ہے کتاب بمعنی مکتوب ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہے
کتب انزلنہ مبرک لیدبروا۔
یہ کتاب جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے ایک بابرکت کتاب ہے تا کہ لوگ اس میں غور وفکر کریں قرآن مجید کے ہر ہر جز کو قرآن،اور کتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو الفاظ لکھنے کے قابل ہوں اگرچہ انہیں ابھی تک نہ لکھا گیا ہو اسے بھی کتاب کہا جا سکتا ہے اسی وجہ سے کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہاں پہلی ہی آیت میں لفظ کتاب کیوں استعمال ہوا ہے۔
مندرجہ بالا جواب کے علاوہ اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ لوح محفوظ پر مکمل قرآن مجید موجود ہے اس لیئے یہاں اس کو کتاب کہا گیا ہے۔(۱)
ذالک کس کی طرف اشارہ ہے؟
بعض مفسرین کے نزدیک یہ (ذلک)اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداوندعالم نے سابقہ کتب تورات و انجیل میں بنی نوع انسان سے وعدہ فرمایا تھا(۲) کہ میں ایسی کتاب نازل کروں گا جس سے حق کے متلاشی ہدایت حاصل کریں گے جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا۔
( فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ )
جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جسے وہ پہلے سے جانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے۔(۳)
____________________
۰۰۰مجمع البیان ج ۱ ص ۱۸۸ ۰۰۰ ۰۰۰مجمع البیان ج ۱ ص ۰۰۰۱۱۸۰۰۰ سورہ بقرہ آیت ۰۰۰۸۹
حالانکہ یہ لوگ تورات و انجیل کی پیش گوئی کے مطابق اس کتاب کی نشانیوں سے بھی آگاہ تھے اور قرآن مجید نازل ہونے کا بھی انتظار کیا کرتے تھے جیسا کہ خداوندعالم کا ارشاد ہے۔
( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ )
اگر ہماری طرف سے ہدایت آجائے تو جو اس کی اتباع کرے گا اس کے لیئے کوئی خوف اور حزن نہ ہو گا۔(۱)
یہ کتاب وہی ہدایت ہے جس کے متعلق خداوندعالم بنی آدم سے عہد وپیمان کر چکا ہے۔
معجزہ
قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے متعلق ہم تفصیلی گفتگو اس سورہ کی ۲۳ آیت کے ضمن میں کرینگے البتہ یہاں اتنا بتانا ضروری ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالی پوری کائنات کو چیلنج کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے۔
قرآن مجید میں ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی حقانیت میں شک کیا جا سکے اور اس کے اعجاز اور وحی ہونے میں کسی قسم کی تردید نہیں ہے قرآن برملا کہ رہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو اس جیسا کوئی ایک سورہ لے آئے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ )
اگر اس میں آپ کو شک ہے،جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی مثل ایک سورہ ہی لے آؤ۔(۲)
_____________________
۰۰۰سورہ بقرہ آیت ۰۰۰۳۸ ۰۰۰ سورہ بقرہ آیت ۲۳۔
متقین کی ہدایت
کتاب اپنا تعارف اس انداز سے کرا رہی ہے کہ وہ متقین کے لیئے ہدایت ہے یہ جداگا نہ ہدایت ہے یعنی متقین کے لیئے دو ہدایتیں ہیں ایک وہ ہدایت جس کی وجہ سے وہ متقی بنے۔
دوسری وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرنے کے بعد انہیں عنایت فرمائی ہے یعنی پہلی ہدایت انسانی عقل اور فطرت ہے اور یہ فطرت سب لوگوں کے وجود میں ہے ہمیں اپنی اس فطرت کی سلامتی کی کوشش کرنی چاہیے جب ہم میں یہ تقوی آجائے گا تق پھر قرآن مجیدہمیں ہدایت کرئے گا۔
بالفاظ دیگر جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے دوگروہ ہیں ایک گروہ حق کا متلاشی ہے جہاں اسے حق وہدایت نطر آئے گا،اسے قبول کر لیں گے اور دوسرا گروہ ہوس پرستوں کا ہے کہ ہدایت و حق کے مخالف ہیں یہ گروہ ہدایت سے بہر ور نہیں ہو سکتا لہذ اقرآنی ہدایت صرف پہلے گروہ کے لیئے ہے۔
( الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ )
متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں،پابندی اور پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔
عموما تمام مکاتب اور مذاہب کا تین گروہوں کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے ایک گروہ اس مکتب کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ایک گروہ پوری طرح اس کا مخالف ہوتا ہے،اور ایک گروہ منافق ہوا کرتا ہے قرآن مجید بھی اس سورہ مبارکہ کے آغاز ہی سے ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کرتا ہے۔
( ۱) متقین،یہ گروہ اسلام کا پیروکار اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہے۔
( ۲) کافر،یہ لوگ اسلام کے مخالف اور مدمقابل ہیں اور ظاہر بظاہر اسلام کے دشمن ہیں۔
( ۳) منافق،یہ دورخ اور دوچہرے رکھنے والے لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے مسلمان بن بیٹھتے ہیں اور کافروں کے سامنے اسلام کے جانی دشمن نظر آتے ہیں۔
پہلا گروہ ۔ متقین
اسلام کے سامنے سرتسلیم کرنے والے اور تقوی چاہنے والے لوگوں کی قرآن مجید نے ان آیات میں چھ صفات بیان کی ہیں جبکہ اس آیة مبارکہ میں مندرجہ ذیل تین صفات کا تذکرہ ہے۔
( ۱) غیب پر ایمان
( ۲) نماز قائم کرنا
( ۳) انفاق فی سبیل اللہ
غیب پر ایمان
ایمان
قلبی اعتقادکا نام ایمان ہے اس میں زبان سے اقرار،اور عمل سے اظہار ضروری ہے یعنی ایسا اعتقاد جس میں شک و تردید کی گنجائش نہ ہو۔ایمان کے کئی مراتب ہیں کھبی تو فقط ایک چیز پر اعتقاد ہوتا ہے مثلا اللہ کے وجود پر اعتقاد رکھتے ہوئے ایمان لانا کبھی اس اعتقاد کا درجہ ایک حد تک بڑھ جاتا ہے جیسے اللہ کے وجود کے علاوہ آسمانی کتب اور ملائکہ پر اعتقاد رکھنا اور ان سب پر ایمان لانا اور کبھی یہ آخری درجہ تک پہنچ جاتا ہے جیسے اللہ،انبیاء علیہم السلام،ملائکہ کے علاوہ اصول دین اور فروع دین پر تہ دل سے ایمان لانا ایمان کا یہی درجہ ہی حقیقی ایمان ہے۔(۱)
جیسا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
الایمان هو تصدیق با لقلب،والاقرار بالسان،العمل بالارکان (۲)
دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور فروع دین پر عمل کا نام ایمان ہے۔
____________________
۰۰۰ میزان ج ۱ س ۸۷ (کچھ تبدیلی کے ساتھ )۰۰۰منہج الصادیقین ج ۱ ص ۱۳۶۔
ایمان بالغیب
غیب اور شہود ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں کیونکہ عالم محسوسات کا نام شہود ہے اور محسوسات سے ماورا دنیا ہماری حس سے پوشیدہ ہے یعنی ہر غیر محسوس چیز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اسے غیب کہتے ہیں،لیکن ہر غیب پر ایمان لان ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ اس سے ایسے امور مراد ہیں جو غائب بھی ہیں اور جزو ایمان بھی ہیں مثلا خداوند متعال کی با برکت ذات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔
( عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ) (۱)
(خداہی)غیب اور شہود کو جاننے والا ہے
قرآن مجید خدا کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے
( لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ )
ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں جبکہ وہ ہمیں دیکھتا ہے(۲) ۔
اس مقام پر صرف ذات پروردگار پر ایمان لانا مراد نہیں ہے کہ غائب کا ایک وسیع معنی ہے یعنی قرآن مجید،قیامت،وحی،فرشتے،اور عالم حس سے ما ورا ہر وہ چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے سب اس مفہوم غیب میں شامل ہیں تفسیر اھل بیت علیہم السلام میں اس غیب سے حضرت امام زمانہ عج
اللہ تعالی الشریف کی غیبت مراد ہے۔(۳)
جیسا کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام ” غیب “ پر ایمان کی لانے کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
من آمن بقیام القائم ( علیه السلام ) انه حق
جو شخص بھی قیام قائم (عجل اللہ الشریف) پر ایمان لائے اور انہیں حق سمجھے وہی غیب پر ایمان رکھنے والا ہے۔(۴)
_____________________
تفسیر کبیر ج۲ ص۰۰۰۲۸منہج الصادیقین ج۱ ص ۱۳۷ و نور الثقلین ج ۱ ص ۳۱،
۰۰۰میزان ج ۱ ص ۴۶ ۰۰۰
حضرت امام زمانہ عجل اللہ الشریف کے قیام کے متعلق حضرت نبی اکرم (ص) ارشاد فرماتے ہیں۔
لو لم بیق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذالک الیوم حتی تخرج رجل من اهل بیتی بواطئی اسمه اسمی وکنیته و کنیتی یملا ء الاارض عدل و مستطا کما قلت جورا وظلما
اگر اس دنیا کا فقط ایک دن ہی باقی رہ جائے تو اللہ تعالی اس دن کو اس قدر طویل کر دے گا یہاں تک کہ میری اھل کا ایک فرد آئے گا اس کا نام میرا نام ہو گا اور اس کی کنیت میری کنیت ہو گی ( یعنی اللہ اسے میرا نام اور کنیت عطا کرے گا )اور وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔(۱)
اس دور میں امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی غیبت پر ایمان رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام زمانہ ( عج) زندہ وسلامت ہیں اور ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ بہرحال ” غیب“ کے کئی مصادیق ہیں اسے چند مصادیق میں منحصر کر دینا درست نہیں ہے بلکہ ایمان بالغیب کا وسیع مفہوم ہے اللہ،قیامت، جنت، جہنم،انبیاء،ملائکہ،اور امام زمانہ (عج) اس کے مختلف مصادیق ہیں۔
____________________
(۱)تفسیر کبیر ج ۲، ص ۲۸، منہج الصادیقین،ج ۱، ص ۱۳۷، اسی مطلب پر روایت بحار الانوار ج ۵۲ ص ۱۲۴
اسی مطلب پر بحار النوار ج۵۲ ص۱۲۴
افضل اہل ایمان
حضرت رسول اکرم(ص) ایک دن اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے،آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ غیب پر ایمان رکھنے والوں میں افضل کون ہے؟
انہوں نے کہاوہ ملائکہ ہیں۔
حضرت نے فرمایا یہ میری مراد نہیں ہے۔
انہوں نے کہا وہ انبیاء جنہیں کتب اور رسالت ملی ہے،فرمایا نہیں۔
کہنے لگے اس سے شہداء مراد ہیں،فرمایا یہ بھی نہیں ہیں بلکہ میری مرادحضرت نے ارشاد فرمایا۔
اقوام فی اصلاب الرجال،یاتون من بعدی،یومنون بی و لم یرونی ویصدقونی ولم یرونی یجدون الورق المعلق فیعلمون بما فیه فهوالاء افضل اهل الایمان ایمانا
یہ ابھی لوگوں کے صلب میں ہیں، میرے بعد دنیا میں آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے،میری تصدیق کریں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہو گا، میری احادیث ان تک پہنچیں گی اور وہ اس کے مطابق عمل کریں گے،یہی لوگ افضل اہل ایمان ہیں۔(۱)
اس کے بعد آپ نے یومنون با لغیب کی تلاوت فرمائی یعنی یہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں اور پھر فرمایا یہ لوگ میرے بھائی ہیں،اصحاب نے سوال کیا۔یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔(۲)
____________________
۰۰۰در منثور ج ۱ ص ۲۶ ۰۰۰۰۰۰ منہج الصادیقین ج ۱،ص ۱۳۸
اسی مطلب کے مشابہ حدیث بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۱۲۳
آپ نے ارشاد فرمایا
انتم اصحابی و هم اخوانی
آپ میرے اصحاب ہو اور وہ میرے بھائی ہیں۔
( ۲) نماز قائم کرنا
متقین ایمان پر غائب رکھتے ہیں اور غائب پر ایمان رکھنا عمل سے جدا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عمل بالارکان میں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کو اس مقام پر بیان کیا جا رہا ہے یہ متقین کی دوسری خصوصیت ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز کو مکمل اہتمام،کمال وضو،اورسنت نبوی کے عین مطابق بجا لانا واجب اور ضروری ہے کیونکہ یہاں صرف نماز پڑھنا مراد نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی میں نماز کوزندہ کرنا اور نماز کی ترغیب دلانا مراد ہے۔
نماز کے حقوق
نماز کے دو حقوق ہیں
( ۱) ظاہری حقوق
( ۲) باطنی حقوق۔
ظاہری حقوق سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے شرائط اور آداب سے بجا لانا چاہیے،نماز کے متعلق تمام ضروری مسائل کا علم ہونا چاہیے۔
باطنی حقوق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور حقیقی خشوع و خضوع اور اس کا محتاج ہونے کا احساس کرتے ہوئے نماز ادا کی جائے اسلامی معاشرہ میں نماز کو زندہ کیا جائے،لوگوں کی توجہ نماز کی طرف مبذول کرائی جائے۔
یہی نماز تقوی چاہنے والوں کے لیئے خدا اور عالم غیب کیساتھ دائمی رابطہ اور اتصال کی موجب ہے اس مقام پر قرآن مجید متقی اور پرہیز گاروں کی صفت بیان کرتے ہوئے انہیں والمتقین الصلوة یعنی نماز قائم کرنے والوں میں شمار کرتا ہے۔
جو متقی نہیں ہیں،نماز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور نماز کی صحیح منوں میں حفاظت نہیں کرتے،قرآن مجید ان کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے۔
( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ )
ایسے نمازیوں کے لیئے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں(۱)
انفاق فی سبیل اللہ
قرآن مجید متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے انہیں تلقین کر رہاہے کہ اپنے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں یہ بندوں کا خدا کے رابطہ کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی رابطہ کا موجب ہے متقین ایثار کے جذبہ کی وجہ سے خود پسندی اور خود پرستی سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے اس سے انہیں قلبی اور روحانی سکون میسر ہوگا اور ان کا دل قرآنی ہدایت کے نور سے منور ہو جائے گا۔(۲)
خداوند عالم نے اس سے پہلی صفت میں نماز قائم کرنے پر زور دیا ہے کیونکہ نماز تمام دینی اعمال میں افضل ترین عمل ہے جب کہ یہاں انفاق کی طرف اشارہ فرمارہاہے کیونکہ عبادت مالیہ میں افضل ترین عبادت زکوة واجبی ہے۔(۳)
____________________
۰۰۰ سورہ ماعون آیت ۴،۵ ۰۰۰ناطق ج ۱ص ۰۰۰۴۵ ۰۰۰منہج ج ۱ ص۰۰۱۳۸
البتہ یہاں خدا وند عالم تمام نعمتوں میں سے انفاق کرنے کا حکم دے رہاہے اور فرمارہاہے کہ جو کچھ ہم نے رزق ادا کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں یعنی اس کے مفہوم میں وسعت پائی جاتی ہے،یہ صرف واجبی زکوة مراد نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو نعمت خدا وندی ہے اس
میں انفاق کرنا ضروری ہے یعنی علم،عقل، فن،ہنر وغیرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا متقی کہلانے کا حق دار ہے جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب مما رزقنہم کی تفسیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس سے یہی وسیع مفہوم اور معنی مراد لیا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو ملی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کتنے والا متقی ہے معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
ان معناه و مما علمنا هم یبثون ۔(۱)
اس کا معنی یہ ہے کہ جن علوم کی ہم نے انہیں تعلیم دی ہے یہ اس علم کو لوگوں میں پھیلاتے رہیں۔
یعنی اس علم کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں لہذا اس آیت مجیدہ سے فقط واجبی زکوة مراد نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم اور معنی میں وسعت پائی جاتی ہے اور اس سے مرا د اللہ کی طرف سے ملنے والا ہر رزق ہے ہمیں اس رزق سے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہوگا خواہ وہ واجب ہو یا مستحب ہو۔(۲)
____________________
۰۰۰جوامع الجامع ج۱ ص۶۵۰۰۰تفسیر کبیر ج ۱ص۳۱،مجمع البیان ج۱ ص۰۰۰۱۲۲
( وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ )
(یہی لوگ )آپ اور آپ سے پہلے (انبیاء)پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کایقین رکھتے ہیں۔
خدا وند متعال اس آیت میں بھی متقین کی تین صفات اور بیان فر ما رہا ہے
( ۱) قرآن پر ایمان
( ۲) سابقہ انبیاء کی کتب پر ایمان
( ۳) آخرت کایقین
قرآن پر ایمان
قرآن مجید متقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہاہے یہ لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور دل اور زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اس کے فرمودات اور ارشادات پر عمل پیرا ہو کر قلبی سکون حاصل کرتے ہیں یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآنی علوم کو سیکھے،اس پر عمل کرے اور اس عظیم کتاب سے سبق حاصل کرے۔
(الف)قرآن مجید تمام آسمانی کتب کا وارث ہے
یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس پر تفصیلا ایمان رکھنا ہو گا جب کہ اس سے پہلی کتابوں پر اجمالی ایمان رکھنا ہی کافی ہے یعنی قرآن مجید کی اتباع اورچ پیروی واجب ہے۔جب ہم لوگ قرآن مجید اور اس شریعت پر عمل کریں گے تو گویا ہم نے تمام الہی کتب اور تمام سابقہ شریعتوں کی پیروی کی ہے کیونکہ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کا وارث ہے اس پر عمل تمام کتب پر عمل ہے شاید اسی وجہ سے اللہ تعالی نے پہلے قرآن مجید پر عمل و ایمان کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد دوسری کتابوں پر ایمان رکھنے کا کہا۔
(ب)آخری کتاب
جس طرح حضرت محمد مصطفی (ص )خاتم الانبیاء قرآن مجید بھی خاتم الکتب ہے اور یہ آیت بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی خدا کہہ رہاہے کہ ہم نے جو کچھ آپ اور آپسے پہلے انبیاء پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لانے والا ہی پرہیزگار اور متقی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد جو نبی اور شریعت ہوگی اس پر بھی ایمان لائیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے یعنی آپخاتم الانبیاء ہیں اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔
( ۲) سابقہ انبیاء کی کتب پر ایمان
تقوی چاہنے والوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی(ص)کے عظیم اور بے مثال معجزہ (قرآن )پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اور ان کی کتب پر بھی ایمان رکھتے ہیں خدا وند عالم نے کائنات کو انسان کے لئے خلق کیا ہے اور اس کی تربیت کے لئے وحی نازل فرمائی کیونکہ انبیاء اور آئمہ اطہار کے بغیر حقیقی راہ کی تلاش اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔
اسی وجہ سے خدا وندعلم نے متقین کے لئے واجب قرار دیا ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی کتب پر ایمان رکھیں یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ساتھ ان کی ( ۱۰۴) کتابوں پر ایمان رکھنا واجب ہے۔(۱)
وحدت ادیان الہی
تمام انبیاء کا ایک ہی ہدف تھا وہ احکام خدا وندی کے بجا لانے یعنی واجبات کی ادائیگی کا کہنے کے ساتھ ساتھ محرمات سے ہمیں روکتے رہے ہیں ان کے ہدف کا ایک ہونا ہی ادیان الہی کی وحدت کی علامت ہے یہ ادیان فرقہ بندی،تضاد اور نفاق کے موجب نہیں ہیں بلکہ انسان ی فکر اور روح کو تعصب سے دور رکھتے ہیں۔
____________________
(۱)جیسا کہ حضرت ابوذر آسمانی کتب کی تعداد کے حوالہ سے حضرت رسول اکرم (ص) سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آسمانی کتب (۱۰۴)ہیں۔
ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام پر (۵۰) صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر (۳۰) صحفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر (۱۰) صحیفے تورات سے پہلے حضرت موسی علیہ السلام پر (۱۰) صحیفے،تورات،زبور،انجیل،اور قرآن مجید۔
یہی وجہ ہے کہ گذشتہ انبیاء کے دستورات ہر ایمان رکھنا قرآن پر ایمان رکھنے سے دور نہیں کرتا بلکہ سب پر ایمان رکھنے کے مترادف ہے نیز امت محمدیہ (ص) کی ہی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنی شریعت اور کتاب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ گذشتہ انبیاء اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
باقی ادیان اس طرح نہ تھے بلکہ صرف اپنے اپنے نبی اور کتاب پر ایمان رکھتے تھے مثلا یہودی صرف حضرت موسی اور توریت پر ایمان رکھتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسی اور انجیل ہی کو مانتے ہیں اور سابقہ اور آنے والی تمام شریعتوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والی امت کے لئے حضرت محمد مصطفی (ص) کے ساتھ ساتھ تمام ادیان الہی کی حقانیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔
آخرت کا یقین
متقین کی چھ صفات میں سے چھٹی صفت یہ ہے کہ انہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے پہلی پانچ صفات پر ایمان رکھنے والا متقی پرہیز گار کہلوانے کا حق دار تھا لیکن اب کہا جا رہاہے کہ آخرت کا یقین ہو نا ضروری ہے۔دل سے تصدیق،زبان سے اقرار اور اصول دین اور فروع دین پر صحیح عمل کرنے کا نام ایمان ہے جب کہ یقین کا درجہ ایمان سے زیادہ ہے کیونکہ یقین ایسا اعتقاد ہے جو واقعہ کے مطابق ہو،اس میں شک وشبہ کی گنجائش بھی نہ ہو اور یہ زائل بھی نہ ہوتا ہو۔
مرحلہ یقین میں دو اعتقاد ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ شئی اس طرح ہے مثلا قیامت یقینا ہے اور یقین میں دوسرا یہ عقید ہ بھی پایا جا تا ہے کہ جس طرح یہ چیز ہے اس کے علاوہ اس کا امکان نہیں ہے یعنی اس میں کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مثلا آخرت میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہر صورت میں قیامت واقع ہوگی اس کے نہ ہونے کا امکان نہیں ہے مرحلہ یقین تک پہنچنے کے لئے عبادت خدا وندی کرنا ہو گی جیسا کہ خدا وند متعال ارشاد فرماتا ہے۔
( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ )
اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو کہ مرحلہ یقین تک پہنچ جاؤ(۱)
بہر حال حقیقی تقوی آخرت ہر یقین کے بغیر پیدا نہیں ہوسکتا،آخرت پر یقین سے مراد یہ ہے کہ ہمیں آخرت،حساب وکتاب،سوال،جنت،جہنم۔منکر،نکیر وغیرہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو نا چاہیے اور ہر وقت آخرت یاد رہنی چاہیے آخرت پر قلبی یقین نہ رکھنے والوں کے متعلق حضرت رسول اکرم (ص) تعجب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔
و عجبنا ممن یعرف ا لنشاء ة الاولی ثم ینکر النشاء ہ الاخرة،و عجبنا ممن ینکر البعث والنشور وھو فی کل یوم و لیلہ عوت و یحیا و عجبنا ممن یومن بالجنہ وما فیھا من النعیم ثم یسعی لداالغرور
مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی خلقت کا تو قائل ہے لیکن قیامت والے دن دوبارہ اٹھنے کا منکر ہر اور مجھے اس پر تعجب ہے جو ہر روز مرنے اور جینے کے باوجود (سونے اور جاگنے )اور مرنے اور جینے کا منکر ہے اور جسے ایسے شخص پر تعجب ہے کہ جنت پر ایمان رکھنے والا شخص کس طرح مغرور دنیا کی چا ہت رکھتا ہے(۲)
____________________
(۱)حجرآیت۹۹(۲)تفسیر کبیر ج ۲ ص۳۳،منہج الصادقین ج۱ ص۱۴۳
( أُوْلَئِکَ عَلَی هُدًی مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ )
یہی وہ لوگ ہیں جو پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔
ہدایت اور کامیابی
خدا وند متعال متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد ان کے مقام اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمارہاہے کہ جو لوگ اپنی ساری زندگی،عقیدہ،عدل،خدا نبوت اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں خدا اور مخلوق کے ساتھ ان کا گہرا تعلق قائم ہے و ہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔
اس کائنات کی افرینش کا ہدف عبادت خدا وندی ہے اور عبادت کا ہدف تقوی ہے اور تقوی کی انتہا کامیابی پر ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان صفات کے حامل متقین کی عظمت بیان کرتے ہوئے فر ما رہاہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہونگے اور کامیابی ان کا مقدر ہو گی۔
یہ ہدایت اور کامیابی بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے اللہ تعالی نے انہیں تقوی اختیار کرنے کے بعد ایک خصوصی عنایت فرمائی ہے اس سے پہلے اللہ تعالی نے اسے عقل اور فطرت عطا فرمائی تھی وہ بھی ایک ہدایت تھی اوراب متقی اور پرہیزگار بن گیا اور تمام اوصاف کا حامل ہو گیا تو اللہ تعالی نے اسے انعام میں خصوصی ہدایت اور کامیابی عطا فرمائی ہے کیونکہ یہاں (ھدی)نکرہ ہے یہ بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہاہے کہ یہ لوگ خدا تعالی کی طرف سے بہت عظیم ہدایت پر فائز ہیں(۱)
خدا وند متعال نے انہیں ھم المفلحون کہہ کر یاد فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان صفات کے حامل ہی کامیاب ہیں ان کے علاوہ کسی کے لئے کامیابی نہیں ہے(۲)
ایمان اور عمل میں استمرار
قرآن مجید نے متقین کی صفات کا تذکرہ فعل مضارع کے ساتھ کیا ہے ( ۳) فعل مضارع ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے ____________________
(۱)روح المعانی ج ۱ ص ۱۲۴(۲)تفسیر نمونہ ج۱ ص۹۳
(۳)یومنون بالغیب،یقیمون الصلوة،ینفقون،یومنون بما انزل با لاخرةهم یوقنون
یعنی صرف ایک مرتبہ اس خصوصیت کا مالک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ استمرار پر دلالت کرتا ہے یعنی آخر دم تک ان تمام پر عمل کرتے رہنا واجب ہے حقیقی متقی وہی ہیں جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور زندگی کے نشیب وفراز سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ایمان اور عمل میں تسلسل اور دوام رکھتے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی عظیم ہدایت اور کامیابی کے حقدار ٹھیریں گے۔
( إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَیُؤْمِنُونَ )
بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیئے مساوی ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
دوسرا گروہ سرکش کفار۔
قرآن کی ان ۲۹ آیات میں تین گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔پہلا گروہ تقوی چاہنے والے متقین کا ہے،یہ لوگ پوری طرح حق کو پہچاننے، قبول کرنے اور اور اس پر عمل کرنے کے لیئے آمادہ تھا اب دوسرے گروہ کو بیان کیا جا رہا ہے جو کفر چاہنے والے ہیں اور اپنی گمراہی میں اس قدر مصر ہیں کہ انکے لیئے حق جتنا واضح ہو جائے یہ اسے قبول کرنے کے لیئے تیار نہیں ہیں بلکہ دین اسلام کے دشمن ہیں۔
شناخت کافر
کسی چیز کا چھپانا اور انکار کرنا کفر ہے اور اس مقدس شریعت میں وہ شخص کافر ہے جو اللہ ک تبارک وتعالیٰ کی وحدانیت،صفات،کتب الہی،انبیاء،اور ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تمام کو نہ مانے ( ۱)
یعنی حضرت محمد مصطفی (ص) جو کچھ لائے ہیں ان سب پر ایمان لانا واجب ہے کوئی ان سب کا انکار کرے یا بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے تو بھی کافر کہلاتا ہے
____________________
(۱)یعنی اصول دین،فروع دین،قرآن اور آئمہ اطہار علیہم السلام کو تسلیم نہ کرنے والا اور ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔
منکر حق
حق کے منکر وہ لوگ ہیں جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیتے ہیں ان کی تعداد انتہائی کم ہے جیسا کہ حضرت رسول اکرم (ص) کے زمانہ میں بعض مشرکین مکہ اور کچھ یہودی ایسے تھے جو حضرت پہچاننے کے باوجود اپنے کفر پر ڈٹے رہے حالانکہ حضرت کی بعثت سے پہلے یہ حضرت کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔
( فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ )
(جنہیں وہ پہلے سے جانتے تھے )جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کفر اختیار کیا۔
ان یہودیوں کی طرح مشرکین مکہ بھی آپ کے اوصاف سے آگاہ تھے،انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ سید الانبیاء ہیں اس کے باوجود یہ حسد اور عناد کی وجہ سے کفر پہ باقی رہے۔ جیسا کہ مکہ میں نازل ہونے والی سورة یس میں اللہ تبارک وتعالی فرماتا ہے۔
( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ) (۱)
ان کے لیئے مساوی ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
لہذا مشرکین قریش ہوں یا یہودی جنہوں نے بھی دین اسلام قبول کرنے میں جاہلانہ تعصب اور عناد کا اظہار کیا ہے اور دین اسلام کی دشمنی میں ہر قسم کی سعی و کوشش کی ہے اور اسلام کو قبول نہیں کیا ہے ان کے لیئے ہدایت کا دروازہ بند ہے، حتی کہ اس قرآن مجید سے جوتقوی چاہنے والوں کے لیئے منبع ہدایت ہے یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہو سکتے۔
لہذا انہیں کچھ کہیں یا نہ کہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں بشارت دیں یا نہ دیں،انہیں وعظ و نصیحت کریں یا نہ کریں،یہ لوگ حق کی پیروی اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیئے آمادہ ہی نہیں ہیں جیسا کہ قرآن مجید ان کی خواہش بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔
( قَالُوا سوَاءٌ عَلَیْنَا أَ وَعَظت أَمْ لَمْ تَکُن مِّنَ الْوَعِظِینَ ) (۲)
ہمیں وعظ و نصیحت کریں یا نہ کریں ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا۔
____________________
۰۰۰سورہ یس آیت ۱۰۔۰۰۰ ۰۰۰ سورہ شعراء آیت ۱۳۶۔۰۰۰
ایمان فعل اختیاری ہے
قرآن مجید کی ہدایت کا دروازہ فقط جاہلانہ تعصب اور عناد رکھنے والے کفار کے لیئے بند ہے لیکن جو لوگ (کفار) عناد اور تعصب نہیں رکھتے ان کے لیئے ہدایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس سے مراد کفروں کے تمام طبقات ہوتے تو پھر انہیں قرآنی ہدایت ہی نصیب نہ ہو سکتی حضرت کے مبعوث ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جبکہ آپ تو رحمت العالمین بن کر آئے ہیں، آپ نے ہر طبقہ کو اسلام کی دعوت دی ہے آپ کے انذار اور بشارت کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور جن لوگوں نے اپنے نطریات اور عقائد کو چھوڑ کر ایمان کو اختیارکیا ہے انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔
جنہوں نے عناد اور سو اختیار کی وجہ سے اپنے باطل نطریات کو نہیں چھوڑا اور اسلام سے دشمنی اور بغض کو باقی رکھا انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک اختیاری فعل ہے۔
( خَتَمَ اللهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَعَلَی سَمْعِهِمْ وَعَلَی أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ) ( ۷)
خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔
کفار کی ضلالت :
الف: دلوں اور کانوں پر مہر۔
ب: تشخیص کی قدرت نہیں رکھتے۔
ج :مستحق عذاب
خدا وند عالم اس آیت میں کفار کی دو اہم نشانیاں بیان فرمارہا ہے جس میں واضح طور پربتایا گیا ہے کہ یہ لوگ تعصب اور عناد میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ خدا نے ان کے دکوں اور کانوں پر مہر لھا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے کیونکہ قلب کا فائدہ حق کو درک کرنا ہے۔سماعت کا ثمرہ آیات قرآنی سننا ہے اور بصارت کا نتیجہ معجزات خداوندی کو دیکھنا ہے۔یہ تینوں خصوصیا ت ان کفار میں موجود نہیں ہیں۔لہذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ کھبی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اپنی ضلالت پر مصر رہیں گے۔
الف :دلوں اور کانوں پر مہر۔
خداوند عالم کا ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دینا اس بات کا کنایہ ہے کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے خداوند عالم نے مہر لگا دی ہے جیسا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
الختم هو الطبع علی قلوب الکفار عقوبةعلی کفرهم ۔(۱)
ختم سے مراد کافروں کے دلوں پر ان کے کفر کی سزا کے طور پر مہر لگا دینا ہے۔
اللہ کی طرف سے مہر لگ جانے کا فعل انسان کے کفر اختیاری کے بعد ہوتا ہے،کفر سے پہلے نہیں ہوتا اور یہ کفر اختیاری کا نتیجہ ہے یعنی ہر انسان کو فطرت سلیم عطا ہو تی ہے اور اس میں دلائل حق پر غور وفکر کی استعداد بھی شامل ہے لیکن جب انسان اپنے ارادے اور عقل کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر آسمانی ہدایتوں اور خداوندی نشانیوں سے مسلسل منہ موڑ لیتا ہے اور شیطانی قانون پر چلنے کی ٹھان لیتا ہے۔
اس وقت وہ غضب کا مستحق ٹھرتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ رحمت سے خارج ہو جاتا ہے اس وقت نصرت الہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور واضح دلائل حقاور روشن سے روشن آیات الہی بھی انہیں نظر نہیں آتیں یہ سب کچھ کافروں کا اپنے ارادے اور اختیار سے دوری اور دانستہ کج روی اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔
بہرحال یہ مسلم ہے جب تک انسان اس مرحلے تک نہ پہنچے وہ کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو،قابل ہدایت ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنے بد اعمال کی وجہ سے پہچان کی قوت کھو بیٹھتا ہے تو اس کے لیئے کوئی راہ نجات نہیں ہے۔
_____________________
۰۰۰تفسیر صافی۔۰۰۰
توبہ و استغفار
یہ واضح حقیقت ہے کہ انسان جب ایک گناہ پر اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اے کچھ سجھائی نہیں دیتا وہ اسے حق اور درست سمجھنے لگ جاتا ہے لہذا انسان کو ہمیشہ اس طرف متوجہ رہنا چاہیے جب اس سے کوئی گناہ سر زد ہو فورا اسے توبہ کر لینی چاہیے تا کہ اس کے دل پر مہر نہ لگ جائے جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
ما من عبد مومن الا و فی قلبه نکتة بیضاء فاذا اذنب ذنبا خرج فی تلک النکتةسواد فان تاب ذهب ذالک السواد فان تماری فی الذنوب ذاد ذالک السوادحتی یغتی البیاض فاذا اغطی البیاض لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا ۔(۱)
ہر شخص کے دن میں ایک وسیع،سفید اور چمکدار نکتہ ہو تا ہے جب اس سے گناہ سر ذد ہو تو اس مقام پر ایک سیاہ نکتہ پیدا ہو تا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر مسلسل گناہ کرتا رہے تو پھیل جا تی ہے اور تمام سفیدی کا احاطہ کر لیتی ہے اور جب سفیدی ختم ہو جائے تو پھر اسے دل کا مالک کبھی بھی خیر و بر کت کی طرف نہیں پلٹ سکتا۔
لہذا جب بھی انسان ہوائے نفس کا غلام بن جائے تو ایسے کان جن سے پرہیز گار حق بات سن سکتا ہے سنتے اور عمل کرتے ہیں اور ایسے دل جس سے متقی لوگ حقائق کا ادراک کرتے ہیں،کفار کے لئے بے کار ہیں ان کے کانوں اور دلوں میں سننے اور سمجھنے کی قوت ہی نہیں رہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔
( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ )
کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگادی ہے۔(۲)
____________________
(۱)اصول کافی ج۲باب الذنوب حدیث۲۰
(۲)سورہ جاثیہ ۴۵ آیت نمبر ۲۳
ب :تشخیص کی قدرت نہیں۔
یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان جب ایک غلط کام کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور روح انسانی کا جزو بن جاتی ہے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو وہ حس تشخیص ہی کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آجاتا ہے یہ لوگ اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے،عبرت حاصل نہیں کرتے،صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتے بلکہ حق کو دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں پر گمراہی اور کفر کا پردہ ڈال رکھا ہے۔
لیکن قیامت والے دن بہت سے حقائق ان کے سامنے ہونگے۔عذاب الہی کو درک کریں گے۔اور یہ بھی جانتے ہونگے کہ یہ ان کے سوء اختیار کی وجہ سے ہے دنیا میں خود کو اندھا بنا رکھا تھا اگرچہ ان کی آنکھیں جمال الہی کا مشاہدہ نہیں کر سکتیں لیکن قیامت والے دن تیز نگاہوں سے عذاب الہی کا ضرور مشاہدہ کریں گی جیسا کہ خدا وندعلم فرماتا ہے۔
( لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ )
یقینا تم غفلت میں تھے ہم نے تمہارے پردوں کو ہٹا دیا ہے اب تمہاری نگاہ تیز ہو گئی ہے۔
ج :مستحق عذاب
جس طرح خدا وند عالم نے تقوی طاہنے والوں کا انعام ہدایت اورکامیابی قرار دیا تھا اسی طرح کفار کی سزا یہ ہے کہ قیامت والے دن انہیں بہت بڑے عذاب کا سامنا ہو گا۔
( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِینَ ) ( ۸)
کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں حالا نکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔
شان نزول
کفار کی مذمت کے بعد تیرہ آیات منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہیں منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی سلول یعتصب بن قشیر اور ان کے پیروکار وں کے درمیان طے پایا کہ ہم لوگ بھی زبانی کلامی تو اسلام کا اظہار کریں۔
لیکن قلبی طور پر اپنے عقیدہ پر قائم رہیں تا کہ مسلمانوں کو جو شرف و منزلت نصیب ہے ہمیں بھی حاصل ہو ہم رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مقربین بن کر اسلام کے اسرار سے آگاہ ہو سکیں اور کفار کو ان اہم رازوں سے باخبر رکھیں یہ لوگ سوچی سمجھی سازش کے تحت رسول اکرم کے پاس تشریف لائے اور اسلام کا اظہار کرنے لگے اس وقت خدا وند عالم نے حضرت رسول اکرم (ص) کو ان کی سازش سے اس طرح آگاہ فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدااور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں حالانکہ یہ خدا اور آخرت پر ایمان نہیں لائے بلکہ یہ لوگ جھوٹ بکتے ہیں۔(۱)
تیسرا گروہ : منافقین
منافق کی شناخت
تاریخ کے ایک خاص موڑ پر اسلام کو ایک ایسے گروہ کا سامنا کرنا پڑا جو ایمان لانے کے جذبہ و خلوص سے عاری تھا اور اسلام کی مخا لفت کرنے کی جرات بھی نہیں رکھتا تھا قرآن مجید اس گروہ کو منافق کہہ کر پکار رہاہے قرآن کے نزدیک منافق کی پہچان یہی ہے کہ۔
المنافق الذی ستروا الکفر و و اظهروا الا سلام
جو کفر کو پوشیدہ رکھتے ہوئے اسلام کا اظہار کرے وہ منفق ہے(۲)
_____________________
(۱)منہج الصادقین ج۱ ص ۰۰۰۱۵۲ (۲)البتیان ج۱ ص۶۷،روح المعانی ج۱ ص۱۴۳
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادیان الہی کو سب سے زیادہ نقصان منافقین سے پہنچا ہے اسی گروہ نے صدر اسلام سے اسلام اور مسلما نوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔تاریخ گواہ ہے اس گروہ نے کافر وں سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے شاید اسی وجہ سے اس مقام پر تیرہ آیتوں میں ان کی باطنی شخصیت اور اعمال کو بیان کیا گیا ہے جبکہ دوسری سورتوں میں بھی ان کی بدکرداریوں کا تذکرہ ہے اور ان کے متعلق قرآن مجید کا واضح فیصلہ ہے۔
( إِنَّ الْمُنافِقينَ فِي الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ )
بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہونگے۔(۱)
حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منافق کی شناخت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
اوصیکم عبادالله بتقوی الله،واحذر کم النفاق فانهم الضالون المضلون والزالون المنزلون یتلونون الوانا و یفتنون افتینا نا و یعمدونکم لکل عماد و تر صدونکم بکل مرصاد قلوبهم دویه و صفاحهم نفیه یمشون الخفا ء و تدبون الضراء وصفهم دواء و قولو هم شفاء وفعلهم الداء العیا ء خنسدة الرخا ء و مئو کدو البلد ء مقنطوالرخاء ۔(۲)
اے اللہ کے بندوں :میں تمہیں تقوی و پرہیز گاری کی وصیت کرتا ہوں اور منا فقین سے ڈراتا ہوں کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں،خود خطاء کار ہیں دوسروں کو خطاؤں میں ڈالتے ہیں،مختلف رنگ اختیار کرتے ہیں،مختلف چہروں اور زبانوں سے خود نمائی کرتے ہیں،ہر طریقہ سے پھانسنے اور برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
_____________________
(۱)سورہ نساء آیت ۱۴۵(۲)نہج البلاغہ خطبہ ۱۹۴
یہ لوگ ہر کمین گاہ میں تمہارے شکار کے لئے بیٹھے رہتے ہیں ان کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے خفیہ چالیں چلتے ہیں ان کی ظاہری گفتگو بھلی معلو م ہوتی ہے لیکن ان کا کردار ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے لوگوں کی خوش حاکی اور آسائش پر حسد کرتے ہیں اور اگر کسی پر مصیبت آن پڑے تو خوش ہوتے ہیں اور امید رکھنے والوں کو مایوس کر دیتے ہیں۔ بہر حال زیر نظر تیرہ آیتوں میں منا فقین کی صفات بیان کی جارہی ہیں۔کیونکہ ایمان دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے لیکن ان کے دلوں میں کفر ہے اور زبان سے دعوی کرتے ہیں یہ نفاق اور منافقت ہے۔
چال بازی
جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے گروہ میں اپنا اثر رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے یا کسی گروہ میں اپنا نفوذ کرنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس گروہ کے اصولوں کو اپنائے اور ان اصولوں کے پیروکاروں کے سامنے یہی اظہار کرے کہ میں ان اصولوں کا پابند ہوں خدا اور قیامت پر ایمان اسلام کے اہم اعتقادی اصولوں میں سے ہیں۔
جب کوئی شخص ان پر ایمان لانے کا اظہارکرتا ہے تو اسے مسلمان تصور کیا جاتا ہے منافقین نے بھی مقصد کے حصول کے لئے ان دو بڑے اصولوں کا سہارا لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن مجید قطعی طور پر ان کے ایمان کی نفی کر رہاہے کہ اگرچہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو خود کو مومن کہتے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے یعنی یہ لوگ نہ مومن تھے،نہ مومن ہیں اور نہ مومن ہونگے بلکہ یہ چالباز ہیں ان کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہچانا ہے۔
( یُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُونَ )
وہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھو کہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے سوا ء کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور انہیں( اس کا )احساس تک نہیں ہے۔
خود فریبی
یہ ایک واضح حقیقت ہے جو بھی اللہ تعالی کو اس کی صفات جلال وکمال کے ساتھ مانتا ہو وہ اسے دھوکہ دینے کا تصور ہی نہیں کر سکتاکیونکہ وہ ہستی ظاہر و باطن سے باخبر ہے البتہ ان کا یہ کہنا کہ ہم خداکو دھوکہ دیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ خدا کو نہیں پہنچانتے ان کا اللہ کے متعلق اقرار صرف زبانی ہے اس لئے یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کودھوکہ دے رہے ہیں۔نیز اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ خدا اور مومنین کو جو دھوکہ دیتے ہیں یہ شاید رسول خدا (ص) اور مومنین کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ہو کیو نکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول خدا کے متعلق فرمایا ہے۔
( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) (۱)
جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ اطاعت کرتا ہے۔
اسی طرح اللہ کا یہ فرمان بھی ہے۔ان الذین یبایعونک انما یبا یعون اللہ جو بھی آپ کی بیعت کرتا ہے وہی اللہ کی بیعت کرنے والا ہے۔
لہذا رسول خدا (ص)کی اطاعت اور بیعت اللہ کی بیعت ہے اسی طرح ورسول خدا کو دھوکہ دینا اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا ہے لہذا خدا،رسول،اور مونین کو دھوکہ دینا ان کی خود فریبی ہے یہ خدا کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی اور جزا ء سزااور نقسان بھی انہی کے ساتھ ہے۔
____________________
(۱)سورہ نساء آیت نمبر۱۰
یعنی ایمان کا نتیجہ نجات آخرت ہے یہ لوگ تمام کوششوں کے باوجود اس سے دور رہتے ہیں بلکہ اس فریب دہی کی وجہ سے ان کا عذاب کافروں کے عذاب سے بھی سخت تر ہو تا ہے جیسا کہ خدا وند عالم کا ارشاد ہے۔
( إِنَّ الْمُنافِقينَ فِي الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ )
بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہونگے۔(۱)
لیکن ان منافقین کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ دل سے آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں یہ لوگ صرف مادی منافع حاصل کر کے خود کو فریب دہی میں کامیاب سمجھتا ہے حالانکہ اس کی خود فریبی ہے جیسا کہ روایت میں ہے۔ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش خود فریبی ہے۔
اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت رسول اعظم (ص) کی حدیث بیان فرماتے ہیں۔
انماالنجاة ان لا تخادعوا فینحد عکم فان من یخادع الله یخدعه ویخلع منه الایمان و نفسه یخدع لو یشعر
انسان کی نجات اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالی کو دھوکہ دینے کی کو شش نہ کرے وگرنہ وہ خود دھوکہ میں پڑ جائے گا کیونکہ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجہ میں خود دھوکہ کھائے گا اور اس سے ایمان کا لباس اتارلیا جائے گا اگر اسے تھوڑا سا بھی احساس ہے تو یہ اس کی خود فریبی ہے۔(۲)
____________________
(۱)نساء آیت ۱۴
(۲)صافی،نور الثقلین ج۱ص۳۵
( فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکْذِبُونَ )
ان کے دلوں میں ایک خاص طرح کی بیماری ہے اللہ نے (نفاق کی وجہ سے) ان کی بیماری اور بڑھادی ہے،اور انہیں ایک درد ناک عذاب اس وجہ سے ہو گا کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔
بیمار دل
اعتدلال طبعی سے ہٹ جانا بیماری اور مرض ہے جب انسانی بدن میں کوئی آفت نہ ہو تو اس بدن کو صحیح و سالم کہتے ہیں اسی طرح اگر کسی دل میں ہٹ دھرمی تعصب اور کوئی آفت و مصیبت نہ ہو تو اسے قلب سلیم سے یاد کیا جاتا ہے اور اس وقت اس کا دل حق کو قبول کرنے کی بھر پور صلاحیت رکھتا ہے۔
جب کہ منافقین کے دل نفاق جیسی آفت کی وجہ سے بیمار ہیں ان کے جسم اور روح میں ہم آہنگی نہیں ہے بلکہ یہ ایمان سے منحرف ہیں ان کاظاہر اور باطن اس انحراف کی نشاندہی کرتا ہے اس کے دل میں شک و کفر اور نفاق پروان چڑھتا رہتا ہے اس بیماری کی وجہ سے ہدایت کے پیغام،واعظ و نصیحت کی آیات اسے فائدہ پہنچانے کے بجائے اس کے عناد،تعصب اور جوش انکار میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔
اس کی ذمہ داری خود اس کے ذاتی سوء مزاج پر ہے یعنی جب بھی کوئی قرآنی آیت نازل ہوتی ہے،معجزہ ظاہر ہوتا ہے،رسول خدا کو فتح نصیب ہوتی ہے،اللہ کی طرف سے ان انعام و اکرام ہوتا ہے تو منافق کی عداوت اور منافقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
جھوٹ کی سزا
منافقین کا اصل سرمایا جھوٹ ہے ان کا اظہار اسلام ہی جھوٹ کا پلندہ ہے یعنی یہ لوگ جب یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالی حضرت رسول اکرم(ص) کو خبر دیتا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔
لہذا اپنے دعوی میں جھو ٹے ہیں یعنی در حقیقت یہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرمودات کو ماننے کا جو دعوی کرتے ہیں وہ سفید جھوٹ ہے بلکہ یہ لوگ منافق ہیں ان کے جھوٹ اور منافقت کی سزا درد ناک عذاب الہی ہے۔
اگرچہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ کفر سے بد تر نہیں ہے کیونکہ کفر و نفاق تمام گناہوں کی جڑ ہے لہذا اس دروغ گوئی کی وجہ سے منافقوں کو جو درد ناک عذاب ہو گا وہ عام جھوٹ کی طرح نہیں ہے ان کے اس جھوٹ سے مراد اعتقادی جھوٹ ہے اور اس کا عذاب سخت تر ہے۔
( وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَتُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ )
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔
فساد فی الارض
انسان کی گمراہی اگر اس کی ذات تک محدود ہو تو اسے فساد فی الارض سے تعبیر نہیں کیا جاتا جیسے کفر اور شرک وغیرہ فساد فی الارض نہیں ہے لیکن جب ان لوگوں سے ایسی بد اعمالیاں سر ذد ہو جن کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہو یعنی انہیں راہ راست سے ہٹا کر معصیت اور گناہ کی راہ پر طلانا مقصود ہو تو یہ فساد فی الارض ہے۔
البتہ بعض گناہ تو برا ہ راست اس عنوان کے تحت ہیں جیسے چغل خوری کرنا، ایک دوسرے کو لڑانا، فسق ظلم اور اسراف کا اظہار کرنا،انفرادی طور پر فساد ہیں لیکن جب کوئی شخص ان غلط کاموں کی طرف لوگوں کو بلا ئے اور انہیں اپنا مشن قرار دے لے یعنی کفر، معاصی نفاق اور غلط کاموں پر ڈٹ جا نا فساد ہے جیسا کہ روایت میں ہے۔
الفساد هو الکفر والعمل بالمعصیة
فساد،کفر اور معصیت کا تکرار ہے۔(۱)
لہذا تبلیغ سوء، نظام اسلام کے خلا ف بغاوت، وحی اور نبوت کا انکار، مبداء اور معاد کی صحت میں شک، لگائی بجھائی، مومنین کا استہزا ء اور تمسخر،کافروں کے منصوبوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی مدد اور لوگوں کو ایمان کے راستہ سے ہٹانا فساد فی الارض کے مصادیق ہیں۔
____________________
(۱)در منثور ج۱ ص۳۰
اصلاح کا دعوی
منافقین کے دل میں جو شک اور انکار ہے اگر یہ لوگ اسی حد تک محدود رہتے تو یہ ان کی انفرادی گمراہی تھی لیکن منافقت کے سایہ میں انہوں نے بہت سے ایسے کام انجام دئیے ہیں جن کی وجہ سے امن و عامہ خطرہ لاحق ہونے کا قوی امکان ہے اسی لیئے مومنین کو جب ان کے ناپاک منصوبوں کا علم ہوتا تھا وہ انہیں نصیحت کرتے کہ اس مفسدانہ روش کو چھوڑ دیں معارف کو درست اور صحیح سمجھنے کے لیے روشن فکر اور عقل سلیم کی ضرورت ہے۔
ان معارف کو عملی جامہ پہنانے کے لیئے صحیح اور پر خلوص عمل کی ضرورت ہے ان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں فساد کو اصلاح اور اصلاح کو فساد کا نام دیتے ہیں یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا دعوی کرتے ہیں کہ ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ ہم تو مصلح ہیں لیکن قرآن مجید حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے والوں کو منافق کے اوصاف سے گردانتا ہے۔
( أَلاَإِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِنْ لاَیَشْعُرُونَ )
آگاہ ہو جاو یہ سب مفسدین ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے ہیں۔
بے شعور مفسد
قرآن مجید اس مقام پر مومنین کو آگاہ اور ہوشیار کر رہا ہے کہ دینی معاشرے میں فساد پھیلانے والے منافقین سے آگاہ رہو اور ان کے جھوٹے اصلاح کے دعوی کو نظر انداز کر کے کہتا ہے۔
یاد رکھو کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں ان کے کردار میں اصلاح کا نام و نشان تک نہیں ہے منافقت کے غلط اثرات ان کی روح، جان،رفتار،و کردار میں ظاہر ہیں دنیا و آخرت میں گمراہی ان کا مقدر بن چکی ہے،ان میں شعور واقعی کا فقدان نمایاں طور پرظاہر ہے۔ یہ فساد پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم درست کام کر رہے ہیں یہ بے شعور مفسد ہیں ان کا اسلام کے اصولون پر قلبی اعتقاد نہیں ہے یہ لوگ نا سمجھی کی وجہ سے ان غلط کاموں کو درست سمجھتے ہیں ان کے نتائج پر غور نہیں کرتے حالانکہ ان غلط کامون کی لپیٹ میں اکثر خود بھی آجاتے ہیں۔
لیکن اگر یہ لوگ صرف اپنی منافقت پر باقی رہتے،اسالمی اسولوں کو دل وجان نہ مانتے اور صرف ان گلط کاموں کے نتائج پر غور کر لیتے تو اس مفسدانہ روش کو ضرور ترک کر دیتے لیکن اپنے نفس کو دھوکہ دینے اور اپنے فساد کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے یہ بے شعور مفسد ہیں۔
( وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلاَإِنَّهُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ وَلَکِنْ لاَیَعْلَمُونَ )
جب ان سے کہا جاتا کہ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔
دعوت ایمان
ایمان کا زبانی کلامی اظہار تو یہ منافق بھی کیا کرتے تھے لیکن چونکہ اسلامی اصولوں کو دل سے نہ مانتے تھے اس وجہ سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح ایمان لے آؤ جو صرف خدا کے لیئے ہو اس میں نفاق کی بو تک نہ ہو اور عقل و شعور کا ثبوت دیتے ہوئے ایسا ایمان لے آؤ کہ انسان کہلوانے کے حقدار بن سکو اور تمہارا کوئی عمل بھی انسانیت کے خلاف نہ ہو۔اس آیت میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ مومنین جیسا ایمان لے آؤ بلکہ کہا گیا ہے کہ عوام الناس جیسا ایمان لے آؤ کیونکہ انہیں ابھی کفر و نفاق سے نکال کر ایمان کے کم ترین درجہ کی طرف لانا مقصود ہے جبکہ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیئے تو انہین کئی مراحل طے کرنے ہوں گے بہرحال خلوص دل کے ساتھ عوام الناس جیسا ایمان لانے سے کفر نفاق کی وادی سے نکل کر مسلمان کہلوا سکیں گے۔
مومنین کی تحقیر ان کا شیوا ہے
منافق اپنے برے اعتقاد اور غلط رائے کی وجہ سے اہل ایمان کی تحقیر اور توہین کو اپنا وطیرہ سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو تو عاقل و ہوشیار سمجھتے ہیں جبکہ مومنین کو نادان سادہ لوح،اور جلد دھوکہ کھانے والے سمجھتے ہیں اور ان کے پاک دلوں کو حماقت اور بیوقوفی سے متہم کرتے ہیں۔
یعنی وہ حق طلب اور حقیقی انسان جو پیغمبر اسلام کی دعوت پر سر تسلیم خم کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی حقانیت کا مشاہدہ کر چکے ہیں ان کی نظر میں وہ نادان ہیں اور یہ عقل مند ہیں کیونکہ مسلمانون کو سیاست نہیں آتی جبکہ ہم سیاست دان ہیں ہم نے کافروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں۔
اگر مشرکین کو فتح ہوئی تب بھی ہماری فتح ہو گی اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ہم ان کے ساتھی کہلائیں گے جبکہ خالص مسلمان بیوقوف ہیں کیونکہ مشرکوں کو فتح ہوئی تو یہ نا عاقبت اندیش مسلما ن مارے جا ئیں گے اور اپنے مستقبل کو خطرہ میں ڈال بیٹھیں گے یعنی خدا پرست اور راہ حق میں جہاد کرنے والوں کو یہ نا دانی کی تہمت لگاتے ہیں۔
حقیقی بیوقوف
قرآن مجید ان کو حقیقی بیوقوف گردانتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی کمزور اور ضعیف رائے کی وجہ سے اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچان سکتے۔ان کی شناخت کا معیار حس اور مادہ ہے جس کی وجہ سے یہ گیب اور غیر محسوس چیز پر ایمان لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں حالنکہ جو توحید کے آئین سے منہ موڑ کر چند روزہ دنیاوی لذتوں میں مشغول ہو جائے اور اپنی عاقبت اور ابدی زندگی کو تباہ کر لے وہی بیوقوف ہے۔
انہیں اس وقت پتہ چلے گا جب ا بدی عذاب کا منظر ان کے سامنے ہو گا اور یہ کافروں سے بھی بد تر عذاب کا ذئقہ چکھ رہے ہوں گے۔یہ ان کی بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ یہ اپنی زندگی کے مقصد کی تعین ہی نہ کر سکے جو گروہ دیکھا اسی کا رنگ اختیار کر لیا اپنی قوت کو سازشوں اور تخریب کاری میں صرف کردیا اس کے با وجود خود کو عقلمند سمجھتے ہیں۔
ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کی عقلون پر پردہ پڑا ہو ا ہے یہ حق کو برداشت نہیں کر سکتے یہ لوگ،جاہل نادان،اور ضعیف العقیدہ ہیں،راہ راست سے منحرف ہیں،ضلالت و گمراہی پر گامزن ہیں،یہی سب کچھ ان کے حقیقی بیوقوف ہونے کا واضح ثبوت ہے۔
( وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَی شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ )
جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں جب اپنے شیطانوں سے تنہائی مین ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو فقط (انہیں ) بنا رہے تھے۔
شان نزول
ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اس کی مومنین کی ایک جماعت کے ساتھ ملاقات ہوئی پھر وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے رسول خدا کے چچا زاد، اے بنی ہاشم کے سردار،ہم بھی آپ کی طرح مومن ہیں پھر اپنے ایمان کی مدح و ثناء کرنے لگا، حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔
یا عبدالله اتق الله ولا تنافق فان المنافق شر خلق الله تعالی
اے عبد اللہ اللہ سے ڈرو اور منافقت نہ کرو کیونکہ منافق اللہ کی بد ترین مخلوق ہے۔
عبداللہ ابن ابی کہنے لگا
اے ابوالحسن ہمیں منافق نہ کہو کیونکہ ہمارا ایمان بھی آپ کے ایمان کی طرح ہے اس کے بعد عبداللہ وہاں سے چلا گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا۔
میں نے حضرت علی کو کس طرح جواب دیا ہے۔وہ سب بہت خوش ہوئے اور عبداللہ کے جواب کی تعریف کرنے لگے اس وقت خداوندعالم نے حضرت علی علیہ السلام کی تائید میں حضرت رسول خدا (ص) پراس آیت کو نازل فرمایا۔
جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لہذا یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی ایمان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ واضح طور پر بتا رہی ہے منافقین کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ عداوت کا اظہار کرنا چاہیے۔(۱) بہر حال یہ آیت منافقین کی پوری طرح تصویر کشی کرتی ہے کہ ان کی منافقت کس طرح ہے؟ دو مختلف گروہوں کے لیئے میل جول رکھنے اور تعلقات کے انداز پر روشنی ڈالتی ہے۔
مومنین کے ساتھ ملاقات کا ریاکارانہ انداز
منافق جب صاحبان ایمان سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح اللہ،رسول،آخرت اور قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں لیکن ان کا یہ سب کچھ زبانی کلامی ہوتا اگر یونہی ملاقات ہو جاتی تو اہنے ایمان کا اظہار کرنا شروع کر دیتے اور اپنی دو رنگی کی وجہ سے یہ لوگ قلبا انہیں ملنے کے مشتاق بھی نہ ہوتے اور ملاقات پر اصرار نہ کرتے تھے۔
____________________
۰۰۰ غایة المرام ۳۹۵،و منہج الصادیقین ج ۱ ص ۱۶۰ ( کچھ تبدیلی کے ساتھ )اور روح البیان ج ۱ ص ۶۲۔
یہی وجہ ہے کہ قراان مجید نے مسلمانوں کے ساتھ ان کے ملنے کو اذا لقوا سے تعبیر کیا ہے کہ جب ملاقات ہو جاتی تو ایمان کا اظہار کرنے بیٹھ جاتے اور یہ اظہار بھی صرف ظاہرا ہوتا تھا اسی وجہ سے یہاں جملہ فعلیہ استعمال ہوا ہے جو حدوث پر دلالت کرتا ہے یعنی ظاہرا تو مسلما ن ہونے کا دعوی کرتے جبکہ باطنا کفر کا اظہار کرتے تھے۔
اپنے بزرگوں سے ملاقات کا انداز
منافق جب اپنے شیطان صفت بزرگوں سے ملتے تو ان کا انداز ہی جدا ہوتا تھا اس وقت یہ اپنے شیطان صفت،مظہر کفروعناداور بیوقوف بزرگوں سے خلوت میں ملاقاتیں کرتے یعنی یہ کافر سرداروں کے ساتھ اپنے باطنی کفر کی وجہ سے خفیہ ملاقاتیں اورقلبی اعتقاد سے کہتے۔ہم آپ کے ساتھ ہیں یہاں ان کے لیئے لفظ،انا معکم،استعمال ہوتی ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور دوام وثبوت پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ دل و جان سے اس حقیقت کا اظہار کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کو تو ہم نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔
مومنین کی اہانت
خداوندعالم اس آیت میں بتا رہا ہے کہ منافق کس طرح مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور وہ ہر وقت ان کی توہین کی کوشش میں لگے رہتے تھے اور اپنے بزرگوں سے جا کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ سردار لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بھی تو ہیں اور ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ انہیں جواب میں کہتے۔
ہم تو انہیں بناتے ہیں ان کا یہ کہنا ان کے جہل نادانی اور تکبر کی علامت ہے اور جس انسان میں تکبر ہو اس کا عقل قرآنی ہدایت کو قبول کرنے سے قاصر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کسی کی تحقیر اور اہانت کو حرام قرار دیا ہے جبکہ خدا،رسول آیات الہی،اورمومنین کی ایمان کی اہانت اورتحقیر کرنا کفر ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( قُلْ أَبِاللَّـهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ )
آ پ کہہ دیجیے کہا ں (تم )اللہ، اس کی آیات اور اسکے رسول کے بارے میں مذاق اڑا رہے تھے تو امعذرت نہ کرو تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے۔(۱)
( اللهُ یَسْتَهْزِءُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ )
خداانہیں خود مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سر کشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے تا کہ یہ اندھے پن میں مبتلا رہیں۔
مو منین کی حمایت
اس ایت مجیدہ میں اللہ تعالی نے منافقین کے مقابلہ میں مو منین کی حمایت کر رہاہے کیونکہ منافقوں نے مسلمانوں کی توہین صرف دین الہی کے اختیار کرنے کی وجہ سے کی ہے لہذا انہوں نے مومنین کے متعلق جو لفظ استعمال کیا ہے اور اس میں مسلمانوں کی تحقیر اور توہین تھی اللہ تعالی نے ان کی حمایت میں اپنی طرف سے وہی الفاظ ان کی طرف پلٹا دیے ہیں اور اللہ نے ایسا کر کے انہیں سزادی ہے جیسا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ارشادفرماتے ہیں۔
ان الله لا یستهزی بهم الکن یجاز بهم جزاء الا ستهزاء
اللہ انکا از خود مذاق نہیں اڑاتا بلکہ ان کے مذاق اڑانے کی سزا دیتا ہے۔
____________________
(۱)سورہ توبہ آیت ۶۵،۶۶
منافقین کے عمل سزا بھی تمسخر اور استہزاء کے مشابہ ہیں یعنی ان کا ظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ان کا باطن کفار کے ساتھ ہے۔
یہ کفار سے کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا ہے لہذا سزا کے وقت اللہ تعالی بھی ان کے ساتھ ان جیسا معاملہ کر رہا ہے اس دنیا میں ان کے لئے مسلمانوں کے احکام جاری فرمائے ہیں یعنی ان کے زبانی کلامی یہ کہنے سے کہ ہم مومن ہیں تمام احکام شرعیہ ان کے لئے جاری فرمائے ہیں۔
دنیا میں نماز روزہ حج زکواة جیسے تمام احکام پر عمل کرنا ان کے لئے ضروری قرار دیا ہے مگر چونکہ باطن میں یہ کافر تھے اس لئے آخرت میں انہیں کافروں سے بھی سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔(۱)
منافقون کے لیئے مومنین کا استہزاء اور تمسخر کوئی حقیقی اور تکوینی اثر نہیں رکھتا بلکہ انکا استہزاء محض اعتباری ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی حمائت کرتے ہوئے اللہ کا استہزاء اور تمسخر سزا کے عنوان سے ہے اس کا تکوینی اور واقعی اثر مسلم ہے۔
اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور عقلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے ان کا ہر عمل بیکار اور فضول ہے اس کے لیئے کوئی جزا نہیں ہے قیامت والے دن میزان پر ان کے اعمال کی کوئی قدروقیمت نہ ہو گی بلکہ ان کے اعمال کے لیئے میزان کی ضرورت بھی نہ ہو گی جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔
( فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ) ۔(۲)
ہم قیامت والے دن ان کیلئے کوئی میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے۔
آپ کہہ دیجیے کہا ں (تم )اللہ، اس کی آیات اور اسکے رسول کے بارے میں مذاق اڑا رہے تھے تو امعذرت نہ کرو تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے۔
____________________
(۱)منہج الصادقین ج۱ ص۱۶۲(۲)کھف آیت ۱۰۵۔
مومنین کے ساتھ استہزاء کرنے پر اللہ تعالی منافقوں کو ایک سزا یہ دیتا ہے کہ یہ ہمیشہ سرکشی اور تباہی کی تا ریکیوں میں ڈوبے رہیں گے جس کی وجہ سے صراط مستقیم کو نہیں پا سکیں گے کیونکہ یہ آیات بینہ اور انبیاء و آئمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں تدبر و تفکر نہیں کرتے ان کے متعلق قلبی اعتقاد نہیں رکھتے اسی وجہ سے ان کا حق سے ہٹنا اور حق کو صحیح طور پر تسلیم نہ کرنا ان کی باطنی عناد اور سوء اختیار کی وجہ سے ہے۔جبکہ اللہ تعالی اپنی طرف سے کفر اور سرکشی میں اضافہ کو پسند نہیں کرتا یہ طغیانی اور سرکشی خود ان کی طرف سے ہے اللہ تعالی ان کی عمر کی رسی دراز کر دیتا ہے انہیں بہت مہلت دیتا ہے لیکن ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ان سے معارف الہی کو سمجھنے کی توفیق سلب کر لیتا ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے کھودے ہوئے ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔
جو لطف اور نور وقلب مومنین کے شامل حال ہے وہ انہیں میسر نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں میں نفاق اور کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے ضلالت و گمراہی زیادہ ہو گئی ہے لہذا اللہ تعالی کی اطاعت و عبادت کی محرک نعمتیں بھی ان کے لیئے مزید سرکشی اور ضلالت کا موجب بن گئی ہیں اور خداتعالی کی طرف سے ڈھیل نے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جس طرح کافر اپنی خطاؤں کے گرداب میں غرق ہیں۔
اسی طرح منافق بھی اپنی ضلالت اور گمراہی و سرکشی کی وجہ سے اس ڈھیل سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور اسی گرداب میں غرق ہو گئے ہیں اور اپنے اندھے پن کی وجہ سے اپنی زندگی اچھائی برائی کی تمیز کے بغیر گزار دیتے ہیں۔
( أُوْلَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوْا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ )
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔
منافقین کا انجام
الف ضلالت و گمراہی کے خریدار
گزشتہ آیات میں منافقین کے مفسد اور باطل اوصاف کو بیان کیا گیا انہون نے متاع گراں،چشمہ ہدایت سے سیراب ہونے کی بجائے ضلالت و گمراہی کو ترجیح دی ہے لیکن اتنے بے شعور ہیں کہ مفسد اور مخرب کام کو اصلاح کا نام دینے لگے مومنین کو سادہ لوح اور نادان سمجھ بیٹھے حالانکہ یہ خود فسادی اور دھوکہ با ز اور نادان لوگ ہیں انہوں نے ہدایت پر جلالت کو ترجیح دی ہے۔ جبکہ ان کے پاس امکان تھا کہ ہدایت سے بلا مانع فائدہ اٹھاتے کیونکہ یہ لوگ وحی کے خوشگوار چشمے کے کنارے پر تھے اس ماحول میں صدق وصفا اور ایمان سے لبریز ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے اس ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید کر لیا ہے جس سے سب فائدہ اٹھا سکتے تھے۔
لیکن صرف متقین نے اس سے فائدہ اٹھایا جبکہ کافر اور منافق کے اختیارمیں بھی تھا لیکن وہ اپنے سوء اختیار کی وجہ سے ضلالت اور گمراہی کے خریددار بنے جیسا کہ خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے۔
( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً )
یقینا ہم نے اسے راستہ کی ہدایت دے دی ہے چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے۔(۱)
____________________
(۱)سورہ دھر آیت ۳۔
(ب)نقصان دہ تجارت
قرآن مجید ہدایت فطری،فہم کی قدرت اور انسانی زندگی اور اس کے کام کرنے کی طاقت کو تجارت کا سرمایہ شمار کرتا ہے اگر یہ سرمایا صحیح عقائد اور معارف الہی کے حصول اور عمل صالح کی راہ میں استعمال ہو تو یہ نفع بخش تجارت ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( إِنَّ اللَّـهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ )
بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔(۲)
لیکن اگر یہ سرمایہ ضلالت اور گمراہی کی راہ میں خرچ کیا ہو تو یہ نقصان دہ تجارت ہے جیسا کہ اسی آیت میں اللہ تعالی منافقوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ انہوں نے فطرت،عقل اور ہدایت کو فروخت کر کے ضلالت و گمراہی کو خرید کر لیا ہے یہ نادان تاجر ہیں تاریک بیابان میں ہدایت کے چراغ کے بغیر حیران و سرگردان ہیں۔
انہیں دنیا نے فائدہ نہیں پہنچایا ہے کیونکہ ہمیشہ فائدہ سرمایا سے زیادہ ہو اکرتا ہے اور ہدایت الہی کی بدولت انہیں جو اجتماعی اور انفرادی مفادات حاصل ہو سکتے تھے وہ بھی انہیں میسر نہ آسکے اور ان مفادات کے مساوی بھی انہیں کچھ نہ مل سکا اور اس ہدایت سے بھی محروم رہے جو آخروی نجات کی ذمہ دار تھی لہذا ان کی یہ تجارت انہیں فائدہ نہ دے سکی بلکہ یہ ان کی نقصان دہ تجارت ہے لہذا انہیں قیامت والے دن دردناک عذاب دیا جائے گا۔
( مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَائَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لاَیُبْصِرُونَ )
ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ سلگائی مگر جب اس آگ سے ہر طرف ورشنی پھیل گئی تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو انھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔
__________________
(۲) سورہ توبہ آیت ۱۱۱
خصوصیات
سب سے پہلی مثال :
یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی مثال ہے جس کے ذریعے منافقین کی حالت کو اشکار اور واضح کیا گیا ہے۔
ضرب المثل کی اہمیت
گذشتہ آیات میں منافقوں کی اصلیت بیان کی جا چکی ہے اب ان کی حقیقت کو زیادہ واضح انداز میں بیان کرنے کے لئے ضرب المثل کے ساتھ ان کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ہمیشہ جب کوئی چیز زیادہ مشکل ہو اور اس کا سمجھنا آسان نہ ہو تو اسے مثال کے ذریعہ بیان کیا جاتا یعنی ضرب المثل ایسا نور جس کی عظمت کسی سے مخفی پوشیدہ نہیں ہے یہ حقائق سے اس طرح پردے دور کرتی ہے کہ غائب بھی حاضر کی طرح معلوم ہوتا ہے۔
عظیم علمی معارف کو مثال کی شکل میں بیان کرنا سابقہ کتابوں کا شیوا بھی رہا ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاة وَمَثَلُهُمْ فِي الاِنْجِیْلِ )
ان کی یہ مثال تورات اور انجیل میں بھی ہیں۔(۱) سورہ فتح آیت ۲۹
مثال کی خاصیت یہ ہے کہ علمی معارف کو اس سطح پر لے آتی ہے جس کی وجہ سے تمام افراد اسے سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے عظیم اورعلمی مطالب کے نقطہ عروج تک سب کی دسترس ہوتی ہے اور قرآن مجید کا بھی مثال بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ عام آدمی بھی حقائق تک پہنچ سکیں اور ان کے لئے علمی مطالب کی معرفت کا حصول آسان اور سادہ ہو اور بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔
___________________
(۱)بحارالانوار ج۲۴ ص۲۶۸
تاریک زندگی
قرآن مجید نے ایک سادہ اور عام فہم مثال کے ذریعے یہ بیان کیا ہے کہ منافقین کی زندگی تاریک ہے ان کا مستقبل بھی تاریک ہے اور اندھیری رات میں،بیا باں میں آگ سلگائی ہے تاکہ اسے راہ سجھائی دے سکے یعنی انہوں نے پیغمبر اسلام(ص) کے پاس آکراظہار اسلام کیا ہے جس کی وجہ سے اس نور حقیقت کے قریب آگئے ہیں جو دین ودنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔
انہوں نے ایک آگ سلگائی جس سے فائدہ اٹھانا ان کے لئے آسان تھا۔اس آگ کی گرد وپیش میں پھیل گئی سینکڑوں لوگ اس نور سے منور ہوئے اور دنیا اورآخرت کی کامیابی پر فائز ہوئے لیکن منافقوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اللہ نے اس شعلہ کو خاموش کر دیا اور انہیں اس تاریکی میں تنہا چھوڑ دیا ان کی زندگی تا ریک سے تاریک تر ہو گئی اس کے سوء احثار کی وجہ سے توفیقات الہی سلب ہو گئیں اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا اور تاریکی ان کامقدر بن گئی ہے۔
نور رسالت وامامت سے محروم
منافقین کی تاریکی اور گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نور رسالت اور نور امامت سے محروم ہیں کیونکہ اس کائنات میں حضرت محمد وآل محمد علیہم السلام کے وجود سے نور اور روشنی ہے جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
اضاء ت الارض بنور محمد کما تضئیالشمس فضرب الله مثل محمد الشمس مثل الوصی القمر
خدا وند عالم نے روئے زمین کو آفتاب کی طرح محمد(ص) کے نور سے روشنی بخشی ہے حضرت محمد (ص) کو آفتاب اور ان کے وصی ( علی) کوچاند سے تشبیہ دی ہے۔( نورالثقلین ج ۱ ص ۳۶)
منافقین حضرت محمد مصطفی (ص) کے دار فانی کی طرف کوچ کرنے کے بعد امامت کے نور سے فیض حاصل نہ کیا یہ لوگ آنحضرت (ص)کے زمانہ میں بھی تاریک زندگی بسر کر رہے تھے اور حضرت (ص) کے بعد بھی اہل بیت کے نور امامت سے روشنی نہ لے سکے اور ظلمت و تاریکی میں ڈوبے رہے۔
جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
قبض محمد مظهرت الظلم فلم یبصروا فضل اهل بیته ۔
حضرت محمد (ص) کی وفات کے بعد تاریکی چھا گئی تب بھی ان لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام کے فضل سے بصیرت حاصل نہ کی۔
( صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَیَرْجِعُونَ )
وہ بہرے،گونگے اور اندھے ہیں اور اب گمراہی سے پلٹ کر آنے والے نہیں۔
بد ترین مخلوق
آنکھ،کان زبان اور دوسرے ادراک کرنے والے حواس انسان کے لئے بہت عظیم سرمایہ ہیں انہی کے ذریعے انسان علمی اور عملی سعادت حاصل کرتا ہے لیکن منافقین نے حق سے رو گردانی کر کے اس عظیم سرمایہ کو کھو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اس بد ترین مخلوق کی گونگے بہرے اور اندھے کے عنوان سے پہچان کرورہاہے یہ لوگ کلا م حق کو نہیں سنتے اسے زبان پر نہیں لاتے ان کے معانی اور مفاہیم میں غور وفکر کرنے کی زحمت نہیں کرتے یہ اللہ،رسول،آئمہ اطہار معجزات اور اسلامی اصولوں کو نہیں مانتے۔
یعنی یہ اوامر الہیہ،حجج بنیہ اور واضح دلائل میں تفکر نہیں کرتے،خدا نے انہیں جو فہم کی قوت عطا ء فرنائی ہے یہ عناد اور حق دشمنی میں استعمال نہیں کر سکتے جیسا کہ خدا وندعالم فرماتا ہے
( لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ) ( اعراف آیت ۱۷۹)
ان کے پاس دل تو ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں،ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں ان کے کان ہیں مگر اس سے سنتے نہیں ہیں۔
یعنی وہ اس معنی میں بہرے نہیں ہیں کہ ان میں سننے کی طاقت نہیں ہے بلکہ وہ ان کانوں سے صدائے حق سننے کا کام نہیں لیتے اس لئے وہ بہرے ہیں ان کی زبانیں ہیں مگر تعصب،عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کلمہ حق کے ساتھ گویا نہیں ہوتیں اس عنوان سے یہ گونگے ہیں،ان کے دیکھنے والی آنکھیں بھی ہیں لیکن ان سے آیات بینات کو نہیں دیکھتے تعصب کی وجہ سے انہیں جلوہ حق نظر نہیں آتا اس لحاظ سے یہ اندھے ہیں۔
یعنی یہ لوگ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کا ایمان کی طرف پلٹنا ممکن نہیں رہا کیونکہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا تھا لہذا ضلالت نفاق سے یقینی ہدایت کی طرف ان کا لوٹنا محال ہے انہوں نے معرفت الہی جیسا اساسی سرمایا اپنے ہاتھ سے دے دیا ہے لہذا اب ان کا ہدایت کی طرف لوٹنے کا راستہ بند ہو گیا ہے اور یہ کائنات کی بد ترین مخلوق کہلوانے کے حقیقی حقدار ہیں۔
( أَوْ کَصَیِّبٍ مِنْ السَّمَاءِ فِیهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُحِیطٌ بِالْکَافِرِینَ ) ( ۱۹)
یا (ان کی مثال) آسمان کی اس بارش کی ہے کہ جس میں تاریکیاں اور گرج چمک ہو موت کے ڈر سے اس کی کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔
خوف و ہراس پر مشتمل زندگی
خداوندعالم اس آیة مجیدہ میں منافقین کی زندگی کی اس طرح تصویر کشی کر رہا ہے کہ ان کی پوری زندگی خوف و ہراس پر مشتمل ہے یہ لوگ انتہائی وحشت اور سرگردانی میں مبتلا ہیں۔
ان کی مثال ایسے مسافر کی مانند ہے جس پر گرج چمک اور بجلیوں کی کڑک کے ساتھ سخت بارش برس رہی ہے بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اتنی وحشت ناک اور مہیب ہے کانوں کے پردے چاک کیے دیتی ہے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونسے ہوئے ہیں کہیں اس خطرناک آواز سے ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔
اس وقت ان کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے وسیع اور تاریک بیابان میں حیران و سرگردان ہیں تاریکی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ان پر عجیب قسم کا خوف و ہراس حاوی ہے اسلام کے غلبہ سے ان کی دنیا سیاہ ہو گئی ہے اس خطرناک زندگی میں ان کا دل دھلا جا رہا ہے۔اسلامی فتوحات کی وجہ سے ہلاکت سامنے نظر آرہی ہے دل لرز رہے ہیں اس کے متعلق کچھ نہیں سننا چا ہتے اس لیئے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تا کہ حق کو نہ سن سکیں اور ہلاکت سے بچ جائیں لیکن اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے اور ان کے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔
عذاب خدا کا احاطہ
خداوندمتعال اس آیة مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا ان پر مکمل احاطہ ہے یہ لوگ کسی صورت مین بھی میرے عذاب سے نہ بچ سکیں گے۔اس مقام پر ان الفاظ میں ارشاد فرمارہا ہے کہ میرا کافروں پر مکمل احاطہ ہے یعنی ہر وہ شخص جو قلبا اسلامی اصولوں کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں کافر ہے اب ایک شخص زبانی کلامی تو اسلامی عقائد کا اظہار کرتا ہے اور باطن میں اس کا نکار کرتا ہے تو یہ باطنی کفر ہے۔
خداوندعالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کافر خواہ اپنے کفر کو ظاہر کرتا ہو یا کفر اس کے دل میں ہو اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہو وہ عذاب الہی سے ہرگز نہیں بچ سکتا میرا عذاب اس پر محیط ہے اور وہ اس سے نہیں بچ سکتے۔
( یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ) ( ۲۰)
قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو خیرہ کردے جب بھی بجلی چمکتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اور جب اندھیر ا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ان کی سماعت وبصارت کو ختم کردیتا بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
مضطرب زندگی
خداوندعالم منافقین کی مضطرب اور مردد زندگی کو بیان کر رہا ہے جب بجلی چمکتی ہے تو یہ چند قدم چل لیتے ہیں لیکن جونہی اندھیرا چھا جاتا ہے اور تا ریکی مسلط ہو جاتی ہے تو یہ اپنی جگہ پر رک جاتے ہیں۔
یعنی جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو فتح نصیب ہو رہی ہے تو کچھ دیر کے لئے انہیں اسلام بھلا معلوم ہو تا ہے اس وقت انہیں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں اسلام کے نور کی روشنی میں چلنا چاہیے اور مسلمانوں سے تعلقات استوار رکھنے چاہیے لیکن اگر اتفاق سے فتح کامرانی کا سلسلہ رک جائے اور مسلمانوں کو وقتی شکست اور زحمت کا سامنا کرنا پڑے تو فورا ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ یہ متحیر ومضطرب و مردد، ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ صرف دنیاوی مفاد کے تحفظ میں ہیں یہ لوگ دل سے اسلام کی حقانیت پر غور نہیں کرتے اسی وجہ سے مضطرب ہیں۔
قرآن مجید ان کی کیفیت و حالت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ جب روشنی دیکھتے ہیں تو چل پڑتے ہیں اور جب تاریکی ہو جاتی ہے یعنی عارضی طور پر فتح کا سلسلہ رک جاتا ہے تو بد گمان ہو جاتا ہے منافقین میں حق طلبی کا جذبہ نہیں ہے دین اسلام کی کامیابیوں سے انہیں تکلیف ہوتی ہے،جس کے نتیجے میں ان فتوحات کو نظر بھر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے لہذا قریب ہے کہ یہ چمک ان کی نگاہوں کو خیرہ کردے۔
انتخاب ہدایت کی مہلت
خدا وند عالم نے سماعت اور بصارت جیسی نعمت ہدایت اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے عنایت فرمائی ہے لیکن منافقین نے کفران نعمت کرتے ہوئے ان نعمتوں سے استفادہ نہ کیا انہوں نے حقائق دیکھنے کی بجائے اپنی آنکھیں بند رکھیں،حق سننے کی بجائے اپنے کانوں میں انگکیاں ٹھونس لیں لہذا ان کے آنکھ اور کان اس قابل نہ تھے کہ ان کے پاس رہیں لیکن اللہ تعالی نے ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں سماعت اور بصارت کی نعمت سے مکمل طور پر محروم نہیں کیا۔ خدا چاہتا تو ان کی یہ صلاحیتیوں کو سلب کر لیتا اس نے ان صلاحیتوں کو سلب نہیں کیا اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا تا کہ ہدایت کے انتخاب میں انہیں مزید مہلت دے اگر کوئی شخص قلبی اعتقاد کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو قبول کر لے،اس کے پاس مکمل مہلت ہے لیکن انہوں نے سوء اختیار کی وجہ سے حق کی راہ کو طھوڑ دیا اورضلالت وگمراہی کی راہ مسافر بنے ہدایت کے انتخاب کی مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے وہ چاہتا تو شروع سے ہی یہ نعمتیں سلب کر لیتا۔
( یَاأَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ) ( ۲۱)
اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا شاید تم متقی بن جاؤ۔
خصوصیات
اس آیت کی دو اہم خصوصیات ہیں جو کسی اور آیت میں نہیں ہیں۔
پہلا خطاب
اس آیت میں یا ایھا الناس سے انسانوں کو پکارا گیا ہے۔قرآن مجید کا یہ سب سے پہلا خطاب ہے یہ پہلا مقام ہے جہاں خداوندعالم نے کسی واسطہ کے بغیر فرمایا ہے۔
اے لوگو ! اس خطاب انسان کو عزت و عظمت دی گئی ہے اور انسان کو اس سے تسکین ملی ہے جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
لذة ما فی النداء ازال تعجب العبادة والعناء ۔
ندا الہی میں خطاب کی ایسی لذت ہے جو عبادت کی تکلیف اور تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔
خداوند عالم انسان پر کسی واسطہ کے بغیر لطف کرتا ہے لیکن انسان اپنی غفلت،جہالت اور سواختیار کی وجہ سے اس رابطہ کو منقطع کر بیٹھتا ہے اور لطف الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔حالانکہ یا ایھا الناس اس بات کی علامت ہے کہ یہ عبد اور معبود کے درمیان نہ ٹوٹنے والا رابطہ ہے۔
پہلا فرمان الہی
قرآن مجید نے سب سے پہلا فرمان الہی یہ جاری کیا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو اس سے پہلے کوئی فرمان الہی صادر نہیں ہوا۔
دعوت عمومی
گزشتہ آیات میں اس نقطہ کو بیان کیا گیا تھا قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور قرآن مجید نے تین گروہوں متقین کافرین اور منافقین کے اوصاف اور مقام کو بیان کیا کہ متقین ہدایت الہی سے نوازے گئے ہیں اور قرآن ان کا رہنما ہے جبکہ کافروں کے دلوں پر جہل و نادانی کی مہر لگا دی گئی ہے اور منافقین کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔
اس آیت میں خداوندعالم نے ایک جامع اور عمومی خطاب کے ساتھ بتایا ہے کہ قرآنی ہدایت کسی ایک گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کی دعوت عام ہے اور یہ سب انسانوں کو یگانہ خدا کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں یعنی متقین اپنی عبادت کو جاری رکھیں اور کافرین اپنے کفر کو چھوڑ کر پروردگار عالم کی بندگی اختیار کریں۔
منافقین اپنی منافقت کو چھوڑ کر اپنی عبادت میں خلوص پیدا کریں۔دعوت قرآن سب انسانوں کے لیئے ہے یہی وجہ کہ لفظ انسان،مسلم،متقی، مومن اور بنی آدم کی نسبت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ۲۴۱ مرتبہ لفظ انسان استعمال ہوا ہے۔(۱)
زیر نظر پانچوں آیات میں خداوندعلام عمومی دعوت دے رہا ہے کہ یہ دعوت کسی ایک گروہ کے لیئے خاص نہیں ہے اس دعوت عمومی کے وقت لوگ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں بعض اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور بعض لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا ہے۔
عبودیت پروردگار
الف، معرفت خداوندی
قرآن مجید عبادت اور پروردگار کے ساتھ مستحکم رابطہ کو انسانی زندگی کی نجات اور سعادت ابدی قرار دیتا ہے خداوندعالم کی معرفت ہی عبادت ہے جیسا کہ حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
اول عبادة الله و اصل معرفته الله توحیده
سب سے پہلی عبادت اللہ تعالی کی معرفت ہے اور اللہ تعالی کی بہترین معرفت اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔(۲)
___________________
(۱)فرقان ج ۱ ص ۱۲۴۔۰۰۰۰(۲)نور الثقلین ج ۱ ص ۳۹۔
ب،صحیح عقیدہ
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اعبدو اربکم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ صحیح عقیدہ رکھنا چا ہیے۔
اجیبوا ربکم من حیث امرکم،ان تعقدوا ان لا اله الا الله،وحده لا شریک له ولاشبیه ولا مثله،عدل لا یجوز،جوادلا ینحل حلم لا یغطل،وان محمد اعبده و رسوله صلی الله علیه و آله الطیبین وبان آل محمد افضل آل النبین وان علیا افضل آل محمد و ان اصحاب محمدالمومنین منهم افضل الصحابه المرسلین وبان امته محمد افضل امم المرسلین ۔(۱)
اپنے پروردگار کی اس طرح اطاعت و عبادت کریں جس طرح اس نے حکم دیا ہے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معباد نہیں ہے وہ وحدہ لاشریک ہے اس کی کوئی شبیہ و مثل نہیں ہے وہ منبع عدل ہے اس کے متعلق ظلم کا تصور نہیں ہے۔وہ ایسا سخی ہے جس کے متعلق بخل کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ایسا حکیم ہے جیسے امور میں خلل نہیں ہے
اور عبادت سے مراد یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت محمد ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اس کے عبد اور رسول ہیں آل محمد تمام انبیا ء (اور ان) کی آل سے افضل ہیں۔حضرت علی (ع) حضرت محمد ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کی آل میں افضل ترین ہستی ہیں اور اصحاب حضرت محمد ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم)مومنین ہیں اور ان میں بعض صحابہ تمام انبیا ء کے اصحاب سے افضل ہیں،حضرت محمد ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم)کی امت تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ہے۔
____________________
(۱)بحارالانوار ج ۶۵ ص ۲۸۶۔
(ج) احترام اہل بیت علیہم السلام
اہلبیت اطہار علیہم السلام کا احترام کرنا عبادت ہے کا احترام کرنا عبادت جیسا کہ روایت میں ہے کہ بریدہ نے حضرت رسول (ص) سے اس کے متعلق سوال کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا :
یا بریده ان من یدخل النار ببعض علی اکثر من حصی انحذف یرمی عند الحجمرات، فایاک ان تکون منهم، فذلک قوله تبارک وتعالیٰ، اعبدوا ربکم خلقکم، اعبدوه بتعظیم محمد و علی ابن ابی طالب ۔(۱)
اے بریدہ جہنم میں اکثر لوگ بغض علی کی وجہ سے جائیں گے اور ان کی تعداد حج کے موقع پر شیطانوں کو مارے جانے والوں پتھروں سے بھی زیادہ ہوگی،پس تم ان جیسا بننے سے ڈرو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعبدوا ربکم الذی خلقکم فرمایا ہے یعنی محمد ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور علی ابن ابی طالب کی تکریم ہی عبادت ہے۔
انسان کو عبادت خداوندی بجا لانے کیلئے اس کے اوامر، نواہی کا خیال رکھنا چاہیے ولایت اہل بیت اصل عبادت ہے۔اگر کسی کو ولایت نصیب نہ ہوئی تو اسکی عبادت نہیں ہے(۲)
____________________
(۱)بحار الانوار جلد ۳۸ ص ۶۹
(۲) حضرت رسول اعظم ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے بیسوں فرامین اسی مطلب پر دلالت کرتے ہیں جیسا کے آپ کا فرمان ہے۔
من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنة
آل محمد کا بغض رکھ کر مرنے والا جنت کی بو تک نہیں سونگھ سکتا۔
اسی طرح مومنین کے ہر عمل کے قابل قبول ہونے کیلئے،حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ضروری ہے جیسا کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه و کان له مثل جبل احد ذهبا، فا نففته فی سبیل الله و مد فی عمره حتی حج الف عام علی قدمیه ثم قتل بین الصفاء و المراة مظلوم، ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحة الجنة و لم یدخلها
البتہ ولایت اہل بیت کا صحیح دعوایدار وہی جو فرائض کا تارک نہ ہو جیسا کہ حضرت امیرالمئومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
لا عبادة کادا الفرائض (۱)
فرائض کی ادائیگی جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔لہذا انسان کو ہر حال میں فرائض کا خیال رکھنا چاہیے اگر کسی مقام پر مستحب اور واجب کا ٹکراو ہوجائے تو اس وقت فرائض کو بجا لانا ضروری ہے بلکہ اس وقت مستحب کی بدولت انسان تقریب الہی بھی حاصل نہیں کر سکتا جیسا کہ مولا متقیان حضرت امیرالمئومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
لا قربته بالنوافل اذا اضرب بالفرائض ۔
ان مستحبات (نوافل)سے قرب الہی حاصل نہیں ہوسکتا جو واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کریں۔(۲)
یا علی اگر کوئی حضرت نوح کی عمر جتنی زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اس کے پاس پہاڑ احد جتنا سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دے دے اور اس کی زندگی اتنی طویل ہو کہ وہ ایک ہزار پیدل چل کر حج کرے حالت میں قتل ہو جائے لیکن یا علی اگر وہ تیری ولایت و محبت کا قائل نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا چہ جائیکہ وہ جنت میں داخل ہو۔
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت ۱۱۳۔(۲)نہج البلاغہ حکمت ۳۹۔
خالق اولین و آخرین کی عبادت
ہمیں اس پروردگار عالم کی عبادت کرنا چاہیے جو ہمیں اپنی کامل قدرت اور حکمت کے ساتھ عدم سے وجود میں لایا ہے یہ خدا کی قدرت،حکمت اور رحمت کی نشانی ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کو توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ تم ذرا غور کرو تو یہی تمہارا حقیقی رب ہے اس نے تمہیں بھی خلق کیا ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباؤ اجداد کا بھی وہی خالق ہے بلکہ پوری کائنات خالق وہی ہے اس ذات کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے لہذاعبادت بھی صرف اسی کیساتھ مختص ہے، تم اپنے خود ساختہ خداؤں کو پوجنا چھوڑ دو کسی چیز ہر بھی قادر نہیں ہیں۔اگر تم اپنے اور اباؤ اجداد کی خلقت پر غور کرو اور لا تعداد نعمتوں کے متعلق فکر کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ سب اس ذات کی رحمت ہے جسکا ولم و قدرت لامتناہی ہے اس وقت یقینا تم اسے ہر لحاظ سے یکتا مانو گئے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کا نہیں سوچو گئے۔
فلسفہ عبادت تقویٰ ہے
تقویٰ ایک نفسانی ملکہ، یہ اعمال صالحہ کی مکمل ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے اسی وجہ سے تقویٰ کو عبادت کا فلسفہ کر دیا ہے انسان عبادت کے ذریعے تقویٰ کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اور تقویٰ چاہیے والی کی صف میں اپنا ستمار کروا سکتا ہے،عبادت ہی موجد تقویٰ ہے۔ اگر عبادت کرنے کے باوجود بھی انسان میں تقویٰ پیدا نہ ہوسکے تو وہ عبادت نہیں ہے کیونکہ اس کائنات کی خلقت و افرنیش کا مقصد انسانیت کی تکمیل ہے جبکہ انسان کی خلقت عبادت کیلئے ہے اور عبادت کا اصلی ہدف تقویٰ ہے لہذا ہم خدائی دستورات اور فرامین کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہم پرہیز گار کہلواسکتے البتہ ہمیں اپنی عبادت میں مفرور بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غرور اور ریا ہمیں تقویٰ سے بہت دور لیجاتی ہے۔
( الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَکُمْ فَلاَتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) ( ۲۲)
جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لئے زمین سے پھل نکالے پس تم کسی کو اس کا ہمسر نہ بناؤ حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔
آفرینش کائنات انسان کیلئے ہے۔
یہ آیت گذشتہ آیت کا تتمہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس پوری کائنات کی خلقت تیرے لئے ہے تجھے متعدد نعمتوں سے نوزا گیا ہے۔
اس آیت میں بیان کی جانے والی ہر نعمت کئی دوسری نعمتوں کا سرچشمہ ہے زمین کے ساتھ اتنی نعمتیں موجود ہیں جن کا احصی ممکن نہیں ہے اس طرح آسمانی نعمتوں کا شمار انسانی طاقت سے باہر ہے یہ سب کچھ انسان کے لیئے بنایا گیا ہے لہذا اسے خدا حقیقی کی بندگی کرنا چاہیے عبادت میں خلوص پیدا کرنا چاہیے ان سب نعمتوں کا موجود ہونا اللہ کی حقیقی معرفت کا راستہ ہے۔
اللہ کی ذات واحد ویکتا ہے انسان کو خدا کی آیات آفاقی میں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ اسے یہ معلوم ہوسکے کہخدا نے اس پوری کائنات کی افرینش اس کے لیئے کیوں فرمائی ہے جب وہ اس میں غور کرے گا تو اسے معلوم ہو گا کہ وہی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، وہ و احد و یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
نعمت زمین
خداوندعالم نے اس آیت مجیدہ میں اپنی کئی نعمتوں کو بیان کیا ہے انسان ان نعمتوں کے متعلق غور کرے کہ خدا نے کس طرح زمین کو بچھونا قرار دیا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے بچھونا کس ذات نے قرار دیا ہے اس طرح آسمان کو ہمارے لیئے چھت قرار دینے والی ذات بھی وہی ہے، پوری کائنات کا خالق بھی وہی ہے اس نے ہر چیز کو ہماری طبیعت کے مطابق بنایا ہے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاسکیں۔
اس آیت مجیدہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
جعلها ملائمه لطباعکم موافقته لاجسامکم ولم یجعلها شدید الحمی والحراره متحرتکم ولا شدیدةالبردمتحمدکم ولا شدیده طیب الرسیح متصدع ها ماتکم ولا شدیدة النتن متعطبکم ولا شدیدة اللین کالما ء فتغرقکم ولا شدیدةالصلابه متمنع علیکم فی دورکم انبیتکم و قبور موتاکم فلذا جعل الارض فراشا
خدا نے زمین کو تمہاری طبیعت اور مزاج کے مطابق خلق فرمایا ہے تمہارے جسم کی وجہ سے اسے زیادہ گرم اور جلا کر راکھ کر دینے والی نہیں بنایا کہ اس کی حرارت سے تم جل کر راکھ نہ بن جاؤ اور اسے زیادہ ٹھنڈا بھی پیدا نہیں کیا ہے کہ کہیں تم منجمد نہ ہو جاؤ۔
اسے زیادہ معطر اور خوشبودار بھی نہیں بنایا ہے کہ کہیں اس کی تیز خوشبو تمہارے دماغ کو تکلیف پہنچائے اور اسے بدبودار بھی نہیں بنایا کہ کہیں تمہاری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے اس زمین کو پانی کی طرح بھی نہیں بنایا کہیں تم غرق نہ ہوجاؤ اور اسے اس قدر سخت بھی نہیں بنایا تاکہ تم گھر نہ بنا سکو مردوں کو دفن نہ کر سکو لہذا خدا نے تمہارے لیئے اس زمین کو ایک بچھونا بنایا ہے۔
نعمت آسمان
خداوندعالم نے انسانوں کو آسمان جیسی بہت عظیم نعمت سے نوازا ہے یہ بظاہر تو ایک نعمت ہے لیکن یہ بھی زمین کی طرح کئی نعمتوں کا سرچشمہ ہے خداوندعالم نے اسے ہمارے سروں پر چھت بنایا ہے جیسا کہ خداوندعالم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔۔
( وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا )
ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔
ہمیں آسمان کے ساتھ گوناگوں نعمتیں میسر آتی ہیں،حتی کہ اس کا آبی رنگ ہونا بھی ایک نعمت ہے جیسا کہ حضرت امام جعفر صاق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
اے مفضل آسمان کے رنگ میں غور وفکر کرو خدا نے اسے آبی رنگ میں پیدا کیا ہے یہ رنگ انسانی آنکھ کے لیئے بہت مفید ہے اس کی طرف دیکھنا بینائی کو تقویت پہنچاتا ہے۔
آسمان کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ااسمان سے بارش برسنا ہے اس کے فوائد کا احصی ناممکن ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام بارش کے آسمان سے نازل ہونے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔
یعنی المطر ینزله من اعلی لیبلغ قلل جبالکم و تلالکم وهضالکم و اوهادکم ثم فرقه زذاذا و وابلا و هطلا لتنشفه ارضوکم و لم یجعل ذلک المطر نازلا علیکم قطعة واحدة فیفسد ارضیکم و اشجارکم و زروعکم و ثمارکم
خداوندعالم بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے تاکہ پہاڑوں کی تمام،چوٹیوں ٹیلوں،گڑہوں اور تمام بلند مقامات پر پہنچ جائے یہ بارش کبھی تو نرم اور کبھی سخت دانوں کی شکل میں اور کبھی قطرات کی شکل میں برستی ہے تا کہ پوری طرح زمین میں جذب ہو جائے اور زمین اس سے سیراب ہو جائے۔
اسے سیلاب کی صورت میں نہیں بھیجاکہیں زمینوں درختوں،کھیتوں،اور تمہارے پھلوں کو بہا کر ویران نہ کردیاس بارش کی برکت سے قسم قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ سب انسانوں کی روزی بنتی ہیں یعنی ہمیں اس خدا کی وحدانیت کی طرف غور کرنا چاہیے جس نے بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگوں کے میوے انسان کے لیئے پیدا کیے ہیں۔(۱)
____________________
(۱)نور الثقلین ج ۱ ص ۴۱۔
شرک کی نفی
خداوندعالم انسانوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ تم عقیدہ توحید اور عبادت میں خلوص پیدا کرو کسی کو اس وحدہ لا شریک زات کا شریک نہ بناؤ سرف اسی کی عبادت کرو جو تمہارا خالق اور رازق ہے تمہاری عبادت تب عبادت ہے جب اس میں شرک نہیں ہے۔
عبادت میں جتنا خلوص زیادہ ہو گا عبادت کا انتہائی درجہ بلند ہو گا اور خلوص کا بہترین درجہ یہی ہے کہ عبادت کرنے والے کے دل میں خدا کے علاوہ کچھ نہ ہو جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
القلب السلیم الذی یلقی ربه، لیس فیه احد سواه
قلب سلیم وہ ہے کہ یا دالہی کے وقت اللہ تعالی کے علاوہ کسی کا تصور تک نہ ہو۔(۱)
تورات،زبور اور دوسرے صحیفوں میں بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ خدا کی کوئیمثل نہیں ہے حالانکہ تحت الشعور میں تم جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ نعمتیں کوئی بھی نہیں دے سکتا صرف اور صرف وہی ذات ہی زمین و آسمان کی خالق ہے جیسا کہ قرآن فرما رہا ہے۔
( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ )
اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ یقینا اللہ نے پیدا کیا ہے۔
لہذا عبادت کے وقت بھی صرف اسی اللہ کے سامنے جھکو اس میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ صرف وصرف وہی ذات لائق عبادت ہے۔
_____________________
(۱)بحار الانوار ج ۶۷ ص ۲۳۹۔
( وَإِنْ کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَائَکُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ )
اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جسیے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسا ایک سورہ ہی لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں ان سب کو (بھی ) بلا لو۔
گزشتہ آیات کے ساتھ ربط
سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا گیا تھا کہ ذلک الکتاب لا ریب فیہ یعنی اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے متعلق کسی نے شک بھی نہیں کیا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی واضح کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔
منافقین کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ یہ لوگ شک و تردید کی بیماری مین مبتلا ہیں اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اس میں کسی قسم کا شک ہے تو اس جیسا ایک سورہ ہی لے آؤ۔
اسی طرح چوتھی آیت میں مومنین کی نشانی ہی یہ بتائی گئی ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں اسی طرح ۲۱ ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کریں یہ کتاب ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح عبادت بجا لانی ہے جو شرک جیسے گناہ سے پاک ہو اور اس سے پہلے والی آیت میں اپنی ایک نعمت آسمان سے پانی نازل ہونا بیان کیا ہے۔
جس طرح آسما ن سے پانی نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری روزی کا سامان ہوتا ہے اور ہمیں جسمانی طور پر غذا میسر ہوتی ہے اور اسی کے دم سے ہم زندہ ہیں بالکل اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی ایک نعمت قرآن مجید ہے یہ ہماری روحانی غذا کے عنوان سے ہے۔ اسی قرآن سے قومیں زندہ ہیں اور ان کی روح کو غذا میسر آتی ہے یعنی ہماری جسمانی پرورش آسمان کا پانی کرتا ہے اور ہمیں صحت و سلامتی حاصل ہوتی ہے جبکہ ہماری روحانی پرورش قرآن مجید کرتا ہے ا س کی وجہ سے ہماری روح کی سلامتی اور مقصد پیدائش کی تکمیل ہوتی ہے۔( ۱)
قرآن مجید کا تعارف
خداوندمتعال اپنی کتاب کا تعارف اس انداز سے کرا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی اس کتاب میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ تعالی نے اسے آسمان سے پیغمبر اسلام پر نازل فرمایا ہے یہ سب لوگوں کی ہدایت کا سر چشمہ ہے،ہمیں راہنمائی کر رہی ہے کہ ہم نے کس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس میں شک کرنے والا پوری کائنات کو اپنی مدد کے لیئے بلا لے تب بھی اس کا مثل نہیں لا سکتا ہے اور وہ کافروں کے لیئے بنائی گئی جہنم کا ایندھن بنے گا۔
____________________
( ۱) جیسے خداوندعالم کا فرمان ہے
( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ )
ب عبودیت کا مقام۔
قرآن مجید میں لفظ عبد جب مطلق استعمال ہو ا ہے اور یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ خاص ہے کیونکہ دوسرے انبیاء کے لئے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں ساتھ پہلے یا بعد میں نبی کا نام یا صفت بھی ساتھ بیان ہوتی ہے اس مقام پر بھی چونکہ لفظ عبد مطلق ہے(۱) یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ خاص ہے۔
جس طرح خد ا کے علاوہ کوئی ذات بھی مطلق حر نہیں ہے اسی طرح آپ (ص) کے علاوہ کوئی بھی مطلق عبد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم جیسے ابو الانبیاء بھی آپ(ص) کے پرچم کے سایہ میں ہو ں گے جیسا کے آپ کا ارشاد گرامی ہے۔
آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیامة
آدم اور اسکے بعد آنے والے سب لو گ قیامت والے دن میرے سایہ میں ہونگے۔
یہ مقام عبودیت اس قدر بلند ہے کہ مو لی کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فر ماتے ہیں۔
الهی کفی بی غدا ان اکون لک عبدا
اے میرے معبود میرے لئے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔(۲)
لہذا مطلق سرداری اور سیادت بھی آپ کے لئے ہے،آپ عبد خدا کے نام سے پہلے ہی سے پوری کائنات میں مشہور ومعروف تھے اسی لئے اس آیت میں بھی عبد مطلق لایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے عبد پر جو کچھ نازل کیا ہے اس میں تمہیں شک ہے تو اس جیسا ایک سورہ لے آؤ۔
____________________
(۱)کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا ۔سورہ قمر آیت نمبر ۹ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی اور انہوں نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا۔واذکر عبدنا ایوب۔سورہ ص آیت نمبر ۴۱۔ ہمارے عبد ایوب کا ذکر کرو۔
(۲)مفاتیح الجنان مناجات حضرت امیر المومنین علیہ السلام ص۲۶۶۔
قرآن کا چیلنج
الف۔قرآن مجید تمام شکوک سے پاک ہے
ریب اس شک کو کہتے ہیں جو تہمت کے ساتھ ہو،قرآن مجید ہر قسم کے ریب و شک سے پاک ہے لہذا اگر تمہں قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے اور تم رسول خدا (ص) پرتہمت لگاتے ہو کہ انہوں نے خدا پر اختراء باندھا ہے اور یہ اس کا اپنا کلام ہے تو تم بھی اس قسم کا کلام بنا لا ؤ یہ لا ریب کتاب ہے اور تم اس میں شک کرتے ہو اور اسے رسول خدا کا کلام کہتے ہو قرآن کی اس آیت میں پیغمبر اسلام کی صداقت بیان کر رہا ہے کہ لوگ کبھی تو توحید میں شک کرتے ہیں۔(۱) کبھی وحی کے بارے میں شک وگمان میں مبتلا ہوتے ہیں(۲) کبھی قیامت کو نہیں مانتے۔(۳)
____________________
( ۱)( وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ) (ابراہیم آیت نمبر ۹)
ہمیں اس بات کے بارے میں واضح شک ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ۰۰۰
( ۲)( أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي ۖ ) (ص آیت ۸)
کیاہم سب کے درمیان تنہا انہیں پر کتاب نازل ہوئی ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہماری کتاب میں شک
( ۳)( وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ )
اورشیطان کو ان پر اختیار حاصل نہ ہوگا مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتاہے اور کون شک میں مبتلا ہے (سباء آیت نمبر ۲۱)
یہ سب شکو ک و شبھات ا س لئے نہیں کہ ان میں کسی قسم کا ریب وشک ہے بلکہ یہ اس لئے شک کرتے ہیں کہ یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں ان میں غور وفکر کی قدرت نہیں رہی یہ اپنے سوء اختیار کی وجہ سے راہ راست سے دور ہیں اس لئے یہ شک کرتے ہیں کہ بلکہ یہ اندھے ہیں انہیں حق سجھائی نہیں دیتا۔(۴) حا لانکہ ان کی آنکھیں ہی اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔(۵) کیونکہ آنکھ اور کان تو ادراک کے وسائل ہیں جب قلب ہی کام نہ کر سکے تو یہ کیا کام کر سکتے ہے۔
____________________
(۴)جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
(بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ) ۔سورہ نمل آیت نمبر ۶۶۔
بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ناقص رہ گیا ہے اور یہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں بلکہ (یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ )یہ با لکل اندھے ہیں۔
(۵)(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) ۔حج آیت نمبر ۴۶۔
کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے ہیں جن سے (حق بات)سمجھنے یا اس کے کان ہوتے جن سے یہ سنتے کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں بلکہ سینے میں موجود دل ہی اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔
انہوں نے غور وفکر اور سوچنے کے چراغ گل کر دیتے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ شک وشبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور قرآن مجید جیسے واضح روشن حقائق کے متعلق شک و تردید کر بیٹھے۔کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہم بھی اس قسم کی کلام بنا سکتے ہیں۔(۱)
قرآن مجید ان لوگوں سے بر ملا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کے قرآن ہونے کے بارے میں شک ہو تو تم بھی اس جیسا کوئی سورہ ہی لے آؤ لہذا اس آیت میں اللہ تعالی ایک طرف تو قرآن مجید کے معجزہ ہو نے کو بیان کر رہاہے اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کی صداقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور میں نے اسے اپنے عبد پر نازل کیا ہے یہ اس کا کلام نہیں ہے،تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو تمہار ا شک تمہارے اندھے پن کی وجہ سے ہے۔
قرآن ہمیشہ رہنے والا ایک معجزہ ہے
معجزہ وہ غیر معمولی چیز ہے جو کسی نبی کو دعوائے نبوت یاکسی اور منصب الہی والے کو اس منصب کے ثبوت میں خدا وند عالم کی وجہ سے عطاء ہوا ہواور اس کے مقابل لانے سے ساری دنیا عاجز ہو یعنی معجزہ ان غیر معمولی آثار کا نام ہے جو ایک مدعی نبوت میں اس کے دعوی کی خصوصی دلیل بن سکیں۔
قرآن مجید ہمارے رسول کا ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے جب کہ گذشتہ انبیاء کے معجزات ایک زمانے تک محدود تھے مثلا حضرت عیسی کا پیدا ہوتے ہی گفتگوکرنا،مردوں کو زندہ کرنا،مادر ذاد اندھوں کو بینائی دینا،یا برص کے مریضوں کو تندرست کرنا،یا حضرت موسی علیہ السلام کو ید بیضاء عنایت فرمانا یہ سب کے سب ایک زماننے تک محدود ہیں۔لیکن قرآن مجید تا قیامت معجزہ ہے اور آغاز سے انجام تک معجزہ ہے یعنی جس طرح حضرت کے زمانہ میں معجزہ تھا اسی طرح آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔
_____________________
(۱) لو نشاء لقلنا مثل هذا (انفعال آیت نمبر ۳۱)
قرآن کی حقانیت یقینی ہے
خداوند عالم اس ایک معجزہ میں پوری کائنات کو چیلنج کر رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے اگر تمہیں اس کے متعلق شک ہے تو کم از کم اس جیسا ایک سورہ ہی بنا لا ؤ۔ یعنی قرآن مجید کی حقا نیت پر اس قدر یقین ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حتمی اس جیسی پوری کتاب بنا لاؤ وہ تو تم یقینا نہیں بنا سکتے،اچھا ( ۱۰) آیات ہی بنا لاؤ،اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فقط و فقط ایک سورہ بنا لاؤ یہاں ایک سورہ جو کہا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم( ۲۸۶) آیات پر مشتمل سورہ بقرہ جتنا سورہ بنالاؤ بلکہ تمہیں اختیار ہے کہ ( ۳) آیات پر مشتمل سورہ کو ثر جتنا سورہ بھی بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھاؤ۔ اگر تم قرآن مجید جیسا ایک سورہ لے آو گئے تو ہم اسے پورے قرآن کے مقابلے میں تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں۔
مخالف قرآن جھوٹے ہیں
خدا وند عالم نے عرب جیسی با حمیت اور با غیرت قوم کو للکارا کر کہا ہے کہ اگر تمہں قرآن پر شک ہے تو اس جیسا ایک سورہ ہی بنا لاؤ اگر تم اکیلے ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے مدد گار ہیں ان سب کو بھی جمع کر لو اور اجتماعی کوشش کرو سب کے سب مل کر اس قرآن جیسا ایک سورہ بنا لاؤ لیکن اگر تم سورہ نہ بنا سکے تو پھر تم جھوٹے ہو اور تمہارا خیال بھی غلط ہے۔
قرآن مجید کسی بھی انسانی طاقت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ صرف اور صرف اللہ کا نازل کر دہ کلام ہے یہ فصاحت اور بلاغت میں بلغاء کے لئے معجزہ ہے اپنی حکمت میں حکماء کے لئے معجزہ ہے اپنے علمی مباحث کے عنوان سے علماء کے لئے معجزہ ہے قانون دانوں کے لئے اجتماعی قانون گذاری کرنے کے لحاظ سے معجزہ ہے۔
غرض قرآن مجید ہر پہلو اور ہر لحاظ سے معجزہ ہے اور اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے اس میں شک و شبہ کرنے والا اگر اس کے مقابل کچھ نہیں لا سکتا تو سمجھ لے کہ میں جھوٹا ہوں اور میرا دعوی غلط ہے۔
( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ )
اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقینا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور یہ کافروں کے لئے تیارکی گئی ہے۔
الف۔ قرآن کا چیلنج لا جواب ہے
قرآن مجید نے نفسیاتی طریقہ اختیار کیا ہے اس نے تیز سے تیز اور سخت سے سخت الفاظ میں چیلنج کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی کوئی اور کتاب بنالاؤ یعنی انہیں غیرت اور حمیت دلاتی ہے تاکہ وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کو استعمال کرتے ہوئے مقابلہ کی کوشش کریں۔
وہ غیور اور باحمیت اور پر جوش عرب جو چھوٹی چھوٹی بات پر جان دینے کے لئے آمادہ ہو جا تے تھے اگر ان میں دم وخم ہوتا اور وہ قرآن کے چیلنج کا جواب دے سکتے ہوتے تو وہ ان طعنوں،سرزنشوں،اور مبارزہ طلیبوں کو سن کر ضرور اپنی فکر کی طاقتوں سے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔
لیکن وہ ناکام اور عاجز رہے انہوں نے واضح طور پر جان لیا کہ یہ انسانی طقت سے باہر ہے اور یہ خدائی کام ہے حضرت محمد (ص) نے تو اسے اپنی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا ہے مضحائے عرب کو مقابلہ کی دعوت دی وہ قرآن مجید کے چیلنج کا جواب لانے سے عاجز آگئے۔ قرآن کاچیلنج لا جواب رہا اور قیام قیامت لا جواب رہے گا کیونکہ اس کی حقانیت کا ثبوت ہمہ گیر حیثیت رکھتا ہے اسی وجہ سے یہ صرف عربوں کے لئے معجزہ نہ تھا۔
بلکہ پوری خلق کے لئے عربی ادیب عمر بن بحر حافظ کہتے ہیں۔عرب قوم کا قرآن جیسا کلام پیش نہ کر سکنا اور اس کے مقا بلے میں عاجز آجانا دنیا کے تمام غیر عرب لوگوں کے لیئے قرآن کی حقانیت کا ثبوت ہے۔
جہاں تک عرب قوم کا تعلق ہے اس نے اس قرآن کے مقابلہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کردیا تھا ۱۴۰۰ سال بعد بھی قرآن مجید اسی انداز میں اپنی مقابل دنیا کے ہر طبقہ کو پکار پکار کر مقابلہ کی دعوت دے رہا ہے اور مخالفین کو سرتوڑ کوشش کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
یہ ماننا پڑا کہ قرآن مجید کا یہ دعوی لا یا تون بمثلہ۔تا قیام قیامت سچا رہے گا یہ سچائی پر اعتماد کی انتہا ء ہے دشمنوں کے ماحول میں داعی حق انتہائی اطمنان و سکون بلکہ یقین کے ساتھ کہ رہا ہے تم ہرگز ہرگز اس کا مثل نہ لا سکو گے اور قرآن کا مثل لانا اس کائنات کی طاقت سے باہر ہے۔
ب :دعوت ایمان
قرآن مجید ایک بار بھی انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ جب تم اس کی مثل نہیں لا سکے ہو تو پھر جان لو کہ قرآن مجید پوری کائنات کے لیئے معجزہ ہے۔
لہذا تم ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر قرآن مجید اور پیغمبر اسلام کی رسالت پر ایمان لے آؤ ضروریات اسلام کو تسلیم کرو تب تمہاری بخشش کا سامان ہو سکتا ہے کیونکہ بخشش کے لیئے اسلام کے اصولوں کو دل وجان سے تسلیم کرنا ضروری ہے یہ تمہارے لیئے اتمام حجت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرلو جہنم کی آگ سے بچاؤ کی یہی ایک صورت ہے کہ اس دعوت ایمان پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرلو۔
ج: اتمام حجت کے بعد انکار کا نتیجہ
قرآن مجید نے اتمام حجت کردی تھی منکرین کے لیئے جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک موقعہ فراہم کیا تھا اب جن لوگوں نے اتمام حجت کے بعد بھی اگر اسلام کی پیروی نہ کی تو تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن بنو گے جیسا کہ خداوندعالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔
( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ )
تم اور جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں۔(۱)
آتش جہنم کا عذاب در حقیقت نا فرمان لوگوں کے لیئے ہے ان لوگوں کی اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہو گی کہ ان کے وہ معبود جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں انہیں بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے اس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو ان کے معبود تھے۔
____________________
(۱)انبیاء آیت ۹۸۔
چونکہ یہ لوگ یہ خیال کرتے تھے قیامت والے دن یہ بت اللہ کے سامنے ہماری شفاعت اور سفارش کریں گے آج انہیں بھی ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہاری کیا شفاعت کر سکتے ہیں یہ تو بالکل بے بس ہیں اگر تم اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ،رسول اور ضروریا ت دین کو دل سے تسلیم کر لو تب اس درد ناک عذاب سے تمہارا چھٹکارہ ہو سکتا ہے۔
( وَبَشِّرْ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِی رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ )
اے پیغمبر! جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں خوشخبری دے دیجئے ان کے لیئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جب بھی انہیں ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیئے ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو پہلے بھی ہمیں کھانے کے لیئے مل چکا ہے اور جو پھل انہیں پیش کیے جا ئیں گے( وہ خوبی و زیبائی )میں یکساں ہیں اور بہشت میں ان کے لیئے پاک و پا کیزہ ہوں گی اور یہ لوگ اس بہشت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جنہوں نے دعوت عبودیت کو قبول نہ کیا اور کفر اختیار کیا حالانکہ ان کے لیئے اتمام حجت بھی ہو چکی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اھل ایمان میں داخل ہو جائیں اس کے بعد انہیں حجج بینہ کے ساتھ دردناک عذاب سے ڈرایا گیا لیکن یہ لوگ راہ راست پہ نہ آئے۔
اب اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے دعوت عبودیت پر لبیک کہی ان کے لیئے بروز قیامت بلند مقام درجات اور نعمتوں کو بیان کیا جارہا ہے۔
بشارت الہی
قرآن مجید میں کئی طرح کی بشارت ہوتی ہے کبھی تو اس مورد کی عظمت کو بیان کرنے کے لیئے بشارت دی جاتی ہے جیسا کہ اس آیت میں صاحبان ایمان کو جنت کی بشارت دی جارہی ہے اس سے جنت کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے اسی طرح خداوند عالم کا یہ فرمان بھی جنت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔
( جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )
جنت جس کی وسعت سارے زمین و آسمان کے برابر ہے اور متقین کے لئے مہیا کی گئی ہے۔(۱)
اگرچہ اس آیت مجیدہ میں تشبیہ کا حکم ہے پیغمبر اسلام (ص) سے خطاب ہے لیکن آپ کے وسیلے سے آپ کی نیک اور صالح امت کو بھی شامل ہے جب امت آپ اور آپ کے حقیقی جانشینوں سے معارف الہی حاصل کر کے حقیقی متقی بن جائیں اور خدا کی واحدانیت،انبیاء کی نبوت اور آئمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کے ساتھ ساتھ ضروریات دین و مذہب پر عمل پیرا ہوجائیں تو اس وقت یہ بشارتیں ان کے لئے ہیں۔
ایمان اور عمل صالح
خدا وند عالم کی یہ سب بشارتیں ان لوگوں کی ہیں جو صاحب ایمان اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں،ایمان، عمل صالح سے جدا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں جہاں بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے وہاں صرف صاحب ایمان نہیں کہا گیا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔(۲)
لہذا جنت میں جانے کے لئے مومن ہونے کے ساتھ،عمل اور اصول عقائد کی پابندی بھی ضروری ہے۔ایمان اور عمل صالح سے ہی انسان کامل بنتا ہے،ایمان جڑ ہے اور عمل صالح اس کا پھل ہے جس طرح جڑ اور پھل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
____________________
(۱)آل عمران آیت نمبر ۱۳۳
(۲)ملاحظہ فرمائیں سورہ طلاق آیت نمبر ۱۱،سورہ نور آیت نمبر ۵۵۔
اسی طرح ایمان اور عمل بھی ہیں نیکی ایمان سے الگ نہیں ہو سکتی،بلکہ عمل صالح کی عملی شکل کا نام ایمان ہے۔رضائے الہی کے مطابق جو کام بھی کریں گے وہ عمل صالح ہو گا جو جتنا زیادہ رضائے الہی کا پابند ہو گا وہ اتنا بڑا مومن ہو گا،عمل صالح کے حقیقی مصداق آئمہ اطہار علیہم السلام ہیں جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔
فالذین امنو ه و عملوالصالحات علی ابن ابی طالب والا صیاء من بعد ه و شیعتهم
حقیقی ایمان لانے والے اور عمل صالح بجا لانے والے تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے اوصیاء ہیں اور پھر ان کے شیعہ ایمان و عمل کا نمونہ ہیں(۱)
بہر حال ایمان کے ساتھ ضروریات دین و مذہب پر قلبی طورپر عمل کرنے والا ہی جنت کی بشارت کا مستحق ہے اور حقیقی مومن ہے جیسا کہ سلیم بن قیس ھلالی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ ا لسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔
جو شخص اس دنیا سے اس حالت میں اٹھے کہ وہ اپنے امام کو جانتا بھی ہے اور اس کا مطیع بھی ہے تو کیا ایسا شخص اہل جنت سے ہو گا؟
حضرت نے فرمایا :
جو شخص بھی ایمان کی حالت میں اپنے اللہ سے ملاقات کرے وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام انجام دیے۔(۲)
____________________
(۱)بحار الانوار ج ۳۶ ص ۱۲۹۔
(۲)بحار الانوار ج۲۸ ص ۱۶،حدیث ۲۲۔
بہشت اور اس کی نعمتیں
صاحبان ایمان و عمل کے لئے جنت اور اس کی نعمتیں ہیں یعنی ان لوگوں نے دنیا میں جتنے نیک اعمال کیے تھے آخرت میں وہ سب ان کے سامنے ظاہر ہونگے کیونکہ اس کا عمل زندہ ہے اور بہشت و اس کی نعمتیں اسی عمل کا ظہور ہیں
الف :بہشت کے باغات
انسان کو اسکے عمل صالح اور ایمان کی وجہ سے ایسی جنت کے باغوں کی بشارت دی جا رہی ہے ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان درختوں پر انوع و اقسام کے پھل لگے ہوئے ہیں یہ لوگ جب بھی ان کا اردہ کریں گے یہ پھل ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور یہ اسے تناول کریں گے۔
جب انہیں کھانے کے لئے پھل دیے جاےئں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جسے پہلے ہم کھا چکے ہیں لیکن جب اسے کھائیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ اس کی لذت اور ذائقہ بہت عمدہ ہے اور حقیقت کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو ان پھلوں کے مشابہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ مشابہت کے لئے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ذاتی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہوں لیکن شکل وصورت میں ایک جیسی ہوں تو پھر ایک دوسرے کے مشابہ کہلاتی ہیں۔
ب:پاکیزہ بیویاں
صاحبان ایمان و عمل کے لئے ایک بشارت یہ ہے کہ انہیں وہاں پاکیزہ بیویاں میسر ہونگی اس سے مراد حوریں بھی ہو سکتی ہیں اور اس دنیا والی نیک بیویاں بھی ہو سکتی ہیں جب یہ بہشت میں داخل ہونگے تو اس دنیا میں جتنی جسمانی اور روحانی کثافتیں تھیں سب ختم ہو جائیں گی اور وہ ازداج مطا ھرہ کہلوانے کی مستحق قرار پائیں گی۔بہر حال مومنین کو حورالعین ملیں گی وہ حوریں،اخلاق کمال اور جمال میں بے نظیر ہونگی اور وہ ہر قسم کی نجاسات سے پاک و پاکیزہ ہونگی۔حضرت رسول اکرم (ص) سے منقول ہے۔ اگر جنت کی عورت ایک دفعہ زمین کی طرف دیکھ لے تو اس کی خوشبو پوری زمین کو معطر کر جائے گی۔ لہذا جسمانی اور روحانی نجاستوں سے پاک،تمام خصوصیات نسوانی کا مرقع بیویا ں صرف اہل ایمان کو نصیب ہونگی۔
نعمتوں میں دوام و ہمیشگی
انسان کو جب بھی اس دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے اسے یقین ہوتا ہے ایک دن وہ اس سے ختم ہو جائے گی اس کے باوجود اسے نعمت میسر آنے کے ساتھ ہی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے اور خدا کا شکر بجا لانے کے لئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔لیکن آخرت میں ان صاحبان ایمان و عمل کو بشارت دیجارہی ہے یہاں دنیا والا معمالہ نہیں ہے یہاں کی نعمتیں ا بدی ہیں اور جاودانی ہیں ان کے لئے فنا اور زوال کا تصور تک نہیں ہے۔
مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہے گاجنت کی نعمات سے لطف اندوذ ہوتا رہے گا۔ جنت کی کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے مقابلے میں بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت نہیں آسکتی کیونکہ دنیاوی نعمت کتنی ہی بڑی ہی کیوں نہ ہو آخر اس نے فنا ہو نا ہے اور جنت کی نعمت تو جاودانی ہے،یہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے اور کافر اور منافق کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لئے جہنم ہو گا۔حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی علت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔
انما خلد اهل النار فی النار لان ینانیهم کا نت فی الدنیا ان لو خلا وا فیها ان یعصوا الله ابدا و انما خلد اهل الجنة لان نیاتهم کانت فالدنیا ان لو لقوا فیها ان یطیعوا لله ابدا،النیات خلد هو لاء و هولا
اہل جنہم اس لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہم میں رہیں گے کیونکہ اس دنیا میں ان کی نیت ہی بد تھی اگر وہ کچھ دیر اس دنیا میں اور رہ لیتے تو خدا کی نافرمانی میں مبتلا رہتے۔ اہل بہشت اس لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے کہ اس دنیا میں ان کی نیت اچھی تھی اور اگر کچھ عرصہ اس دنیا میں اور زندہ رہتے تو اللہ تعالی کی اطا عت میں ان کی زندگی گزرتی اس لئے یہ ہمیشہ جنت میں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔(۱)
____________________
(۱)نور الثقلین ج ۱ ص۴۴۔
( إِنَّ اللهَ لاَیَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِینَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ )
بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے کم تر کسی چیز کی مثل بیان کرے اب جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے خدا اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہی میں صرف فاسقوں کو ڈالتا ہے۔
شان نزول
اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے ابن مسعود روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے منافقین کی پہچان کے لیئے اسی سورہ کی ۱۷ ویں اور ۱۹ ویں آیات میں مثال کے ذریعے ان کے حقائق سے پردہ اٹھایا تو وہ کہنے لگے خدا سے بعید ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے۔
ان کے جواب میں خداوندعالم نے اس آیة مبارکہ کو نازل کیا کہ اللہ تعالی کو مچھر اور اس سے کمترکسی چیز کی مثال بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔اسی طرح اس آیت کے شان نزول کے حوالہ سے قتادہ کی یہ روایت بھی کتب تفسیر میں موجود ہے کہ خداوندعالم نے سورہ عنکبوت کو نازل کیا تو یہودی اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے یہ خدا کی نازل کردہ سورہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی سے بعید ہے کہ وہ ایسی چیزیں بیان کریں۔
اس وقت یہ اایت نازل ہوئی اور خداوندعالم منافقین اور کافرین کے حقائق کو ایسی مثالوں سے بیان کرسکتا ہے۔مچھر ہو یا عنکبوت کی مثال سب اللہ کی طرف سے ہیں اسی کمتر مخلوق مچھر ہی نے تو نمرود جیسے مغرور شخص کو ہلاک کر دیا تھا اور عنکبوت (مکڑی) نے غار ثور کے دھانے جالہ بن کر پیغمبر اسلام کی حفاظت کی تھی،یہ حقیر چیزیں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے تو تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا تھا نمرود ظالم تھا اسے مچھر نے ہلاک کر کے نئی تاریخ لکھی ادھر مکڑی نے ظالموں سے حضرت کی حفاظت کر کے تا ریخ رقم کی۔
قرآنی تمثیل
قرآن مجید وحی الہی ہے اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے قرآن کے مخالف کھبی تو قرآن کے انداز بیان پر اعتراض کرنے لگتے ہیں اور کھبی قراانی مطالب کو پسند نہیں کرتے۔اس آیت میں خدا ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمارہا ہے کہ تمہیں مطلب سمجھانے کے لیئے مثال دی ہے یعنی انسانی ذہن محسوسات سے مانوس ہے وہ اس وقت تک کسی حقیقت کا آسانی سے تصور نہیں کرسکتا جب تک حسی شکل میں اس کی مثال نہ بیان کر دی جائے اور انسانی مشاہدے کو مدنطر رکھ کر مثال نہ پیش کر دی جائے۔
اسی وجہ سے قرآن مجید نے چھوٹی اور بڑی چیزوں کی مثالیں بیان کر کے مطالب کو سمجھایا ہے لہذا خدا ایسی مثالیں دینے سے نہیں شرماتا اور اس مثال کو اپنی اور اپنے کلام کی شان کے خلاف نہیں جانتا خواہ مچھر سے مثال دی جائے یا اس سے کمتر کسی اور مخلوق سے مثال دی جائے کیونکہ اللہ کا مقسد صرف حقیقت کو انسان کے ذہن کے قریب لانا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی مطالب کو کبھی برہان ذریعہ بیان کرتا ہے کبھی جدال احسن،کبھی موعظہ اور کبھی مثال کے ساتھ بیان کرتا ہے۔
مچھر کی مثال کیوں
منافق کافر اور مشرک آپس میں مل بیٹھ کر اعتراض کرتے تھے کہ مچھر ایک حقیر سی مخلوق ہے خدا وند متعال نے اس کا تذکرہ کیوں کیا ہے اس کی نسبت کسی بڑی مخلوق کو بیان کرتا،لیکن حقیقت یہ ہے کہ مچھر بھی بہت بڑی مخلوق ہے،اسی مچھر کے متعلق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں۔
ولو اجتمع جمیع حیوانها من طیرها و بها ئمها و کان من صراحها و سائمها و اضاف اسناخها و اخباسها و قبلدة اممها و اکیاسها علی احداث بعوضةما قدرت علی احداثها ولا عرضت کیف السبیل الی ایجادهاو تحیرت عقولها فی علم ذلک و تاهت و عجزت ۔
تمام حیوان خواہ پرندے ہوں یا جانور رات کو پلٹ کر آنے والوں میں سے ہوں یا چراگاہوں میں رہنے والے ہوں،یعنی کسی صنف سے تعلق رکھتے ہوں اور تمام خواہ کند ذہن ہوں یا ذہین اور ہوشیار اگر یہ سب مل کر بھی ایک مچھر پیدا کرنا چاہیں تو وہ اسے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کہ اسے کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے اسے جاننے کے لیئے ان کی عقلیں حیران و سر گردان ہیں قوتیں عاجز اور درماندہ ہو جائیں گی۔ آخر کا ر شکست خوردہ ہو کر اقرار کر لیں گے کہ وہ اسے نہیں بنا سکتے اور ہم اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں اور یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اسے فنا کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔(۱)
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مچھر کی مثال کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں۔
خداوندعالم نے مچھر کی مثال دی ہے حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات و اعضاء و جوارح ہیں جو خشکی پر رہنے والے سب سے بڑے جانور (ہاتھی )کے جسم میں ہیں بلکہ اس کے جسم میں دو اعضاء ہاتھی کی نسبت زیادہ ہیں (سینگ و پر ) جو ہاتھی کے پاس بھی نہیں ہیں۔(۲)
خداوندعالم اس مثال سے خلقت و افرینش کی خوبی و عمدگی بیان کررہا ہے یہ ظاہرا کمزور جانور ہے جسے خدا نے ہاتھی کی طرح کلق کیا ہے اس میں غور و فکر انسان کو اس خالق حقیقی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔اس مچھر کی سونڈ ہاتھی کی سونڈ کی مانند ہے اور اندرسے خالی ہے اور مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے بلکہ یہ دنیا کی عمدہ سرنگ معلوم ہوتی ہے اور اس کا اندورنی سوراخ بہت باریک ہے۔ خدا مچھر کو جذب دفع اور ہاضمے کی قوت دی ہے اسی طرح اسے مناسب ہاتھ پاؤں اور کان عطا فرمائے ہیں اسے پر دیئے ہیں تا کہ غذا تلاش کر سکے اور یہ پر اتنی تیزی کیساتھ اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں کہ آنکھ سے یہ حرکت نہیں دیکھ سکتے
____________________
۰۰۰نہج البلاغہ خطبہ ۱۸۶۔۰۰۰۰۰۰صافی ج ۱ ص ۱۰۴۔۰۰۰
اور یہ جانور اتنا حساس ہے کہ کسی چیز کے اٹھنے کے ساتھ ہی یہ خطرہ معلوم کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے خود کو خطرہ سے دور کر لیتا ہے اور انتہائیہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا کمزور ہونے کے باوجود بڑے بڑے جانوروں کو عاجز کر دیتا ہے۔
قرآنی مثالیں اور انسانی رویہ
قرآن مجید میں بہت سی مثالیں موجود ہیں خداوندعالم نے مچھر یا اس جیسے یا اس سے کمتر مخلوق کی مثالوں کے ساتھ حق کو بیان کرتا ہے اس طرح عقلی حقائق کو حسی مثالوں کی شکل میں بیان کر کے ھق کو واضح کرتا ہے۔خدا وندعالم نے مچھر مکھی مکڑی شہد کی مکھی اور چیونٹی جیسی چیزوں کے ساتھ مثالیں پیش کی ہیں ان کی وجہ سے لوگو ں کا رویہ دوطرح ہو گیا ہے زیرنطر آیت میں لوگوں کے دوگروہوں میں تقسیم ہو کر مثالوں کے متعلق مختلف نطر اور رویہ کو بیان کیا گیا ہے۔
جو لوگ ایمان لائے انہوں نے توحید قرآن مجید انبیاء اور آئمہ اطہار علیہم السلام کو قبول کر لیا اور پکے مومن بن گئے جب ان کے سامنے ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں تو انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ مثالیں پروردگار عالم کی طرف سے حق ہیں انہیں کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے پیش کیا گیا ہے لیکن ان کے مقابل کافر فاسق اور دوسرے لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں ان کا رویہ مومنین سے جدا ہے یہ لوگ جب ایسی مثلیں سنتے ہیں تو دشمنی کی وجہ سے کہتے ہین بھلا ان مثالوں کا کیا فائدہ نجانے خدا نے انہیں کیوں بیان کیا ہے ہمیں تو یہ ایک عبث اور فضول کلام لگ رہا ہے اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔
ہدایت اور گمراہی
خداوندعالم اس آیت میں ارشاد فرمارہا ہے کہ ان مثالون کا فائدہ یہ ہے کہ بعض ان مثالوں سے ہدایت پا جاتے ہیں اور بعض لوگوں کا مقدر ضلالت اور گمراہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی فکر سے تدبیر نہیں کی جس کی وجہ سے یہلوگ حقیقت کا انکار کر بیٹھے خدا نے بھی اپنے لطف و تو فیق کا ان پر راستہ بند کر دیا ہے اور انہیں ضلالت و گمراہی کی وادی میں سرگردان چھوڑ دیا ہے۔
جن لوگوں نے ان مثالوں میں غور وفکر کیا انہوں نے عقل اور توفیق سے ہدایت کی راہ تلاش کر لی تو ان کی آنکھوں سے حجاب ہٹ گئے اور انہیں ان مثالوں کے ذریعے ہدایت نصیب ہوئی۔
خداوندعالم نے اس آیت میں ہدایت و گمراہی کو اپنی طرف نسبت دی ہے اس مراد یہ ہے کہ یہ گمراہی انسان کے برے عمل کی وجہ سے ہے کیونکہ انسان حجت عقل نقل کتاب سنت کے ہوتے ہوئے بھی صراط مستقیم پر نہ چل سکے تو بہ کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود گناہ طغیانی اور سرکشی پر مصر رہے تو ایسا شخص اپنے سو اختیار کی وجہ سے صراط مستقیم سے منحرف ہو جائے گا اس وقت اللہ بھی اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور مزید لطف توفیق کا راستہ اس پر بند کر دیتا ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّـهُ قُلُوبَهُمْ ) ۔(۱)
جب وہ اپنے حق سے منحرف ہوئے تو خدا نے بھی ان کے دلوں کو منحرف کردیا۔
جبر کی نفی
اس آیت کے آکر مین خداوندعالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ گمراہی صرف ان فاسقوں کا مقدر ہے یعنی جو لوگ اپنے ارادے اور سو اختیار کی وجہ سے د ین سے خارج ہو گئے ہیں یہ فاسق کہلاتے ہیں۔(۲)
اللہ کا مقصد انہین گمراہ کرنا نہیں ہے لیکن ان مثالوں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض تو ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور بعض تعصب اور عناد کی وجہ سے مزید گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گمراہی ان کے لیئے ہے جو ابتداء ہی سے راہ حق سے ہتے ہوئے ہیں یعنی یہ گمراہی ہمارے اپنے سو اختیار اور بد اعمالی کی وجہ سے ہے اللہ نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا بلکہ انہیں تو اختیار تھا انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا اور ہدایت کو چھوڑ بیٹھے۔
____________________
۰۰۰ صف آیت ۵۔۰۰۰
(۲)المراد بافاسقین ھنا الخارجون عن حدودالایمان،روح المعانی ج ۱ ص ۲۱۰،
( الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُوْلَئِکَ هُمْ الْخَاسِرُونَ )
اور جو خدا سے محکم عہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن (تعلقات)کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی لوگ خسارے میں ہیں۔
گزشتہ آیت مین خداوندعالم نے صرف فاسقوں کو گمراہ قرار دیا ہے اس آیت میں ان کے تین اوصاف بیان کر کے انہیں بالکل مشخص کردیا ہے،ان لوگوں نے قرآنی امثال سے ہدایت حاصل نہ کی بلکہ گمراہی کو اختیار کیا یہ گمراہی ان کی طبیعت فسق کا نتیجہ ہے ذیل میں ان کی صفات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔
( ۱) عہد شکنی
اس آیت مین خداوندعالم نے فاسقوں کی پہلی صفت عہد شکنی قرار دیا ہے عہد شکنی دو طرح سے ہو سکتی ہے کبھی تو انسان بذات خود کسی عہد کو وفا نہیں کرتا اور کبھی اپنے اور عہد کے درمیان رابطہ کو منقطع کر لیتا ہے وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں وہ سب اللہ کا عہد ہیں جو شخص ان میں تحریف کا موجب بنے یا ان سے اپنا تعلق اور رابطہ منقطع کرلے تو وہ عہد شکن ہے۔
خداوندعالم بتا رہا ہے کہ فاسق خداسے محکم عہد وپیمان باندھ کر عہد شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں یعنی انسانوں نے خدا سے مختلف عہد وپیمان باندھ رکھے ہیں مثلا توحید و خداشناسی کا پیمان شیطان کی پیروی نہ کرنے کا پیمان،ضروریات دین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا پیمان،انبیاء،آئمہ قیامت و دین کے تمام اوامر و نہی کو قبول کرنے کا پیمان،گویا خدا کے ساتھ محکم عہد پیمان باندھنے کے بعد توڑنا فاسق کی نشانی ہے۔
اس خدائی عہد کو توڑنے والے مختلف گروہ مراد ہو سکتے ہیں منافق اس لیئے عہد شکن ہے کیونکہ اس نے ظاہری اسلام قبول کیا حضرت رسالت کو قبول کیا احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کا عہد وپیمان باندھنے کے باوجود یہ لوگ کبھی قرآن میں اعتراض کا پہلو تلاش کرتے کبھی حضرت کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے کبھی احکام الہی کا استھزاء کرتے لہذا یہ لوگ عہد شکن کہلائے۔
کافر اس لیئے عہد شکن ہیں کیونکہ یہ لوگ عقل سلیم،فطرت کے خلاف برسرپیکار ہیں انہیں بہت سی نعمتیں دی گئیں ان کی ہدایت کے لیئے عقل کے علاوہ انبیا اور آئمہ اطہار علیہم السلام بھیجے گئے تا کہ کسی نہ کسی طرح یہ اپنے فطری عہد پر عمل پیرا ہوں جیسا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے۔
و بعث فیهم رسله وواتر الیه انبیائه یستادوه میثاق فطرته،
خداوندعالم نے لوگوں کے پاس اپنی طرف سے یکے بعد دیگرے انبیاء اور رسول بھیجے تا کہ وہ ان سے یہ خواہش کریں کہ وہ اپنے فطری پیمان پر عمل کریں۔
جب ان لوگوں نے اپنی فطرت کے مطابق عمل نہ کیا تو گویا انہوں نے عہد پیمان کو توڑ دیا،اس طرح خدا سے عہد شکنی کرنے والے اھل کتاب بھی ہیں خدا نے ان سے ان کی کتابوں میں عہد لیا تھا ان کی کتب میں انہیں پہلے سے نبی آخرالزمان کی بشارتیں دی گئی تھیں لیکن جب آپ(ص) مبعوث ہوئے تو انہوں نے اللہ سے کیا عہد وپیمان توڑ ڈالا اور اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا فاسقوں کی یہ صفت صرف اس دور کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ آج بھی جو دین اسلام،حجرت نبی آخر الزمان،اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید اور ضروریات دین کو نہ مانے تو حقیقتا وہ اللہ سے باندھے ہوئے مستحکم عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو گا۔
قطع تعلق
خداوندعالم نے جن تعلقات کا انہیں حکم دیا ہے یہ لوگ ان تعلقات کو منقطع کر لیتے ہیں یعنی خداوندعالم نے جن رشتوں اور تعلقات کو جوڑنے اور مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے یہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے اس پر قائم نہیں رہتے،اس سے تمام حقوق مراد ہیں خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق الناس ہوں اللہ نے ان حقوق کو قطع کرنے سے منع فرمایا ہے۔جو انسان،خدا،اسکی وحدانیت،اس کے فرامین اس کے انبیاء اور انکے آئمہ اطہار سے رابطہ منقطع کر لیتا ہے تو گویا وہ فاسق ہے جیسا کہ بعض روایات میں بھی اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے ہمیں حضرت امیرالمومنین اور آئمہ اہلبیت علیہم السلام سے تعلق جوڑے رکھنا چاہیے(۱)
ان سے تعلق کو توڑنے والا اور ان سے رابطہ منقطع کرنے والا فاسق ہے،اسی طرح حقوق الناس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے،اس میں صلہ رحمی،عزیزوں اور دوستوں سے تعلق اور محبت ان سے قطع تعلق ان کے دوسرے حقوق کا خیال رکھنا ان کی حق تلفی نہ کرنا معاشرے سے رشتہ جوڑے رکھنا ضروری ہے جو لوگ حقوق الناس کا خیال نہیں کرتے وہ اس آیت کی روسے فاسق ہیں کیونکہ اللہ تعالی اس آیہ مجیدہ میں فاسق کی دوسری علامت اور صفت قطع تعق کو بیان فرمارہا ہے۔
۰۰۰ولیقطعون ما امر الله به یعنی من صله امیر المومنین والآئمه،
____________________
نور الثقلین ج ۱ ص ۴۵۔۰۰۰
فساد فی الارض
فاسقون کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ لوگ زمین مین فساد برپا کرتے ہین یعنی خداوندعالم نے انہیں اس دنیا کو قبول کرنے ضروریات پر عمل پیرا ہونے اور توحید انبیاء اور قیامت پر صحیح عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ اس دین کے مقابلہ میں اپنا غلط عقیدہ رکھتے ہیں لوگوں کو اسلام کے سامنے سرتسلیم خم کرنے سے روکتے ہیں حق و حقیقت کا استہزاء کرتے ہیں مومنین کو اذیتیں دیتے ہیں اس نظام ہستی میں موجود اصلاح سے سبق حاصل نہیں کرتے بلکہ خلق خدا کی گمراہی کا سامان پیدا کرتے ہیں یعنی یہ لوگ اپنے طرز عمل سے زمین خدا پر فساد برپا کرتے ہیں تا کہ لوگوں کے عقائد حقہ میں تزلزل پیدا ہو جائے۔
فاسق خسارے میں ہیں
اس آیت کے آخر میں خداوندعالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ مندرجہ بالا صفات کے مالک ہیں وہ خسارے اور نقصان میں ہیں یعنی جو لوگ ہدایت فطری کا سرمایا اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں،حقوق اللہ اور حقوق الناس کا خیال نہیں رکھتے بانی شریعت کو تکلیف میں مبتلا کرنے میں کوشاں رہتے ہیں اسلامی احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے فساد کا موجب بنتے ہیں۔
یہ اس دنیا میں بھی خسارے میں ہیں کیونکہ ان پر کوئی اعتماد نہیں کرتا انہیں قلبی سکون میسر نہیں ہوتا،ہر وقت پریشانی انہیں دامن گیر رہتی ہے،ساری زندگی منافقت اور غلط کاری میں گزار دیتے ہیں اپنی تمام سعادتیں بدبختی اور سیاہ کاری میں خرچ کرتے ہیں اور دین الہی سے کارج ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ لوگ خسارے میں ہوں گے اور جہنم کا ابدی عذاب نہ صرف ان کا بلکہ ان کے خاندان کا بھی مقدر ہو گا،جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ ) (۱)
فسق کی راہ اختیار کرنے والے خود بھی خسارے اور گھاٹے میں ہیں اور اپنے خاندان کو بھی قیامت تک اس خسارے اور نقصان میں مبتلا کر دیں گے۔
___________________
۰۰۰ زمر آیت ۱۵ ۰۰۰
( کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللهِ وَکُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ) ( ۲۸)
تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی دی پھر وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں زندگی دے گا اور پھر اس کی طرف لٹا ئے جاؤ گے۔
توحید شناسی۔
خدا کی سر زنش
یہ اور اس کے بعد آنے والی آیت انسان کو خدا کی عظمت اور توحید شناسی کی طرف متوجہ کر رہی ہے گویا خدا وند عالم نے۔ ۱۲،۲۲ آیت میں تو حید شناسی کے حوالہ سے جو دلائل بیان کیے تھے ان کی تکمیل کرتے ہوئے انسانوں کو سر زنش کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس قدر نعمتیں عطا کیں ہیں اس کے باوجود تم کیونکر انکار کرتے ہو۔اس آیت میں خدا بیک وقت کافر،منکر اور مسلمان سب کو مخاطب ہے کافروں کے لئے یہ برھان اور حکمت کے عنوان سے ہے۔
جبکہ تمہارا اور اس پوری کائنات کا خالق میں ہوں تو پھر انکار کیسا؟ لیکن جو لوگ اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں ان کے لئے یہ آیت جدال ہے کہ جو حقیقی خالق ہے موت وحیات بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہی پوری کائنات کو مدبر ہے۔
اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہوسکتا تم صرف اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرسکتے ہو،جب وہی سب کچھ ہے تو پھر انکار کیسا؟اور جو لوگ خدا کی خالقیت اور ربوبیت کے قائل ہیں لیکن معصیت اور سرکشی کر بیٹھے ہیں اور خود کو مسلمان کہلوانے کے باوجود بد عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
ان کو وعظ و نصیحت اور سرزنش کی جا رہی ہے کہ خود کو سنبھال لو۔موت وحیات سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے تو پھر صراط مستقیم سے منحرف کیوں ہو جاتے ہو کیوں خدا کی اطاعت اور پیروی میں سستی سے کام لیتے ہو۔
بہرحال اتنے واضح اور روشن دلائل کے بعد اس ہستی کا انکار یا اس کے احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی درست نہیں ہے انہیں تو اپنی خلقت اور موت حیات کے متعلق غور فکر کرنا چاہیے۔شاید اس کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
دنیاوی زندگی
خداوند عالم انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا رہا ہے کہ خدا نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے وہ اس کا لطف ہے تم کچھ بھی نہ تھے ہم نے تمہیں خلق کیا جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ) (۱)
یعنی تم کچھ بھی نے تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔
خداوند متعال اس مقام پر فرما رہا ہے کہ تم مردہ تھے ہم نے تمہیں نعمت حیات سے نوازا ہے اگر تم صحیح معنوں میں اپنے متعلق غور فکر کرو تو تمہیں خدا کی وحدانیت کا یقین پیدا ہو جائے گا۔
___________________
( ۱) مریم ۹ ۔
یہ جملہ انسانی وجود کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے انسان اپنے سفر کا آغاز نقص سے شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ راستہ طے کرتا چلا جاتا ہے اور نقطہ کمال تک جا پہنچتا ہے۔
اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ مردہ تھا پھر نجانے کتنے مراحل طے کرنے کے بعد اس دنیا میں آیا خدا نے اسے نعمت حیات سے سرفراز کیا پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسے اس دنیا سے جانا پڑا پھر اسے قیامت والے دن دوبارہ زندگی ملی حساب کتاب ہوا گویا اس کی زندگی آغاز سے انجام تک تغیرات سے پر ہے۔
خدا اس انسان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے تم کس طرح کفر اختیار کرتے ہو کیوں خدا کی طرف نہیں آتے حالانکہ تم مردہ تھے تمہیں زندگی ملی اور تم جانتے ہو تم کن کن مراحل سے گزرے ہوئے کیسی کیسی تبدیلیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑا تم کتنے حجابوں اور پردوں میں پوشیدہ تھے ہم نے تمہیں حیات دی اور تمہارے بے جان جسم میں روح پھونکی۔یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم عدم سے وجود میں آئے لہذا اس نعمت حیات کا قدر دان کبھی بھی جنت کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا معاملہ نہیں کرے گا جو لوگ ایسی عظیم نعمت دینے والی ہستی سے غافل ہیں انہیں بہت جلد اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے اور آخرت کا دردناک عذاب ان کا ٹھکانہ ہو گا۔
جیسا کہ خدا کا فرمان ہے۔
( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) ۔
اگر تم میرا شکر بجا لائے تو میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا اور اگر تم نے کفر کیا تو میراعذاب بھی شدید تر ہے۔
لہذا انسان کو اپنے اس زندگی کے ابتدائی مرحلے میں اپنے اختیار کی وجہ سے ایسی راہ کا انتخاب کرنا ہو گا جس میں سعادت ہی سعادت ہو اور وہ اگر اپنے سوء اختیار کی وجہ سے اس دنیا میں بد کاری اور غلط کاری میں مصروف رہے،اصول دین پر اس کا صحیح اعتقاد نہ ہو،فروع دین کی بناآوری میں کوتاہی کرتا رہے تو اس نے اپنی زندگی کے اس مرحلے میں اپنے لئے کچھ مہیا نہیں کیا لہذا اس کی سزا بھی اس کے اپنے سوء اختیار کی وجہ سے ہے اور جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہو گی۔
عالم برزخ کی زندگی
قرآن مجید کی یہ آیت عالم دنیا میں اور عالم آخرت کے درمیانی عالم،عالم برزخ کی زندگی پر ایک واضح دلیل ہے کیونکہ اس آیت میں ایک اور اس کے بعد زندہ کرنا ہے۔پھر موت اور زندگی ہے اور تیسرے مقام پر خدا کی طرف لوٹنا ہے کیونکہ اس آیت میں صرف الیہ یرجعون نہیں ہے بلکہ ثم الیہ یرجعون ہے،ثم فاصلے پر دلالت کرتا ہے یہ ایک فاصلے کا زمانہ عالم برزخ ہے
اس دنیا سے جانے کے بعد اور آخرت سے پہلے انسان کو عالم برزخ کا سامنا کرنا ہو گا،عالم برزخ کا سفر قبر میں شروع ہو جاتا ہے اس پر تمام مذاہب اسلام متفق ہیں کہ انسان سے قبر میں منکر نکیر آکر سوالات کرتے ہیں اور انہیں جوابات دینا ہو ں گے عالم برزخ انسان سے اس کے اعتقادات کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں اگر وہ اس کا درست جواب دے دیں تو اس کی قبر روشن ہو جائے گی اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھل جائے گا تاکہ نسیم بہشت سے بہر مند ہوسکیاور اگر جواب نہ دے سکے تو اس کی قبر میں آگ لگ جائے گی اور عذاب اس کا مقدر ہو گا۔
جیسا کہ حضرت رسول اعظم کا ارشاد ہے۔
القبر روضة الجنة او حفرة من حفر النیران
قبر یا تو جنت کے باغات میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔
قبر کے سوالات
انسان کا عالم برزخ کے لئے سفر کا آغاز قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے،اس عالم میں انسان کے اعتقادات کے متعلق سوالات ہو تے ہیں،اصول دین کے متعلق پوچھا جاتا ہے فروع دین کے متعلق سوالات عالم آخرت میں ہو ں گے یہاں اسے تو حید،عدل،نبوت،امامت اور قیامت کے متعلق جواب دینا ہوں گے۔جیسا کہ صحیح اورمستند روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آپ کی تجھیز،تکفین اور تدفین میں شریک ہوئے آپ نے اپنی ردا مبارک سے بی بی کو کفن پہنایا،آپ کو دفن کرنے سے پہلے حضرت آپ کی قبر میں لیٹے اور اس کے بعد،بی بی کو دفن کیا تعویض قبر بند کرنے کے بعد قبر کے نزدیک ہی بیٹھ رہے اور پھر بلند آواز سے ارشاد فرمایا۔
ابنک،ابنک،ابنک،
آپکا بیٹا،آپکا بیٹا،آپکا بیٹا،
جب آپ واپس تشریف لائے تو اصحاب نے سوال کیا
یا رسول اللہ آپ نے کسی کے ساتھ لطف و کرم نہیں فرمایا جتنا آپ نے بی بی کے لئے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بی بی میری ماں کا رتبہ رکھتی ہے اس نے اولاد سے بڑھ کر میرا خیال رکھا ہے میں نے اسے اپنی چادر میں اس لئے کفن دیا ہے تاکہ اس کی حرمت و بزرگی کو محفوظ رکھ سکوں اور قبر میں اس لئے لیٹا تھا تاکہ حشرات الارض اسے اذیت نہ دے سکیں۔
اصحاب نے سوال کیا قبر بند ہونے کے بعد آپ نے ابنک،ابنک،ابنک فرمایا تھا،اسکا کیا معنی ہے؟
حضرت نے فرمایا جب تعویض قبر بند ہوا تو منکر نکیر آگئے اور انہوں نے سوال کیا:
من ربک
تیرا رب کون ہے؟
جواب ملاالله ربی ۔
اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے۔
پھر سوال ہوا
من امامک،
فاطمہ بنت اسد خاموش ہوگئیں تو میں نے انہیں تلقین کی
ابنک،ابنک،ابنک، آپکا بیٹا،آپکا بیٹا،آپکا بیٹا،آپ کا امام ہے
یہ سننے کے بعد منکر نکیر وہاں سے چلے گئے۔
روایات میں ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے زندہ کرتا ہے اسے دوبارہ حیات ملتی ہے،اسکے حواس پلٹ آتے ہیں بدن میں روح وآپس آجاتی ہے تاکہ وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے سکے توحید کی وحدانیت،رسالت پیغمبر کی گواہی اور امامت و ولایت امیر المومنین اور دوسرے ائمہ اطہار علیہم السلام کو بیان کر دے تو اس کے لئے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ آرام دہ زندگی گزارتا ہے۔
عالم آخرت کی زندگی
ثم الیہ ترجعون سے خداوندعالم آخرت کی زندگی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے بلکہ یہ آیت معاد پر ایک محکم دلیل ہے کیونکہ کافر مبداء و معاد کا انکار کرتے ہیں قرآن مجید ان کی تصویر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں۔
( ما یُهْلِکُنا إِلاَّ الدَّهْرُ )
ہم تو ایک زمانے تک ہلاک ہو نگے اور اللہ کا فرمان ہے۔
( وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ) ۔
ہم دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔
خداوندعالم انہیں اس آیت میں کہہ رہا ہے تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس دن دوبارہ زندہ کرنا بے مقصد اور عبث نہیں ہے۔اس دن اپنے اعمال و حساب وکتاب کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہو گا اور خدا تعالی کے حکم سے جہنم اور جنت کی طرف روانگی ہو گی نیک
اور صالح لوگ اپنے اعمال کی جزا دیکھنے کے لئے جنت میں جائیں گے اور بد کار و فاسق لوگ اپنے اعمال کی سزا پانے کے لئے جہنم میں دھتکارے جائیں گے۔
لہذا قرآن مجید کی یہ آیت انسان کے آغاز وسط اور اختتام کو بیان کر رہی ہے یعنی انسان کی تین حالتیں ہیں ایک اس کا آغاز ہے،عدم سے وجود میں آنا ہے اس دنیا میں انسان کی پیدائش اس کا آغاز ہے،اور مرنے کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ مرحلہ عالم برزخ ہے
__________________
۰۰۰۰ جاثیہ ۲۴۔۰۰۰۰ ۰۰۰۰انعام ۲۹۔۰۰۰۰
یہاں اس سے اعتقادات کے متعلق سوال ہو گا اور اس کے بعد آخری مرحلہ حساب کتاب اور سزا و جزا کا ہے جیسا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کیف تکفرون باللہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔
( کنتم امواتا ) ،فی اصلاب ابائکم و ارحام امهاتکم ( فا حیاکم ) اخبرکم احیاء ( ثم یمیتکم ) فی هذا الدنیا و یقبرکم ( ثم یحیکم ) فی القبور ( ثم الیه ترجعون ) فی الاخرة بان تموتوا فی القبور بعد ثم تحیو ا للبعث یوم القیامه ترجعون الی ما وعدکم
تم باپ کے صلب اور ماں کے رحم میں مردہ تھے خدا نے تمہیں زندہ پیدا کیا پھر تمہیں اس دنیا میں موت دے گا اور تمہیں قبروں میں ڈالا جائے گا پھر تمہیں قبروں سے زندہ نکالے گا پھر تمہیں آخرت والے دن اس کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا یعنی تم مردہ قبروں میں ڈالے گئے
،تمہیں زندہ کیا گیا قیامت کی طرف بھیجا گیا اور پھر تمہیں (جزا سزا کے بعد)تمہارے وعدے کے مطابق بھیجا جائے گا۔
لہذا اس آیت میں خدا انسان کو خبردار کر رہا ہے کہ جب تیری ابتداء بھی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے تیری انتہا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور درمیانی مرحلہ میں بھی تو خدا کا محتاج ہے تو پھر بھی تو خدا کا کفر اور انکار کرتا ہے۔
( هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَی إِلَی السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ )
وہ اللہ جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لئے پیدا کیا اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات مستحکم آسمان بنا دئیے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
عظمت انسان
خداوندمتعال گزشتہ آیت سے الہی نعمتوں کاتذکرہ فرما رہا ہے اس آیت میں انسان کی نعمت حیات کاتذکرہ کیا تھا اور اب اس آیت میں خدا زمین جیسی اہم نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے یہ زمین قدرتی ذخائر کا خزانہ ہے اس میں نباتات،جمادات اور معدنیات جیسی عظیم نعمتیں موجود ہیں یہ سب انسان کی بقا کے لئے خلق کی گئیں ہیں۔
خداوندعالم انسان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس جہاں میں موجود ہر چیز انسان کے لئے خلق کی گئی ہے تاکہ انسان اس سے استفادہ کرے۔
خداوندعالم ان نعمتوں کی یاد دھانی اس لئے کروا رہا ہے تاکہ انسان کو دعوت توحید دینے کے ساتھ ساتھ مہذب بھی بنائے۔
دعوت توحید اس طرح ہے کہ جب وہ یہ سوچ لے گا کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لئے خلق کی گئی ہے اور اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا پورا پورا حق حاصل ہے اور اسے جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق اور اس کی نشانیاں ہیں تو وہ ان کے مشاہد ہ اور مطالعہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی معرفت پیدا کرے گا۔
انسان کو مہذب اس عنوان سے بنایا ہے،جب اسے یہ معلوم ہو گا کہ یہ سب نعمتیں صرف اور صرف انسان کے لئے خلق ہوئی ہیں تو وہ غور کرے گا کہ میں کس لئے پیدا کیا گیا ہوں تو اسے مقصد تخلیق صرف عبادت خداوندی نظر آئے گا یعنی زمین و آسمان اور نعمتوں کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت کے لئے ہیں اور انسان کا کمال یہ ہے کہ خدا کا عبادت گزار عبد کہلوائے۔
لہذا جو لوگ صرف مادی فوائد اور ان نعمتوں کے حصول کو اپنی زندگی کا مطمع نظر قرار دیتے ہیں وہ سب خسارے میں ہیں حتی کہ وہ تمام کہکشاؤں کے بدلے اپنا عقیدہ اور عمل ہاتھ سے دے بیٹھے تب بھی وہ خسارے میں ہے اس کا نفع صرف اور صرف عبادت خداوندی ہے۔
جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا ارشاد گرامی ہے۔
یا عم ! والله لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر
چچا جان! خدا کی قسم اگر میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر مہتاب رکھ دیں تب بھی میں ھدف الہی سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔
لہذا ایسے انسان پر تعجب ہے جسے خدا نے اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کے باوجود
یہ کفران نعمت کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے زمین آسمان کی تمام نعمتیں اس کے اختیار میں دے رکھی ہیں لہذا یہ بھی اپنا حق ادا کرے اور خدا کی عبادت کو ہی مشعل راہ قرار دے اور کسی صورت میں اپنے عمل اور عقیدے سے منحرف نہ ہونے پائے۔
نعمت آسمان
خداوندعالم زمین جیسی عظیم نعمت کے بعد نعمت آسمان کو بیان کیا ہے کہ یہ بھی انسان کے فائدے کے لئے خلق کیے گئے ہیں یہ زمین کی فضا پر ایک مضبوط چھت کی طرح ہے اور یہ اس قدر مضبوط اور قوی ہے اس کی وجہ کے آسمانوں سے پتھروں سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ پتھر شب روز کشش زمین کے مرکز میں کھنچے آتے ہیں اگر یہ مضبوط چھت نہ ہوتی تو ہم ہمیشہ ان خطرناک پتھروں کی زد میں رہتے یہ اس کی جلد کا سبب ہے کہ یہ پتھر زمین کی فضا میں ہی جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے شر سے محفوظ ہیں۔
سات آسمان
اس حوالہ سے علماء مفسرین میں ایک بحث موجود ہے کہ سات آسمانوں سے کیا مرادہے۔
بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد سیارات سبع یعنی عطارد،زہرہ،مریخ، مشتری، زحل،چاند اور سورج ہیں۔بعض کے نزدیک ان سے مراد زمین سے اوپر ھوائے متراکم کی مختلف تہیں مراد ہیں اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں سات کے عدد کو کثرت کے معانی میں استعمال کیا گیا ہے یعنی اس سے عالم بالا کے کرائت مراد ہیں کوئی مخصوص عدد مراد نہیں ہے۔
بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد سات آسمان ہی ہیں اور جتنے کرات اور سیارات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ سب پہلے آسمان کا جز ہیں جبکہ دوسرے چھ آسمان ہماری نگاہوں اور علمی آلات کی دسترس سے باہر ہیں۔
جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ) ۔(۱)
ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے سجایا
اور دوسری آیت میں ارشاد ہے۔
( إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ) ۔(۲)
یقینا ہم نے نچلے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی۔
ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آسمان اول پر ہیں اس کے علاوہ چھ آسمان اور بھی موجود ہیں ان کے متعلق ہمیں زیادہ علم نہیں ہے اور مزیدیہ کہ جب خود خدا کہہ رہا ہے کہ آسمان سات ہیں تو ہم اس کا نکار کریں زیادہ سے زیادہ یہی کہیں کہ ہم ان سات آسمانوں کی شکل اور کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔
جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ کا ارشاد ہے۔( اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ) ۔(۳)
اللہ وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔
__________________
فصلت :۱۲۔۰۰۰۰صافات :۶۔۰۰۰۰سورہ طلاق :۱۲۔۰۰۰
علم مطلق خداوند
اس سورہ کی بیسویں آیت خداوند متعال کی قدرت مطلقہ پر دلالت کرتی ہے قدرت خدا کا تزکرہ اس کے ضمن میں ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس سورہ میں خداوند متعال کے علم مطلق کے متعلق تذکرہ نہیں ہوا۔
یہ پہلا مقام ہے جہاں اس صفت کو بیان کیا جا رہا ہے۔قرٓن مجید نے خداوندعالم کو ”عالم“ ”علیم“ اور علام سے یاد کیا ہے اگر یہ تینوں کلمے اللہ تعالی کے وصف علم کو بیان کر رہے ہیں لیکن علیم اور علام کسی اور خصوصیت کو بھی بیان کر رہے ہیں جو کلمہ عالم میں نہیں ہے۔کلمہ علیم علام کی طرح مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا کا علم تمام جوانب،اشیاء،اشخاص اور مخلوقات پر محیط ہے۔کسی چیز کا خالق اس کے متعلق مکمل علم رکھتا ہے اور اللہ اس پوری کائنات کی ہر ہر چیز کا خالق ہے لہذا معلوم ہو گا کہ اللہ تعالی کا ئنات کے ذرے ذرے کا علیم اور جاننے والا ہے۔
( وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لاَتَعْلَمُونَ )
اوراے رسول !(اسوقت کو یاد کرو) جب تمھارے پرور دگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا نے والا ہوں تو انہوں نے کہا۔کیا اسے بنا ئے گا جو زمیں میں فساد اورخونریزی کرے جبکہ ہم تیری تسبیح اورتقدیس کرتے ہیں۔تو ارشاد ہوا میں وہ جانتاہوں جو تم نہیں جانتے۔
نعمت خلافت۔
گزشتہ آیات میں خدا وندعالم سے خلقت انسان کے مقصد اورھدف کو بیان کیاتھااب اس آیت میں اس ھدف اور مقصد تک پہنچنے کیلئے راہ اور راہنماکو بیان کررہاہے کیونکہ جس چیز کا آغاز اور انجام ہوتاہے اس کیلئے راہ اور راہنما کا ہونا ضروری ہے۔اسی لئے اللہ تبارک وتعالیٰ ایک آیت میں اپنی بہترین نعمت ” خلافت “ کا تذکرہ فرمارہے۔
خداوند متعال کی خواہش یہ تھی کہ وہ روئے زمین پر اپنا جانشین اور خلیفہ مقررکرتے اوراسکی تمام صفات صفات خداوندی کا پر تر ہوسکا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلاتر ہو ‘پوری کائنات کی تمام نعمتیں ‘سب خزانے ‘غرض ہر چیز اس کے سپرد ہو۔اورایسے شخص کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ عقل ‘ شعور ‘ادراک اور خصوصی استعداد کا حامل ہو اوران چیزوں کی بدولت موجودات ارضی کی رہبری اور پیشوائی کا منصب سنبھال سکے۔
اس وقت خداوند عالم ملائکہ سے انسان کا تعارف کروارہاہے۔یہاں یہ سوال پیداہوتاہے کہ خداوندعالم نے فرشتوں کو اس تدبیر الہی سے کیوں آگاہ کیااور یہ کیوں کہاکہ میں زمین میں اپنا جانشین اورخلیفہ مقررکرنے والاہوں۔
اس حوالہ سے مفسرین نے کئی وجوحات بیان کی ہیں۔بہرحال اسکا ایک مقصد یہ ہوسکتاہے کہ خدا انسان کی عظمت کو بیان کرے اوراسے خلیفہ الہی کے لقب سے ملقب کرے اور بتائے کہ یہ احسن تقویم کا مصداق مخلوق ہے اس وجہ سے خدا وند متعال اپنے آپ کو تبریک پیش کرتے ہوئے بتارہاہے کہ خدابارک اللہ یعنی کتنی بابرکت ذات ہے جس نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا۔شاید ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے فرشتوں اورانسانوں کے درمیان ایک خاص رابطہ اور تعلق برقرار رہے گا۔فرشتے ہی اس کے عظیم رسولوں کے پاس وحی اوراللہ کا پیغام لانے والے ہوں گے یعنی یہ انبیاء الہی کے پاس اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تاکہ انبیاء وحی الہی کو لوگوں تک پہنچائیں۔
بہرحال خداوند متعال نے انسان کو جو منصب خلافت عنایت فرمایاہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خداکسی کا محتاج ہے اوراسے اپنا جانشین اور نائب بنا رہاہے تاکہ اسکے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچاسکے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ قدرت نہیں رکھتاکہ وہ فیعض وبرکات الہی درک کرسکے۔یہ کام فقط خاصان خدا کا ہے اسی لئے تو فرمادیا۔
( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ )
جس نے (میرے ) رسول کی اطاعت کی اس نے (مجھ) اللہ کی اطاعت کی۔
حقیقی خلیفہ کون؟
قرآن مجید کی اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہورہاہے کہ خداوند عالم نے قرمایا‘ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والاہوں‘کہ حقیقی خلیفہ وہی ہے جیسے خود خدابنائے اس کا معیارتقوی اور تقدس کیساتھ علم اسماء کو قرار دیاہے۔
خد انے ملائکہ کو بھی تعلیم دی تھی جسکا انہوں نے اقرار بھی کیاتھا لیکن وہ اسے شنوصیات پر منطبق نہ کرسکے بہرحال خلیفہ اللہ صاحب کردار اوراعلم کائنا ت ہوتاہے۔حقیقی خلیفہ کی معرفت کے لئے ہم اس روایت کو بیان کرتے ہیں جس میں حضرت عمر نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے جناب سلمان ‘ حباب طلحہ‘ جناب زبیر ‘ اور کعب الاجبار سے سوال کیا کہ کیاتم لوگ جانتے ہو کہ حقیقی خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے طلحہ اور زبیر نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن حضرت سلمان نے کہا میں ان کے درمیان فرق کوجانتاہوں۔وہ فرق یہ ہے۔
الخلیفه هوالذی یعدل بالاعیه ‘ ویقسم ‘ باسویه ویشفق علیهم شغقه الرجل علی اهله و یقضی لکتاب الله
یعنی خلیفہ وہ ہوتاہے جو اپنی رعیت کیساتھ عدل وانصاف کرے انہیں برابر برابر حقوق اوراپنی رعیت پر اسقدا مہربان ہو جتنا اپنے اہل خانہ پر مہربان ہے اسکا ہر قیصلہ قرآن کے مطابق ہوتاہے۔
اور وہ اللہ کے اور اولاامر نواہی کو کسی کمی اورزیادتی کے بغیر اسی طرح بیان کرتاہے جستطرح وہ نازل ہوئے ہیں۔اور بادشاہ اسکے علاوہ ہے۔
یہ سنتے ہی کعب الاجبار نے کہا سلمان تم نے کتنی اچھی بات کہی ہے ‘ مجھے بھی خلیفہ کے معنیٰ کا علم نہ تھا اور میرے علاوہ یہ بھی اس کے معنیٰ سے آگاہ نہ تھے۔سلمان تم علم وحکمت سے کتنے بسریز ہو۔(۱)
بہر حال اللہ اوراسکے خلیفے کے درمیان قرب معنوی پایاجاتاہے اسی وجہ سے خلیفہ کیلئے ضروری ہے خلیفہ الہی مظہرالعجائب اور مظہر الغرائب ہونا چاہیے۔اسے جسمانی ‘ روحانی اور تمام جامع حقائق صفات میں پوری کائنات سے افضل ہونا چاہیے۔
_____________________
(۱) منھبح الصادقین جلد۔۱۔ص ۲۲۰۔۲۲۱
چار خلفاء
اکثر مفسرین نے اس آیت اکے ضمن میں قرآن مجید میں چار ایسی ہستیوں کا ذکر کیاہے جنمیں خدا نے خلیفہ بنایاہے۔
البتہ بعض کتب میں چار کے بجائے تین خلفاء کا تذکرہ ہے جیسا کہ حافظ جسکانی نے شواہد تنزیل میں تین خلفاء خدا کا تذکرہ کیاہے اس نے عبداللہ بن مسعود سے روایت بیان کرتے ہوئے ذکر کیاہے کہ قرآن مجید میں تین افراد کو اللہ تعالی ٰ کی خلافت نصیب ہوئی ہے سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم ہے۔ان کیلئے خدا نے فرمایا۔
( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ )
بقرہ : ۳۰
دوسرے خلیفہ حضرت داؤد میں جن کے لئے اللہ تعالی ٰ نے فرمایا۔
( يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ )
اور تیسرے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ اسلام ہیں ان کیلئے خدا وندعالم نے ارشاد فرمایا۔
جیسا کہ حضرت امام رضا اپنے اباؤاجداد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا!
ایک مرتبہ میں مدینہ کے راستوں پررسول خدا کا ہمسفرتھا۔اس وقت ہماری ایک خوبصورت بڑی داڑھی والے شخص سے ملاقات ہوئی اس نے حضرت رسول خد ا کو سلام کیا اور پھر میری طرف متوجہ ہوکر ارشاد فرمایا۔
السلام علیکم یارابع الخلفاء
اے چوتھے خلیفہ آپ پر سلام ہو۔
اس کے بعد اس نے حضرت کو مخاطب کر کے فرمایایا رسول جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح ہے۔
حضرت نے فرمایاجی ہاں !پھر وہ شخص چلاگیا۔
حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول خد ا کی بارگاہ میں عرض کی۔
یارسول اللہ یہ کیاہے ! اس بزرگ نے جو کچھ کہاہے آپ نے اسکی تصدیق بھی کی ہے؟
حضرت نے فرمایا!یہ بالکل حقیقت ہے۔
اللہ تبارک تعالی ٰ نے انی جاعل فی الارض سے خلیفہ سے حضرت آدم کو پہلا خلیفہ بنایا
( لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .) ۔ شوری: ۵۵
یعنی حضرت آدم حضرت داؤد جس طرح خلیفہ تھے اس طرح یاعلی آپ اس زمین میں میرے خلیفہ ہو۔
شواھد التنزیل۔ج ۱ ۔ص ۷۵ ۔ ۷۶
اورفرمایا
( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ )
سے داؤد کے خلیفہ خد اہونے کا اعلان کیا۔
اور حضرت موسی ٰ نے جب حضرت ہارون کیلئے جب یہ کہا‘اخلفنی می قومی واصلح اس سے حضرت ہارون کی خلافت کا اعلان کیا
اوراللہ تعالی ٰ کا یہ فرمان ‘اذان من الله ورسوله الی النساس یوم الحج الکبیر ‘ آپ کے لئے کہا آپ اللہ اوراسکے رسول کے مبلغ میں اورآپ میرے وصی ‘وزیر ‘ میرے دین کے قاضی اور میری امانتیں لوٹانے والے ہیں ‘ آپ کی قدرومنزلت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک ہے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گاآپ چوتھے ہیں جیسا کہ اس بزرگ نے آپ کو سلام کیا۔آپ کو معلوم ہے وہ بزرگ کون تھے۔
حضرت نے فرمایا !لنیس۔
حضرت رسول خدانے فرمایا!وہ تمہارے بھائی حضرت خضر علیہ اسلام تھے۔
عظمت رسول اعظم۔
خداوند متعال اس آیت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس انداز مین بیان فرماتے ہے۔کہ اے رسول جب تمہارے پرودگار نے ملائکہ سے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے ربک فرمایاہے ‘ رب العالمین نہیں کہا۔اس سے بات کی طرف اشارہ فرمارہاہے کہ آپ کااس
خلافت میں اہم حصہ ہے ‘ درحقیقت اس کائنات میں آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اللہ کے سب سے بڑے نائب اور خلیفہ میں اور آپ ہی کی ذات گرامی زمین وآسمان میں امام اقدم کہلوانے کی حقدار ہے۔
اگر خداوندمتعال آپ کو یہ شرف نہ بخشتا تو حضرت آدم کو پیدا ہی نہ فرماتا۔(۱)
بلکہ حضرت آدم کو خدا نے جن اسماء کی تعلیم دی تھی وہ اسماء حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل تھے۔(۲)
___________________
(۱)لایخفی لطف الرب هنا معنا فاالی ضمیر ه (ص) بطریق المظاب وکان فی تنولعه والحروج من عامه الی خاصه رمزاًالی ان المقبل علیه بالخطاب له ‘الخط الاعظم والقسم الاو ضرمن الجملة المجنربها رسول صلی الله علیه (وآله ) وسلم علی الحقیفه الخلیفة الاعظم فی الخلیقة والامام المقدم فی الارض والسموات العلی ولولاة ماخلق آدم روح المعانی جلد۱۔ص۲۱۸۔وفرقان۔ج۱۔ص۲۷۹
(۲) قرقان۔ج۱۔ص۲۸۴
اس آیت میں مزید چار صفات کو بیان کیاجارہاہے دو صفات ایسی ہیں جو خلافت کے منافی ہیں اور دو صفات وہ ہے جنکا کسی خلیفہ میں پایاجانا لازمی اور ضروری ہے سب سے پہلے ہم اس آیت کی ترتیب کے مطابق ان دو صفات کا تذکرہ کرتے ہیں جو خلافت کے منافی ہیں اوران صفات کا حامل خلیفہ الہی کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔
فساد اور خونریزی۔منافی خلافت
ملائکہ خدا کی معصوم مخلوق میں اور انکی عصمت پر قرآن مجید کی یہ آیت دلالت کرتی ہے۔
( وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) ۔(۱)
یعنی جو حکم دیا جائے یہ اسی پر کے مطابق عمل کرتے ہیں۔
حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خداوند عالم نے انسان کی عظمت سے فرشتوں کوآگاہ کیا اورانہیں بتایاکہ میں آدم کو زمین پراپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو فرشتوں نے حقیقت کاادراک کرنے کےئے خدا وند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا۔
پروردگار !کیاتو اسے اپنا جانشین اور خلیفہ قراردے گا جو روئے زمین پر فساد پھیلائے گااورخون ریزی کرتے گا؟
اس مقام پر مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں کہ فرستوں کو کستطرح معلوم ہواکہ یہ مخلوق زمین پر فساد اور کون ریزی کی مرتکب ہوگئی؟
____________________
(۱) ۱۶۔۵۰
بعداز مفسرین کے نزدیک خدانے خود فرشتوں کو آئیندہ کے حالات سے بطور اجمال آگاہ کیاتھا۔بعض کے نزدیک ”فی الارض “ کی لفظ سے ملائکہ خودہی سمجھ گئے تھے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مادہ ہونے کی وجہ سے نزاع اورتزاھم کا احتمال ہے۔بعض کے نزدیک حضرت آدم سے پہلے بھی روئے زمین پر اور مخلوقات بستی تھیں ان میں نزاع۔جھگڑا‘ فساد اور کون ریزی پائی جاتی تھی اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مخلوق بھی فساد اور خونریزی کا شیکار رہے گئی۔
بہرحال ان تین وجوہات میں سے جو وجہ بھی ہوفرشتے اتنا ضرور جانتے تھے کہ تمام شر‘ فساد اور خون ریزی ہے خواہ یہ انفرادی حدتک ہو یا اجتماعی حدتک ہو۔اور یہ بھی جاتنے تھے کہ ان صفات کا حامل شخص خلیفہ الہی کہلوانے کا حقدار نہیں ہے کیونکہ ایساشخص جو غضبی اور شھوی قوتوں سے مرکب ہے۔
ان کے درمیان مزاحمتیں زیادہ ہیں ان کے انتظامت فساد پر مبنی ہیں ارحتمی طور پر اسکی زندگی کے نوعی اورشخصی جینے اسکو کمال تک نہیں پہنچنے دیں گے اوراسکی پوری زندگی فساد اورخوں ریزی کے علاوہ کچھ نہ ہوگی اس وجہ سے یہ مخلوق لائق خلافت نہیں ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے جو شخص بھی فرشتوں کے اس تجزیہ اورتحلیل کے موافق ہوگاوہ خلافت الہی جیسے منصب کے قابل نہیں ہے لہذا کہاجاسکتاہے کہ فساد اورخون ریزی ایسی صفات میں جنھیں خدا کے جانشین میں موجود نہیں ہونا چاہیں بلکہ یہ صفات خلافت کے منافی اور مخالف ہیں۔
تقدیس اور تسبیح۔لازمہ خلافت
فرشتوں نے جب یہ کہا کہ خدایا ہم تیر ی تسبیح اور تقدیس تقرب الہی کا وسیلہ ہیں اور یہ دونوں صفات کا حامل شخص ہی خلیفہ الہی کی منزل تک پہنچ سکتاہے۔
اسی وجہ سے تو ملائکہ خدا کے حضور عرض کررہے ہے پروردگار ہم تمام قسموں اور تقدیس بیان کرنے والوں کی طرح تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاک وپاکیزہ حمد وثنا ہمارا وطیرہ ہے اور تیری حمد وثنا کا نتیجہ ہے کہ ہم زندہ اور قائم ہیں ہم ہر وقت تیر ذکر کرتے تیری بزرگی کا ورد کرتے رہتے ہیں شرک ‘ نقص اور عیب جیسے گناہوں کا ارتکاب ہم سے ناممکن ہے یعنی تو کیا معصیت کاروں کو خلیفہ بنائے گا جبکہ ہم معصوم اور تمام گناہوں سے پاک ہیں۔
یعنی فرشتے سمجھتے تھے کہ اگر مقصد عبوریت اور بندگی ہے تو ہم ہمیشہ عبادت میں ڈوبے رہتے ہیں لیکن وہ اس سے بے خبر تھے کہ انسان کے اندر تین قوتیں ہیں اورانکی زندگی کادارومدار انہیں تین قوتوں پر ہے انسان کے وجود میں سہوت ‘ غضب اور قسم قسم کی خواہشات موجود ہیں ہر وقت انہیں یہ خواہشات گھیرے رکھتی ہیں ان کی وجہ سے انسان فساد اور خون ریزی کرتاہے۔اوراسے تیری قوت عقلیہ بھی ملی ہے اسکی وجہ سے وہ ان خواہشات اور شہوات پر کٹرول حاصل کرے معرفت اوراطاعت الہی کے اعلی ٰ درجے پر فائیز ہوجاتے ہیں۔جب انہیں یہ سب کچھ معلوم نہ تھا اسی وجہ سے انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی کہ تسبیح وتقدیس وعصمت جو کہ خلافت کا لازمہ ہے ‘ہم میں موجود ہے تو ہمیں ہی خلیفہ بنا دے۔
لیکن انہیں کب معلوم تھا کہ اس آدم علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد ‘ابراھیم ‘نوح ‘موسیٰ ‘اورعیسی ٰ سے اولوالعزم انبیاء اورائمہ اطھار جیسے مصعوم امام اورصالح بندے اس دنیا میں تشریف لائیں گے یہ تو ایسے افراد ہیں جن کی ایک لمحے کی غور وفکر فرشتوں کی سالھا سال کے عبادت کے برابر ہے۔
شاید اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہاتھا
فرشتوں سے بہترہے انسان بننا
مگراس میں پڑتی ہے محنت زیادہ
فرشتوں نے فساد کو منظر رکھا لیکن وہ اس طرح متوجہ نہ ہوئے کہ ان کے پاس عقل جیسی قوت موجود ہے اسے بروئے کار لاکر عدل وانصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ عدالت اجتماعی پرپورا اثر رکھتے ہیں اپنے نفس اورخواہشات پر کنڑول حاصل کرکے اخلاق حسنہ اورصفات پسندیدہ کے حامل ہوسکتے ہیں۔
لامحدود علم الہی۔
ملائکہ کا علم محدود تھا جس کی وجہ سے وہ انسانی کمال سے آگاہ نہ تھے وہ اس سے بھی آگاہ نہ تھے کہ انسان کس استعداد کا مالک ہے انسان میں توانائی پائی جاتی ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے کی صلاحیت رکھتاہے ‘غیبی حقائق دریافت کرنا ان کے بس میں ہے جبکہ ان کے مقابلے میں فرشتے بے بس ہیں۔
حضرت امام صادق ارشاد فرماتے ہیں:
جب فرشتوں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی ہمیں زمین پر خلیفہ بنایاجائے کیونکہ ہم تیری تسبیح ‘ تقدیس اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں کبھی بھی تیری معصیت نہ کرتے ہیں جبکہ ہمارے علاوہ جیسے تواپنا خلیفہ بنائے گا وہ عصیان کا مرتکب ہونگے توخدا وند عالم نے انہیں جواب دیا۔
( إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )
میں وہ جانتاہوں جوتم نہیں جانتے۔
اس سے ملائکہ کو علم ہوگیا کہ وہ اس بافضیلت مخلوق کے رتبے سے واقعف نہیں ہیں لہذا وہ اپنے سوال پرشرمندہ ہوئے اور عرش الہی میں پنا ہ لی اوراستغفار وتوبہ میں مشغول ہوگئے۔
جب حضرت آدم عدم سے وجود میں قدم رکھتے ہیں تو جنت ان کا مسکن بنا انواع اقسام کے میوے مقدر بنے اور جب ترک اولی ہوا جنت سے زمین پر آئے اللہ کاخطاب ہوا۔آدم زمین پر ایساگھر تیارکروجس میں تیری ذریت کے خطار لوگ پناہ حاصل کریں اوراستغفارکریں اورخود کو خطا اورعصیان سے پاک کریں۔۔۔
جب گھر مکمل ہوا تو گناہ ھگار لوگ برھنہ سر ‘ ننگے پاؤں ‘ اورپریشان بالوں اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے اورتفریح وزاری اور نالہ بیقراری ہوئے ان کی توبہ واستغفار سے رحمت خدا انکے شامل حال ہوئی اس وقت خداوند متعال نے فرشتوں سے خطاب کیا۔
دیکھو آدم کی خلقت میں یہ حکمت ومصلحت ہے۔۔۔اس کی وجہ سے میں نے اسے اپنا جانشین بنایاہے اورپوری کائنات میں وہ اللہ کا خلیفہ قرارپایا۔(۱)
بہر حال( إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) سے اللہ تعالی کے لامحدودعلم کی طرف اشارہ ملتاہے کہ وہ لامحدود علم کا مالک ہے اورجیسے جتناچاہتاہے اپنے علم سے تواز تاہے اسی لیئے جب فرشتوں نے یہ سنا کہ جو میں جانتاہوں وہ تم نہیں جانتے ‘ فوراًخاموش ہوگئے انہیں یقین ہوگیاکہ خلیفہ الہی کے متعلق ہماراگمان اورخیال درست نہیں ہے۔
____________________
منبھح الصادقین۔جلد ۱ ۔ص ۲۲۴
( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلاَئِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَء إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ )
اور (خدانے ) آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کیااورفرمایااگر اپنے دعوے میں (کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ) سچے ہوتوان چیزوں کے نام بتاؤ۔
علم آدم :
خداوندمتعال کی ایک بہت بڑی نعمت علم ودانش ہے اس نعمت کی وجہ سے انسان کو پوری کائنات پربرتری حاصل ہے اورعلم انسان کو فرشتوں اوردوسری مخلوقات سے ممتاز بناتاہے اوریہ ایسی صفت ہے جسکا تسبیح وتقدیس کی طرح خلیفہ الہی میں پایاجانا لازمی ہے یعنی خلیفہ اللہ کہلانے والی ہستی کیلئے اعلم ترین ہونا ضروری ہے۔خدا نے کامل انسان کو اپنے لطف وکرم سے حقائق عالم کے ادراک کی استعداد ‘ صفات کمال تک پہنچنے کی طاقت عطا فرمائی ہے اوراس نے آثار اورآیات الہی کے کیساتھ ‘ خدااورکمال الہی کی معرفتاورشناخت حاصل کی اورعبادت اورخودسازی سے کمال حاصل کر جب یہ کمال اپنے درجہ اتم پر پہنچاہے توانسان عالم کہلایااوراس چیز کا حقدار بناکہ اسے خلافت الہی سونپ دی جائے۔
مندرجہ بلاآیت بھی انسان کے علم کو بیان کررہی ہے کہ خدانے اپنے خلیفہ کو اسماء کی تعلیم دی اوراس علم کی وجہ سے اسے فرشتوں پر برتری نصیب ہوئی۔مفسرین نے علم اسماء کی تفسیر میں کافی چیزیں بیان کی ہیں اورمختلف انداز میں اس کی تفسیر کی ہے۔ان سب تفسیروں کو بنیادی طور پر تین نظروں میں تقسیم کیا جاسکتاہے۔
اس سے مراد خارج میں موجود اشیاء کے نام ہیں یعنی کائنات کی ہر بڑی چھوٹی چیز جودین ودنیا کے ساتھ مربوط ہوسکتی ہے اس کے نام آدم کو تعلیم کئے گئے۔دوسرانظریہ یہ ہے کہ خداوندمتعال نے حضرت آدم کو اشیاء کے خواص ‘ آثار اور معانی سے آگاہ کیاہے مثلاًفرض کریں خدانے کسی جانورکو خلق کیا ہے تواس کی خلقت کے فلسفے کو آدم سے بیان کیاہے اوراس فلسفے کی تعلیم دی ہے۔تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ان اسماء سے مراد اسراد آفریتش میں اورخزائن خداہیں۔
جہاں تک پہلے معنی ٰ کا تعلق ہے کہ اس سے مراد ہر جادات ونیابات وغیر ہ کے نام ہیں یعنی یہ فرہنگ لغت ‘ کا علم ہے اوریہ علم کوئی ایسی بلند فضیلت چیز نہیں ہے جیسے ملائکہ کے مقالبے میں شرف وبزرگی کا معیار قرار دیاجاسکے اسی طرح اسکا دوسرا معنیٰ اور نظریہ بھی نامناسب ہے کیونکہ یہ اسماء کے عزمی مفہوم سے خارج ہے کیونکہ الفاظ توان عربی مفاھیم پرآتے ہیں ان معانی پرنہیں آتے جو عقلی تو جیہات کی وجہ سے کھینچ تان کرقراردیئے گئے ہوں۔(۱)
علم آدم اورخزائن غیب:
حضرت آدم کو جن اسماء کی تعلیم دی گئی تھی وہ نہ توالفاظ تھے اور نہ ہی مفاھیم تھے کیونکہ اسماء کیلئے جمع مزکر سالم کی ضمیر لانااس بات کی علامت ہے کہ حقائق خارجیہ تھے‘ مفاھیم زحینہ نہ تھے اللہ کی تمام آیات اورنشانیوں کی تعلیم لازمی ہوتی ہے یعنی متعلم اور معلم کے درمیان کسی قسم کاکوئی واسطہ نہیں ہے۔
بہرحال جن اسماء کی اللہ تعالی ٰ نے حضرت آدم کو تعلیم دی تھی خزائن غیب میں جسکی خدا نے انسان کامل کو تعلیم دی ہے لہذا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسکا تعلق اوررشتہ اصلی وہی مخزن ہے اورجو خلیفہ الہی ہے وہ اس رشید سے باخبر ہے۔
____________________
(۱) فصل الخطاب۔جلد۱۔ص۹۸۔المیزان۔جلد۱۔ص۲۳۳
حضرت امیرالمئومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں !
والله لوشسئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه ومولجه وجمیع شابه لفعلت ولکتی اخاف ان تکفروافِی برسول الله ۔(۱)
مجھے خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو آپ میں سے ہرشخص کی جداجدا آئیندہ اورگزشتہ زمانوں کی شرگزشت ‘ اورسرنوشت بیان کرنا چاہوں توبیان کرسکتاہوں لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جب تم مجھ سے یہ اخبارغیب سنکر کفر اختیار نہ کرلواور یہ یقین سے کہنا شروع کردو(معاذاللہ ) علی ‘ رسول خداسے بالاترہیں۔
اس کے بعدارشادفرماتے ہیں۔
الاوانی مفضید الی انی صه ممن یومن ذلک منه
البتہ میں ان خاص اسراروں کو اپنے اولیاء خاص جوکہ امین میں سپرد کرتاہوں۔
بہرحال اس کائنات اورجہاں میں جوچیزیں بھی ظاہر ہیں ان کارشیتہ عتد اللہ ہے اورکائنات میں کیسی ایسی چیز کا وجود نہیں ہے جیسے خلیفہ اللہ ‘ولی ا لقدر اورانسان کامل نہ جانتاہو۔(۲) اسی علم کی وجہ سے حضرت آدم خلیفہ الہی قرار پانے کے حقدار ٹھہرے اورانہیں فرشتوں پر برتری اورفضیلت ملی۔
___________________
(۱) تسبیح وخطبہ۔۱۷۵
(۲) تفسیر قرآن جوادی آملی جلد۶۔ص۱۹۶
فضیلت آدم۔
جب خدا وندعالم نے حضرت آدم کی تمام فرشتوں اورکائنات پرفضیلت بیان کرنا چاہی تواس نے حکم دیاکہ آسمان پرنور کا منبر لگایاجائے اس کے اوپر نورانی کرسی رکھی جائے اور تمام فرشتے اس منبر کے قریب حاضر ہوجائیں جب سب حاضر ہوگئے توحضرت آدم کو حکم دیاگیاکہ منبر پرتشریف لے جائیں وہاں مسلحات کو پیش کیاگیا۔(یعنی جن کے نام تھے ان کو پیش کیاگیااورکہاگیاکہ ان کے نام بتاؤ)(۱)
یہاں انسیلونی باسماء ھولادہے یعنی مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ یہ نہیں کہاگیاانسبئون مھذہ الاسماء (مجھے یہ نام بتاؤ ) اس سے واضح ہوجاتاہے کہ پیش کئے جانے والے اسماء نہیں تھے بلکہ اصحاب اسماء تھے اوراس سے مراد صاحب عقل ھستیاں ہیں اوریہ وہی ہستیاں ہیں جنکا تعارف اور جنکی پاک سیرت کوظاہر کرنے والے خط وخال ہی ملائکہ کو بشری عظمت کااحساس
دلائیں اوراللہ تبارک وتعالیٰ خلافت کے لئے جوان ہستیوں کاانتخاب کیاہے یہ فرشتوں کے سوال کا مکمل جواب بن جائے۔
بہرحال ایک سوال باقی ہے کہ ان ہستیوں اورمسحمات کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کی کیاضرورت تھی۔اس سلسلے میں مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیئے ہیں۔ان میں اہم ترین تین قول ہیں۔
بعض مفسرین کاخیال ہے کہ خداوندمتعالنے ابتداًتمامموجودات کو خلق فرمایااس کے بعدفرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیاگیااوران سے کہاگیاکہ ان کے اسماء بتاؤ۔
____________________
(۱) مبتھح الصادقین۔جلد ۱۔ص۲۲۷
بعض مفسرین کا خیال ہے خدانے اپناارادہ تکوینی فرشتوں کے دل میں ڈالااورانہوں نے خداکے ارادہ تکوینی سے تمام موجودات کامشاہدہ کیایعنی خدانے چاہاکہ فرشتے موجودات کا مشاہدہ کریں فوراًانہوں نے مشاہدہ کیااوراپنے لاعلمی کااعلان کردیا۔
بعض مفسرین کاخیال ہے کہاس سے صرارروح ہے اورفرشتوں کا عالم ارواح جیسے عالم انوار بھی لکھتے ہیں میں امتحان دیا اورانہوں نے انسان کامل کے مقابلے میں لاعلم ہونے کا اعتراف کرلیا اورحضرت آدم کی فضیلت اور برتری کو تسلیم کرلیا۔
کیافرشتے سچے نہیں؟
خداوندمتعال نے اس آیت میں کہاہے کہ اگر تم سچے ہوتوان مسمیات کے نام بتاؤ اوروہ نام نہ بتاسکے اس سے ظاہرہوتاہے کہ فرشتے (نعوذباللہ) کسی نہ کسی لحاظ سے سچائی کے معیار سے الگ ضرورہیں اوریہ ملائکہ کی عصمت کے خلاف ہے۔اس کے جواب میں اتنا کہناکافی ہے کہ صدق کا وہ مفہوم جسکی وجہ سے اس کو کذب کے مقابل اورمتضاد سمجھا جاتاہے یہ لفظی اصطلا ہے اس لحاظ سے فرشتوں کوصرف صادق ہی کہاجاسکتاہے کیونکہ صدق اورکزب کا احتمال خبر میں ہوتاہے انشاء میں نہیں ہوتا‘ انساء میں صدق ہماصدق ہوتاہے اورفرشتوں نے اس سے پہلے جو کہاہے
أتجعل فیها ۔۔۔
(کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنانے والاہے۔)
یہ جملہ ستفھامیہ ہے اس میں صدق وکذب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا مانناپڑے گاکہ یہ ان کی عصمت کے خلاف نہیں ہے۔اورخداوندمتعال کلام مخاطب کیساتھ کہتاکہ اگر تم سچے ہوتوان کینام بتاؤ یہ تسبنیہ اورتسبکیت کے عنوان سے ہے۔یایہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے دل میں یہ خیال لاتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے اورہم سب سے افضل وبرتر ہیں۔(۱)
____________________
(۱) انهم قالوافی انفسهم ماکنانطن ان تحلق الله خلقا اکرم علیه منانحن خوان الله وجیرانه واقرب الخلق الیهتفسیر عیاشی
یہ خیال گناہ نہیں کہ وہ سزا کے مستحق ٹہریں اورانکی عصمت کے خلاف ہو بلکہ یہ خیال ان کے نقص علم کی وجہ سے ہے جسکا ادراک انہیں امتحان کے بعد ہوگیا کہ ہم اس منصب کے اصل نہیں ہیں لہذا چونکہ ان کے ذہن میں آنے والی بات صادق نہ تھی اس لیئے امتحان کے وقت کہاگیا تھا کہ اگر سچے ہوتو تام بتاؤ لہذا فرشتوں کی عصمت پرکسی قسم کاکوئی حرف نہیں ہے اوروہ سچے اور معصوم ہیں۔
( قَالُوا سُبْحَانَکَ لاَعِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ )
ملائکہ نے عرض کی تو ہر برائی اورعیب سے پاک ہے ہم تو وہی جانتے ہیں جسکا تونے ہمیں علم دیاہے۔یقیناتوبڑا جاننے والا اور مصلحتوں کو پہچاننے والاہے۔
خاصان خدا کا انداز گفتگو:
یہ فرشتوں کا خاصہ ہے کہ جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں اسکی اتبداء تسبیح خداوندقدوس سے کرتے ہیں اوراس کی انتہاتقدیس پرکرتے ہیں اوراس کے درمیان آپنی بات بیان کرتے ہیں مثلاًاسی زیر نظرآیت میں خداوندمتعال سے اس طرح گویاہے خداتوہر برائی اورعیب سے پاک ہے اورآخر میں تقدیس‘تنزیہ اورتحمیدبیان کرتے ہے کہ توہی دانا وحکیم ہے اور تسبیح وتقدیس کے درمیان نہایت مودبانہ انداز میں عرض کررہے ہے کہ ہم توکچھ بھی نہیں جانتے ہمیں توصرف اس چیزکاعلم ہے جوتو نے ہمیں تعلیم دی ہے۔
البتہ یہ صرف فرشتوں کاخاصہ نہیں ہے بلکہ انبیاء علیھم اسلام بھی اس طرح مودبانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں مثلاًحضرت موسیٰ حکیم اللہ جب اللہ سے بات کرناچاہتے تو پہلے تسبیح وتقدیس کرتے پھر اپنی بات بیان کرتے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔
( سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ) ۔(۱)
توپاک وپاکیزہ ہے اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتاہوں۔
اورحضرت یونس اس انداز میں خد اسے تکلم فرماتے ہوئے نطر آتے ہیں۔
( لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ ) ۔(۲)
پروردگار !تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے توپاک وبے نیاز ہے۔اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔
انسان اورفرشتے میں فرق
انسان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ایسی ہے جو پوری کائنات میں کسی مخلوق خدا کے حصے میں نہیں آئی۔اوروہ خصوصیت یہ ہے اس میں اختیاری طور پر عملی اورعلمی ترقی کی لامحدود صلاحیت پائی جاتی ہے انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات خواہ وہ مجادات نباتات ہوں یاوہ صفائے جوھر کی بلندوبالا مخلوق فرشتے ہوں‘انہیں جوکچھ خدانے اعطاکیاہے وہ سب کے سب کمالات اتنے ہی رکھتے ہیں جتنے انہیں عطاہوتے ہیں ان عطایائے الہی کو اپنی قابلیت سے مذید بڑھانے کی طاقت یاتوان میں بالکل ہی نہیں ہے یاپھر اگر ہے توانتہائیانتہائی محدودحدتک ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے امتحان لیاتو یہ امتحان بھی حافظ اور یاداشت کاامتحان نہ تھا‘اگر حافظ کا امتحان ہوتاتو فرشتے شکست نہ کھاتے بلکہ سب کچھ بتادیتے کیونکہ فرشتے سہووسنیان سے بلاتر مخلوق ہے یہ اپنی یاداشت میں نہ سبعر کرتے ہیں اورنہ انہیں کوئی چیز بھول جاتی ہے۔
____________________
(۱)اعراف :۱۴۳
(۲) انبیاء :۸۷
لیکن یہاں امتحان حافظے کا نہیں تھابلکہ یہ ذحانت کا امتحان تھا‘انہیں اسماء کی تعلیم دی گئی تھی اوران کے سامنے مسحیات کو پیش کیاگیاکہ ان کے ناموں کی تطبیق کرتیں ‘لہذا یہ عقل وفراست کاامتحان تھااوراس چیز کا سوال تھاجوانکو بتائی جانے والی حدود سے باہر تھا۔لہذا فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں اپنی کم علمی اور انکساری کااعتراف کرتے ہوئے عرض کیا۔
پروردگار ! جو کچھ تونے سکھایاہے ہم توفقط اسے ہی جانتے ہیں جبکہ اسماء کے حقائق اور معارف ہمیں نہیں سیکھائے گئے لہذا اسے ہم نہیں جانتے تو جب بھی کسی کو کسی چیز کی تعلیم دیتاہے تو وہ تیرے علم وحکمت اورمصلحت کے مطابق ہوتی ہے ہم مقام خلافت کے لائق نہ تھے لہذا تو نے ہمیں اسکی تعلیم نہ دی۔
( قَالَ یَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنتُمْ تَکْتُمُونَ )
(اللہ) نے فرمایاہے اے آدم انہیں ان موجودات کے اسماء (واسراء ) سے آگاہ کرو جب اس نے انہیں آگاہ کیاتو(خدا) نے فرمایا۔کیا میں نے کہاتھاکہ میں زمین وآسمان کے غیب کو جاتاہوں اور جوکچھ تمہارے ظاھرو باطن میں ہے اس سے واقف ہوں۔
علم معیار خلافت:
گزشتہ آیات میں جب ملائکہ نے انسان کی ظاہری خلقت اور پہلے سے زمین پررہنے والی مخلوق کے حالات کا مشاھدہ کیاتھا تواللہ تعالیٰ سے سوال کیاتھاکہ آدم کس طرح خلیفہ بن سکتے ہیں یہ تو زمین پرفساد اورخون ریزی کریگاجبکہ ہم تیری تسبیح وتقدس کرتے ہیں کیاہم اس سے افضل نہیں؟ اس آیت میں خداوندعالم جواب دینے کیلئے حضرت آدم کے علم ‘باطنی استعداد اورلیاقت کو بیان فرمارہے ہے۔اورگویایہ بتاناچاہتاہے کہ معیار خلافت صرف تسبیح وتقدس نہیں بلکہ اس کے ساتھ علم بھی ضروری ہے۔
جیسا کہ خداوندعالم کاارشاد ہے۔
( إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ ) ۔
اللہ نے اس (طالوت ) کو تمہارے لیئے منتخب کیاہے اوراسکے علم وجسم میں وسعت عطافرمائی۔
یہی معیار حضرت آدم کی خلقت اور اعطاء خلافت میں بھی مدنظر رکھاگیا۔کیونکہ مرحلہ تشریح قانون سازی عالم کل ذات کے ہاتھ میں ہے لہذا مرحلہ عمل میں ضروری ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے جو علم ونہم میں پوری کائنات پر فوقیت رکھتاہو۔
اب اس معیار کو مرصح ظہور کرنے کیلئے حضرت آدم کوحکم دیاجارہا ہے کہ تم ملائکہ کو حقائق ہستی سے آگاہ کرو حضرت آدم نے ان حقائق سے ملائکہ کو آگاہ فرمایااس وقت ملائکہ پر حضرت آدم کی برتری اور فضیلت واضح ہوگی اورمنصب خلافت کا حقدار ہونا بھی روشن ہوگیاکہ خلیفة اللہ وہی ہوسکتاہے جس کے پاس تمام مخلوق کے حقائق کاعلم ہو۔
اب خداوندمتعال فخر سے فرمایارہاہے
( قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) ‘(۲)
کیا میں نے تمہیں نہیں کہاتھاکہ میں زمین وآسمان کے پوشیدہ امور کو جانتاہوں۔
یہ سن کر ملائکہ حکم پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم ہوگئے۔کہ اللہ تبارک وتعالیٰ تمام مغیبات اورمصالح کاعالم اورحکیم ہے۔
اس آیت کہ آخر میں فرمایاجوکچھ تمام ظاہر کرتے اور چھپاتے ہواسے میں جانتاہوں یہاں ملائکہ نے بعض چیزوں کو توظاہر بظاہر بیان کیاتھاکہ حضرت آدم کی اولاد فساد وخون ریزی کرے گی اورحضرت آدم پراپنی برتری کو چھپاتے تھے کہ ہم حضرت آدم سے افضل نہیں لہذاخداکہتاہ ے کہ جوکچھ تم چھپاتے اورظاہر کرتے تھے میں اسے جانتاہوں۔
____________________
(۲) غیب کے بارے میں کہاجاسکتاہے کہ اس سے مراد وہ پوشیدگی ہے جسکو ہماری نسبت دی جاسکتی ہے وگرنہ ذات حق پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے لہذا قرآن مجید میں جس مقام پر غیب کی نسبت خدا کی طرف ہے اس سے یہی مراد ہے جیسے “عالم الغیب والشهاده“
پس واضح ہوگیاتمام اچھے اوصاف میں علم کامرتبہ سب سے بلند ہے اورعلم ہی الہی خلافت کامعیار ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت امیرالمومنین بھی مقام افتخار میں اپنے علم کو پیش فرماتے تھے۔
رضیناقسمة الجبار فینا
لناعلم ولاعدٰء مال
فان المال یغنی عن قریب
وان العلمه یبفیٰ لایترال
ہم اللہ تبارک وتعالیٰ کی اس تقسیم پر بہت راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے نواز ا ‘اور ہمارے دشمنوں کو مال ودولت دیاجبکہ مال توجلدہی ختم اورفنا ہوجائے گااورعلم غیرفانی دولت ہے۔
( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَی وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنْ الْکَافِرِینَ )
جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ‘ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔اس نے نکار اورتکبرکیااور وہ کافروں میں سے تھا۔
مسجود ملائکہ:
جب خداوند متعال نے حضرت آدم کو حقائق ہستی کی تعلیم دی اورحضرت آدم کی ملائکہ پر استعداد واضح ہوگی اورحضرت آدم کو ملائکہ کااستاد بنادیاتوتمام ملائکہ کو خلیفہ الہی کی عزت واکرام کیلئے سجدہ کرنے کاحکم دیا۔ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔(۱)
یہ سجدہ عبادت خداوندی کیلئے تھاکیونکہ قرآن ‘سنت اوراولہ غعلبہ سے ثابت ہے کہ عبادت صرف ذات حق سے مختص ہے اس لئے ملائکہ نے حضرت آدم کو جوسجدہ کیاتھاوہ حضرت آدم کی بندگی اورعبادت نہ تھی فضل وکمال کے اظہار کے لئے تھا اورحضرت آدم کو قبلہ قرار دیاگیاتھااسی لیے ابلیس
نے سجدہ کرنے سے انکار کردیاتھا۔
۱ ۔ اسی طرح حضرت رسول اکر کافرمان بھی ہے۔
لم یکن سجود هم لآدم انما کان آدم قبلة ًلهم یسجدوں نحوة للله عزوجل ۔(۲)
حضرت آدم کو کیے جانے والے سجدہ میں حضرت آدم فرشتوں کیلئے قبلہ بنائے گئے تھے انہوں نے حضرت آدم کی طرف اللہ تبارک وتعالیٰ کیلئے سجدہ کیا۔
۲ ۔جیسے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں۔
لماخلق الله آدم ابان فضله للملائکه واراهم فاخصد به من سابق العلم ومعرفة الاسماء وجعله‘ محراباًوکعبة وباباًوقبلةً ۔۔۔(۱)
ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایاتواس کے فضل وکمال کو ملائکہ پر ظاہر کیا اورحضرت آدم کی سبقت علمی اور معرفت اسماء کی خصوصیت انہیں دکھلائی۔اوراسے محراب اورکعبہ ‘باب اللہ اورقبلہ قراردیا۔
____________________
(۱) قرآن مجید کی اس آیت کے آغاز میں لفظ اذ ہے اسکا تعلق اذکر مقدر کیساتھ ہے۔اس کا مطلب یہ ہے تم اس واقعہ کو ہمیشہ یادرکھو اوراس سے عبرت اورنصیحت حاصل کرو۔الفرقان۔ص۲۹۴:ج۱
(۱) مستدرک ‘ نہج البلاغہ :۳۸(۲) تفسیر البرھان :ص۸۱:جلد ۱
آیاسجدہ عبادت ذاتی ہے؟
ہرسجدہ تذلل ‘خشوع وخضوع اورعبادت شمارنہیں ہوتاکہ اسے ہم عبادت ذاتی قرار دیں۔جن لوگوں کایہ خیال ہے سجدہ ایساعمل ہے جس کے عبادت بننے کے لئے اللہ کے امر اورحکم کی ضرورت نہیں ہے۔یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ عبادت کا معنیٰ یہ ہے‘ عبد اپنے آپ کو مقام عبادت میں قراردے اورصرف اس کام کو بجالائے جو مولیٰ کی طرف سے مقررہو۔اسکا کامعنیٰ یہ کہ فعل عبادع میں ضروری ہیکہ مولاکی مولویت اورعبد کی عبودیت کے اظہار کی صلاحیت پائی جائے۔ اور یہ خصوصیت سجدہ میں منحصر نہیں ہے البتہ سجدہ مولیٰ کی آقائی اورعبد کی عبودیت پر دلالت کرنے والے اعمال میں سب سے واضح عمل ہے اس میں عبد نیاز جبیں کو خاک پر رکھ دیتاہے لیکن پھر بھی یہ ذاتی عبادت نہیں ہے۔اگریہ ذاتی عبادت ہوتاتواللہ تعالیٰ غیراللہ کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتاجیسا کہ اس آیت کے علاوہ ایک مقام پرارشاد وقدرت ہے۔
( وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ) ۔(۱)
یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ حضرت یعقوب ‘انکے بیٹوں اورانکی شریک حیات کے عمل کی حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ فروالہ سجداًکہ وہ سب حضرت یوسف کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ ملائکہ کاحضرت آدم کو سجدہ کرنا بھی خدا کی عبادت تھی اوراس کے حکم کی اطاعت اس میں تھی کہ حضرت آدم کے شرف وکمال کیلئے سجدہ کیاجائے اور حضرت آدم کا یہ شرف وکمال محض انکی وجہ سے نہ تھا بلکہ آپ کے وجود وسعود میں انوار مقدسہ عالیہ کے باعث تھا۔جیسا کہ حضرت رسول اکرم کا فرمان ہے۔
____________________
(۱) یوسف:۱۰۰
ان الله تبارک وتعالیٰ خلق آدم فاودعنا صلبه وامر الملائکة بالسجود نه تعظیماًلنا واکراماًفکان سجود هم الله عزوجل عبودیة ولادم اکراما وطاعیة لکوننافی صلبه ۔(۱)
اللہ تبارک وتعالیٰ نے جب حضرت آدم کو خلق فرمایاتو ہمیں امانت کے طور پر اس کے صلب میں رکھا۔اور ملائکہ کو حکم دیاکہ اسے ہماری تعظیم اوراکرام کیلئے سجدہ کریں لہذا ان کاآدم کو سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کیلئے عبادت کے عنوان سے اورحضرت آدم کے لیئے احترام اوراطاعت کے عنوان سے تھا کیونکہ ہم اسکی صلب میں تھے۔
حقیقت سجدہ:
خداوندمتعال نے اس آیت مبارکہ میں فرشتوں سے حضرت آدم کو قبلہ سمجھ کر سجدہ کاحکم دیاہے اوریہ اللہ کی عبادت ہے اورحضرت آدم اور معصومین کی تعظیم ہے۔یہاں یہ گمان پیدانہ ہوکہ تعظیمی سجدہ جائیز ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ
اولاً:حضرت آدم کو قبلہ سمجھ کر خداکیلئے سجدہ کیاگیاتھا۔
____________________
(۱) نور الثقلین :جلد۱:ص۵۸
ثانیاً:اگر یہ کہیں صرف اورصرف حضرت آدم کیلئے تعظیمی سجدہ تھااوراسے قرار نہیں دیاگیاتھا تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائیز بھی تھاتواسلام نے اسے منسوخ قراردیاہے۔( ۱)
بہرحال غیراللہ کو سجدہ کرناحرام ہے( ۲) اورقرآن مجید کی آیات بھی یہی کہتی ہیں ( ۳) اورروایات میں بھی یہی حکم ہے۔( ۴)
____________________
(ا) جیسا کہ سیوطی اسباب نزول میں یہی کہتاہے کہ اس شریعیت میں یہ منسوخ ہے اور تفسیر لوامع التزیل جلد ۱:ص۱۸۹‘پر بھی تصریح موجود ہے کہ سابقہ شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائیز تھا مگر اسلام میں منسوخ قرار دیاگیاہے۔
(۲)یحرم السجود لعیز الله تعالیٰ من دون فرق بین المعصومین وغیرهم ومایغعله الشیعة فی مشاهد الائمه لابد ان یکون للة شکراتوفیقهم لزیارتهم والحضور فی مشاهد هم ۔منھاج الصالحین امام خوشی :جلد۱:ص۱۷۹
یعنی غیراللہ کو سجدہ کرناحرام ہے خواہ معصومین ہویاان کے علاوہ کوئی اورہو۔البتہ شیعیان حیدرکرار ائمہ اطھار علیھم اسلام کی ضریحوں پر جوسجدہ بجالاتے ہیں وہاللہ تبارک وتعالیٰ کے شکرکیلئے ہیاس نے انہیں ان مبارک ضریحوں پرحاضرہونے اورانکی زیارت کی توفیق عطافرمائی ہے۔
(۳) قرآن مجید کی آیت میں تصریح موجود ہے کہ سجدہ فقط خداتعالیٰ کی ذات کیساتھ مخصوص ہے جیسا کہ ارشاد ربالعزت ہے “ان الذین----له سیجدون :۷:۲۶‘اورلاتسجدوا واسجدوالله :۴۱:۳۷‘اوران المساجد للله ۔۲ ۷ :۸ ۱ (۴) ابوحمزہ مسجدہ کوفہ میں حضرت امام زین العابدین کوسجدہ کرناچاہتاتھاتوحضرت نے فرمایا”ایسانہ کرو سجدہ توفقط اللہ تبارک وتعالیٰ کیلئے ہے‘مفاتح الجنان۔زیارت ہفتم اسی طرح ایک جاثلیق حضرت امیرالمومنین کی شخصیت سے متاثر ہوکر آپ کو سجدہ کرناچاہتاتھاتوحضرت نے ارشادفرمایا‘
اسجدلله ولاتسجدلی اللہ کو سجدہ کرو مجھے سجدہ نہ کرو۔
تفسیر مخزرازی جلد:۲:ص:۲۱۲ اور عمادالاسلام :جلد۱:ص ۳۳۵
حقیقت ابلیس:
ابلیس کا معنی“ رحمت الہی سے مایوس ہونے والا“ ہے سجدہ الہی سے انکارکے باعث رحمت الہی سے مایوس ہواتوشیطان کا نام ابلیس بن گیاجبکہ روایات مطابق اس کانام حارث یاغرازیں تھااوررحمت الہی سے مایوس ہونے کی وجہ سے یہ شیطان کانام ہے اسیلئے اسے ابلیس کہتے ہیں۔ حقیقت ابلیس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف رائے ہے بعض کے خیال کے مطابق یہ ملائکہ میں سے تھااوروہ اس کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ملائکہ سے نہ ہوتاتو ملائکہ کے زمرے میں اسے خطاب نہ کیاجاتااور ملائکہ سے الااستناتیہ کے ذریعے اسکو الگ نہ کیاجاتا۔تواس سے معلوم ہوتاہے کہ ملائکہ کایہ ہم جنس تھا۔
لیکن حق یہ ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہ تھے اس کی دلیل کے لئے قرآن مجید کی آیات اورروایات موجود ہیں۔جیسا کہ خداوندمتعال کافرمان ہے۔
( فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ ) ۔(۱)
تمام ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیایہاں مھکم یہی بتا رہے ہے اس جنس ملائکہ سے ایک فرد بھی ایسا نہ تھاجس نے سجدہ نہ کیاہو۔
اسی طرح ایک اوجگہ ارشاد رب العزت ہے۔
( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ) ۔
____________________
(۱) سورہ حجرایت :۳۰
جب ہم نے ملائکہ سے آدم کے لیے سجدے کا انکار کیا توسب نے سجدہ کیااورابلیس نے نہ کیاوہ جنات میں سے تھااوراس نے اپنے رب کے حکم سے فسق اختیارکیا۔(۲)
بہرحال جن اور ملائکہ دو جداجدا مخلوقات ہیں(۳) لہذا یہ ہم جنس نہیں ہیں۔
یہاں یہ سوال پیداہوتاہے کہ جب یہ ہم جنس نہیں تھے اورآیت مبارکہ میں سجدہ کرنے کاحکم ملائکہ کوہواہے ابلیس کو حکم نہیں ہواتو پھر نافرمانی پراسے راندہ درگاہ الہی اورلعین کیوں قرار دیاگیا؟
نیز عرفی محاورات میں بھی ایسے ہی ہے جب ایک فرد کسی گروہ میں یوں مل گھل جائے کہ علیحدہ شمار نہ ہوتاہو تو جب اس کو خطاب ہوتاہے تو وہ فرد خود اس گروہ کے ضمن میں مخاطب ہوتاہے۔ اورکلام عرب میں موالی قبائل کے بارے میں اکثر ایسی تعبیرات ملتی ہیں۔
اسکا جو اب یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کااجتماع ہے کہ سجدہ کرنے کاحکم ابلیس کو بھی ہواتھا
اور قرآن مجید میں بھی دوسرے مقام پرارشاد قدرت ہے۔
( مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ) ۔
____________________
(۲) سورہ اعراف:۵۰
(۳) جنات کوآگ سے پیدا کیاہے لہذا یہ ناری مخلوق جبکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں یہ معصیت نہیں کرتے کیونکہ ان میں حیوانی غرائیز نہیں پائے جاتے جو نافرمانی اورتمیز کے متفاقی ہوتے ہیں۔ناری مخلوق اورحیوانات غرائیز حیوانی (کھانا پینا‘ نکاح کرنا رکھتے ہیں اورابلیس کو خدانے آگ سے پیدا کیاتھاجیساکہ یہ خود فخریہ انداز میں کہتاہےاناخیر خلقتنی من نار ۔
سورہ اعراف:آیت ۱۲
میں زیادہ بہت ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا لہذا اس میں غریز ہ حیوانی تھا وج نافرمانی اورسرکشی کا متقاضی ہے۔
جب تمہیں سجدہ کرنے کاحکم دیاگیاتو پھر کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا۔(۱)
فرشتوں کو سجدہ کاحکم دیئے جانے کے علاوہ قرآن مجید میں کسی اور سجدہ کا حکم نہیں لہذا یہ آیت ابلیس کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے تم نے حکم عدولی کیوں کی اورسجدہ کیوں نہ کیا۔لہذا جب ابلیس کو بھی سجدہ کا حکم تھااوراس نے نافرمانی کی اورلعنت کامستحق ٹہرااورآواز قدرت آئی۔
( قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ) ۔(۲)
یہاں سے نکل جابیشک تو راندہ درگاہ ہے اورقیامت تک تجھ پرلعنت برستی رہے گی۔
( وَقُلْنَا یَاآدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُلاَمِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَتَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلاَتَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنْ الظَّالِمِینَ )
ترجمہ:ہم نے کہااے آدم تم اپنی زوجہ کیساتھ جنت میں رہواور جو جی چاہے (آزادی سے کھاو) تہمیں کھانے کااختیار ہے لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جاناوگرنہ تجاوز کرنے والوں میں سے ہوجاو گے۔
گزشتہ آیات میں حضرت آدم کی خلقت کے اجتماعی جہات کے متعلق بات ہوتی رہی ہے جسمیں حضرت آدم کی خلقت ‘خلافت الصیرّ‘تعلیم اسماء‘اور معلم ملائکہ ہونے کے حوالے سے تذکرہ ہوا۔اب اس آیت سے حضرت آدم کے انفرادی پہلووں کا تذکرہ ہورہاہے۔اس میں دنیاوی زندگی میں ‘شریک حیات ‘رہایش کی جگہ (جنت ) اور دیگر ضروریات زندگی کو بیان کیا جارہاہے۔
____________________
(۱) اعراف:۱۲(۲) سورہ حجرآیت :۳۴‘۳۵
تشکیل خانوادہ:۔
حضرت آدم کو خلقت کے بعد تنہائی کی وحشت سے دوچار ہوناپڑا۔تنہائی کو ختم کرنے کے لئے پروردگار عالم نے آپ کے لئے شریک حیات کو خلق فرمایاتاکہ حضرت آدم تنہائی کے کرب سے نکل آئیں حضرت حواّ کی تخلیق کی جزئیات قرآن مجید میں صراحت کیساتھ مزکورنہیں البتہ قرآن مجید میں دوآیات ایسی ہیں جن میں حواّ کی خلقت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ارشادرب العزت ہے۔
( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) ۔( اعراف : ۱۸۹)
وہ اللہ جس نے تہمیں ایک نفس سے پیدا کیاہے اوراسی سے اس (نفس واحدہ) کا حقبت بنایاہے تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔
بہرحال ان آیات سے اتنا واضح ہوتاہے کہ ان دونوں کوایک چیز سے پیدا کیاگیاتھاان کی پیدائش کے حوالہ سے علماء اکرام میں بہت زیادہ اختلاف پایاجاتاہے بعض کے نزدیک حضرت آدم کی ساخت سے بچ جانے والے خمیر سے حواّ کو خلق کیاگیاتھا اس کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت حواّ کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے خلق کیاگیاتھااوراس کی تائید حضرت امیر المومنین کے احکام اور قضایامیں نقل ہواہے۔
یہ ایک طویل واقعہ ہے جس میں ایک شخص کو بلایاگیا۔جسکے دونوں آلے تھے ‘حضرت سے پوچھا گیاکہ یہ عورت ہے یامرد۔
حضرت نے اسکی پہچان کی مختلف صورتیں بیان فرمائیں اورآخر میں فرمایااسکی پسلیاں دیکھی جائیں اگر ایک پسلی کم ہے تو یہ مرد ہے اوراگرزیادہ ہے توعورت ہے۔( ابوالفتوح زازی جلد ص)
بہر حال اسی وجہ سے حضرت آدم نے اسکانام حواّرکھا کیونکہ یہ پسلی سے زندہ خلق کی گئی تھی۔
حقیقت جنت:
حضرت آدم کی تسکین کیلئے جب حضرت حواّ کو خلق کیاگیاتواس وقت اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایاکہ جاو جنت میں رہو۔
حضرت آدم جناب حواّ کے ساتھ جنت میں رہنے لگے۔(۳)
علماء کرام کے درمیان اختلاف پایاجاتاہے کہ اس جنت سے کونسی جنت مرادہے تفاسیر نے اس سلسلے میں کم ازکم چار مقامات کاتزکرہ فرمایاہے۔(۴) لیکن شاید صحیح قول یہ ہے کہ یہ دنیا وی جنت ھی۔اس سلسلے میں روایات بھی موجودہیں جو اسکی تائید کرئی ہیں مثلاًحسین ابن یسر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم کی جنت کے متعلق حضرت امام جعفر صادق سے سوال کیاتوحضرت نے ارشاد فرمایا۔
یہ دنیاوی جنات میں سے ایک جنت تھی جن جنت میں شمس وقمر طلوع کرتے تھے (مزید فرمایا) اگر یہ آخرت کی جنت ہوتی تو کبھی بھی حضرت آدم کو وہاں سے نہ نکالاجاتا۔(۵)
____________________
(۳) جنت کی اصل جن سے پہلے اسکا معنی پوشیدہ ہوتاہے لہذا ایسی زمیں جو درختوں سے پوشیدہ ہوگی ہواور اسمیں سرسبز باغات ہوں اسے جنت کہاجاتاہے۔
(۴) علماء نے ویسے توکئی جنات کاتزکرہ کیاہے لیکن چار جنتیں زیادہ شہرت رکھتی ہیں
الف۔جنت برین۔
ب۔ کسی اورسیارے کی جنت۔
ج۔ علم برزخ کی جنت۔
(۵) سألت اباعبدالله عن جنة آدم مقال جنات الدنیاتطلع فیها الشمس والضمر ولوکانت من جنات الآخرة ماخرج مناه ابداکافی
اورگزشتہ آیات کاسیاق سباق بھی یہی بتاتاہے کہ یہ دنیا وی جنت تھی کیونکہ ارشاد رب العزت ہے۔
آدم کو مٹی سے پیدا کیاگیا۔(۱)
حضرت آدم کو زمین کے لئے خلیفہ بنایا گیا۔(۲)
اسی طرح روایت میں معصوم نے فرمایا۔
لولا الحجة لساخت الارض باهلها ۔(۳)
اگرزمین پر حجة خدا نہ ہوتو زمین ہر چیز سمیت غرق ہوجائے۔
اسی طرح اگریہ دنیاوی جنت ہو تو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں رھتی جبکہ حضرت آدم اورجناحواّ کو حکم دیاگیاکہ جنت میں جاکر رہو وہاں عیش سے زندگی گرارو اورانہیں حکم ہواکہ ”لاتقربا هذه الشجر “ یعنی اس درخت کے پاس نہ جانا۔یہ تکلیف ہے۔اوردنیا درالتکلیف ہے‘لہذا اس سے ظاہر ہوتاہے کہ دنیاوی جنت تھی۔(۴)
____________________
(۱)حلق من الارض (۲)انی جاعل فی الارض خلیفه (۳)
(۴) اس کے علاوہ بعض علماء قائل ہیں کہ یہ جنت برین تھی لیکن بریں میں خلا اورہمیشگی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق سے بیان کردہ حدیث میں کہاگیاہے کہ اگر جنت برین ہوتی تو کبھی حضرت آدم کو وہاں سے نہ نکالا جاتانیز اگر یہ جنت بریں ہوتی تو شیطان کبھی نہ کہتا( هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ ) طہ :۱۲ یعنی کہا میں تمہیں ایسے درخت کے متعلق نہ بتاو جسکا پھل کھانے سے تم ھمیشہ جنت میں رہو۔ اسی طرح اس سے بھی یہیں کہاجاسکتا ہے کہ یہ عالم برزخ کی جنت تھی کیونکہ دنیاوی زندگی سے کوچ سے پہلے عالم برزخ میں داخل نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے( مِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى یوْمِ یبْعَثُونَ ) لہذا یہ برزخی جنت بھی نہ تھی اسی طرح کسی اورسیارے کی جنت ہوتا بھی اوپر بیان کے گئے دلائل کے ہونا مناسب نہیں ہے لہذا کہاجاسکتاہے کہ شاید وہ جنت دنیادی جنت تھی۔ البتہ یہاں کوئی یہ اشکال کرسکتاہے کہ آیت میں ”اھبوطہ“ لفظ موجودہے جسکا معنیٰ نیچے اترنے کاہے اگر یہ آسمانی جنت نہ وہتو نیچے اترنے کاامر کیا معنی ہے؟اس میں علماء نے کئی جواب دیئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اصبطوا صرف نزول مکانی کیلئے استعمال ہو بلکہ یہ نزول رتبی کیلئے بھی استعمال ہوتاہے” والله العلم بالصواب“
د۔ دنیاکی جنت۔
انسان مخلوق مختار:
حضرت خدا وند متعال نے حضرت آدم اور جناب حواّ کو جنت میں داخل کرکے ارشاد فرمایا۔کہ اس جنت میں تمہارے لیے ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں۔آپ کیلئے آسائش ہے ‘ یہاں کوئی رنج وغم نہیں ہے۔یہاں دنیاوی زندگی گزارنے کی تمام ضروری چیزیں موجودہیں۔رہائش کیلئے جنت جیسا گھر ہے ‘تسکین کے لئے حواّ جیسی بیوی ہے اور کھانے پینے کیلئے جنت کی ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے۔
آپ کو بالکل خود مختار منایاگیاہے اس جنت سے جو کچھ کھانا چاہو کھاو لیکن فلاں درخت کے قریب نہیں جانا(۱) اگر اپنی اختیار و مرضی سے اس کے قریب گئے تو تمہیں خسارہ اٹھانا ہوگااور جنت سے جانا ہوگااور یہ ظلم ہوگا۔(۲)
____________________
(۱) شجرہ ممنوعہ کی تفسیر کے سلسلہ میں علماء کرام کے درمیان اختلاف موجودہے قرآن مجید میں اسکے متعلق تو وضاحت موجود نہیں ہے البتہ روایات میں اسکاتزکرہ موجودہے کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا اوراس سے تناول نہ کرنا۔ مزید روایات میں ہے کہ شاید یہ درخت گندم ‘انگور‘ کافور اوربعض میں اسکے علاوہ اور چیزوں کا تزکرہ بھی ہے البتہ ان روایات کی اسناد میں خدشہ کیاگیاہے لہذا کہاجاسکتاہے یہ قشابھہ آیات میں سے ہے اور ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسادرخت تھا جسکی وجہ سے حضرت آدم اورحواّ کو جنت سے نکلنا پڑا۔
(۲) ظلم کا معنی وضع الشی فی غیر محلہ ہے اورقرآن مجید نے بھی اسکی یہ تعریف کی ہے ”ومن یتعد حد ودالله فاوٴ لاللک هم الظالمون “یعنی اللہ کی مقرر کردہ حدود سے قدم بڑھانے والے ظالم ہیں لیکن حد کو دیکھنا ہوگا کہ یہ واجب قرار دی گئی ہے یا مستحب اورارشاد ہے۔اس کا ظ سے ظلم کا حکم بھی مختلف ہوجائے گااور وہ ظلم جو حدو جوبی سے تجاوز ہووہ گناہ ہے جبکہ دوسری اقسام کا ظلم زیادہ سے زیادہ ترک اولیٰ “ ہوگا گناہ ہوگا۔
تکلیف میں کسی نہ کسی قسم کی مصلحت ضرور ہوتی ہے ہوسکتاہے اس نہی اور منع کرنے میں بھی کوئی بڑی مصلحت ہو اوراس میں ایک یہ ہوسکتی ہے کہ انسان سے کہاجارہاہوکہ تمہیں ہمیشہ اس جنت میں رہنے کے لئے خلق نہیں کیاگیاہے بلکہ تمہیں زمین کے لیئے خلیفہ بنایاگیاہے اور تمہیں مٹی سے پیدا کیاگیاتھالہذا اگر حضرت آدم اس درخت سے تناول فرماتے تو مصلحت خلقت انسان کو عملی جامہ نہ پہنایاجاسکتا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کے سجدہ اور ابلیس کی سرکشی کاواقعہ سات مرتبہ ذکر ہواہے
اورحضرت آدم کو جنت سے نکالے جانے کا تزکرہ تین سورتوں میں ہواہے۔(۱)
ان تمام آیات کو اکٹھاکرکے نتیجہ نکالیں تو”فتکونامن الظالمین “ میں اصطلاحی ظلم مراد نہیں ہے بلکہ اسکا معنی دنیاوی مصیتیں ‘ نقصان اورخسارہ اور تجاوز ہے(۲)
لہذا یہاں جزا کے حق میں ظلم نہیں ہے بلکہ اپنے نفس پر تجاوزجیسا ہے کہ قرآن مجید بھی اسی کی تائید کرتاہے کہ
( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ۔(۳)
پروردگار ہم نے اپنے نفس پر تجاوز کیاہے اوراگرتم نے ہمیں معاف نہ کیاتو ہم خود کو خسارے میں ڈالنے والے ہونگے۔
بہرحال اس ظلم سے مراد وہ نقصان اور خسارہ ہے جو دنیا میں تنگدستی اورسختی کا موجب ہوگااور تاکوینی طورپراس درخت سے دیکھنے کااثر ہے جبکہ یہ خداوندمتعال کے فرمان کی معصیت نہیں ہے بلکہ حضرت آدم “ ابو الا بنا ء اولی الاعظم اور معصوم تھے ان سے خدا کی معصیت کا سرزدہوناناممکن ہے۔ اب یہاں علماء کرام نے خسارے میں پڑجانے کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف احتمالات
بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کا زمین پرآنا سزا کے طور پر نہ تھا بلکہ اس کواس لئے خسارہ کہاگیاتھاکیونکہ شیطان حضرت آدم پر اپنے حربے میں کامیاب ہوگیاتھا۔اس سے زمین پر جا کر لوگوں کو پھسلانے کی اسکی جرات بڑھ گی۔
بعض علماء نے فرمایاہے کہ اس کو خسارہ اس لئے کہاگیاہے کیونکہ اس ظاہری باغ وبہار کو چھوڑکر نئے سرے سے زمین کو آباد کرنے کی زحمت کرناپڑی لہذااسے خسارہ کہاگیاہے اور بعض علماء نے کہاہے کہ حضرت آدم کیلئے خسارہ کا لفظ اس لئے استعمال ہوا ہے کہ حضرت آدم کو ملائکہ کی تسبیح وتقدیس سے جو مانوسیت حاصل ہوتی تھی۔اب ظاہری طور پر حضرت آدم اس سے جداہوگئے چنانچہ حضرت آدم کو اس کا بہت زیادہ افسوس تھا لہذا اسلئے کہاگیاہے کہ تم خسارہ میں ہوگئے۔
آدم کا گناہ کیاتھا:۔
( فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَی حِینٍ ) ( ۳۶)
تو شیطان نے ان کے ارادے سے انہیں اس جگہ سے ہٹایا اور جہاں وہ تھے وہاں سے انہیں نکلوادیا۔اورہم نے کہا تم اتر جاو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔
شیطانی وسوسہ:
خداوند متعال نے حضرت آدم اور حضرت حواّ کیلئے جنت جیسے مقام کو رہائش گاہ قراردیا۔وہاں ایک عرصہ تک ٹھہرے۔شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم کو فوراً ہی زمین پراتار دینے سے وحشت نہ ہو لہذا کچھ وقت سرسبز اورشاداب مقام پر گزار لیں۔جہاں ضروریات زندگی کی ہر چیز میسرہو۔تاکہ یہاں رہ کر اگلی منزل کیلئے تیار ہوجائیں اور شیطانی وسوسوں کا بھی عملی طور پر ملاحظہ کرلیں کہ کس طرح دشمنی کرتاہے اورکس طرح لوگوں کو پھٹکاتاہے۔اب اگرحضرت آدم اپنی قوم کو تبلیغ کرتے کہ شیطانی وسوسوں سے بچ کر رہنا یہ میرا اور تمہارا دشمن ہے اورلوگوں کو جنت سے پھٹکانے کی کوشش کرتاہے۔
یہاں لوگ سوال کرسکتے تھے کہ یہ کس طرح ہمارادشمن ہے اسکا جواب تو یہ دیتے کہ اس نے مجھے سجدہ نہ کیاتھااور دشمنی کا واضح طور پر اظہار کیاتھالیکن اگر حضرت آدم کو جنت میں نہ رکھا جاتاتو یہ دوسرے سوال کاجواب نہ سے سکتے کہ کس طرح شیطان وسوسے کرتاہے لہذا اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تاکہ آپ شیطانی وسوسوں سے آگاہ ہوسکیں کیونکہ اس دنیا میں وہ حضرت آدم تمہیں پھسلا سکتاتھا۔اب حضرت آدم کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح وسوسے ڈالتاہے اس سے کس طرح بچ کر رہنا ہے۔
شیطان کو بھی یہ موقع غنیمت لگا کہ دنیا میں تواللہ کے اس مخلص بندے پر میرا کوئی اثر نہ ہوسکے گالہذا یہ حضرت آدم کے پاس آ کر اس انداز سے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتاہے(۱) اور کہتاہے۔
( مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ) ۔(۲)
خدا نے تمہیں اس درخت سے اس لئے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاو۔
لیکن یہ کہنے کے بعد اسے اندازہ ہواکہ جو مسجدو ملائکہ ہواس کے لئے ملک سنا کوئی اہمیت نہ رکھتاتھا لہذاایک اور ہتکنڈا استعمال کرتاہے۔( أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ) ۔(۳)
تہمیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم اس کے استعمال سے ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بنو لہذا اس کو کھالو اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس زمینی جنت پر قیام کرو اوراس کے بعد یہ قسمیں کھانے لگا کہ میں سچ کہہ رہا ہو۔(۴) لیکن حضرت آدم نے اس کی ایک نہ مانی اور فرمایاجس چیز سے خدا نے مانع فرمایاہے میں وہ ہرگز بجا نہیں لاسکتا۔
اب اس نے حضرت حواّ کے پاس جانے کا سوچا اوروہاں جاکر کہنے لگااللہ تعالیٰ نے اب اس درخت کو تمہارے لئے مباح قراردیاہے اب اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں رہااگر تم نے آدم پہلے اسے کھالیا تو آدم پر حکمران رہوگئی حضرت حواّ نے اسے تناول کر لیا اورپھر حضرت آدم کے پاس جا کر کہا میں نے اس درخت کو تناول کرلیا ہے اسکا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوالہذا آپ بھی اسے تناول فرمالیں یہ مباح ہوچکا ہے مباحت کا سن کر حضرت آدم نے بھی تناول کرلیا اوراس طرح شیطان اسے پھسلانے میں کامیاب ہوگیا۔(۵)
_____________________
(۱) اعراف : ۲۰(۱) اعراف :۲۰ (۲) اعراف:۲۰
(۴)( وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) ۔اعراف :۲۱ یعنی شیطان قسمیں کھا کر کہنے لگا میں تہمیں نصیحت کررہاہوں کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔لیکن حضرت آدم نے اس کی قسموں کی پروا نہ کی۔
(۵) جہاں عدوات ودشمنی ‘حسد وکینہ ‘جھوٹ ‘ سختی فنا کدورت اورشقاوت جیسا ماحول ہوگا۔اس میں لوگ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہونگے اورابلیس اوراس کے پیروکار بھی حضرت آدم کی نسل کیساتھ دشمنی رکھتے ہونگے یہ کفر وطعنیان اور ایمان واعتقادات کی وجہ سے دشمنی کریں گے اور ابلیس اوراسے کے پیروکار راہ راست سے ہتکانے کیلئے ہر ممکن حیلہ و بہانہ تلاش کریں گے اورکوشش کریں گے کہ انسان کو نیکی کے راستہ سے ہٹالیں اوراسکے لئے خدا کی خوشنودی اورزیادہ ثواب کا لالچ دیکر برے کاموں میں پھنسانے کی کوشش کریں گے یہ نہ صرف مردوں کا دشمن ہے بلکہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔
انسانی نسل کا دشمن :
حضرت آدم اورحضرت حواّ جب اس شجرہ ممنوعہ سے شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے تناول کر بیٹھے تواللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت آدم اورانکی اہلیہ کو حکم دیا کہ اس پاک وپاکیزہ سرزمین ‘جسمیں جنت جیسا ماحول تھا ‘ضروریازندگی کی ہرچیز میسر تھی۔کسی قسم کی پریشانی نہ تھی‘کو چھوڑ کر کسی اورجگہ منتقل ہوجاو۔
یہ ہر انسان کواس کے مزاج کے مطابق جال میں پھنساتاہے عورتوں کو گمراہ کرنے کیلئے عورتوں کے مزاج کے موافق پھندے ڈالتاہے مردوں کیلئے مردوں کا مزاج اختیار کرتاہے لہذااس دشمن سے بچنا ضروری ہے اس کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکا لاگیااورخبردار کہاگیاکہ زمین پراسکا خیال رکھنا یہ تمہاری پوری نسل کا دشمن ہے گویا کہاجارہاہے کہ اپنی نسل کو اسکی مکاریوں ‘وسوسوں اورشیطانی حربوں سے بچنے کی تلقین کرنا البتہ یہ زمین پر جا کر سب مخلصین کو ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کریگا۔
عارضی قرار گاہ:
خداوندعالم نے حضرت آدم کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اورفرمایا کہ ایک مغیر مدت تک زمین میں تمہاری قرارگاہ ہے تم اس جگہ سے ایک وقت تک استفادہ کرتے رہو اس میں تمہاری اولاد کو مکمل اختیار ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں میں پھنس کر جہنم کا راستہ اختیار کریں یا خداوند متعال کی فرمان برداری کرکے جنت میں آئیں ہم نے تو یہاں آپ کے عمل کو دیکھنا ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔
( ثُمَّ جَعَلۡنٰکُمۡ خَلٰٓئِفَ فِی الۡاَرۡضِ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ لِنَنۡظُرَ کَیۡفَ تَعۡمَلُوۡنَ ) ۔(۱)
ان کے بعد ہم نے تہمیں دنیا میں انکا جانشین بنایاہے تاکہ ہم دیکھیں کیسے عمل کرتے ہو۔
لہذا بتایاجارہاہے کہ
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
حضرت آدم سے ترک اولیٰ ہواتوانہیں یہ خسارہ دیکھنا پڑا کہ معصوم ہونے کے باوجود جنت سے نکال دیئے گئے روایات میں مختلف مقامات کاتزکرہ موجودہے کہ حضرت آدم کو کہاں بھیجا گیا۔(۲)
ہم حضرت رسول خداسے مروی ایک روایت تبرکا ًبیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ خداوندمتعال نے حضرت جبریل کو وحی کی کہ حضرت آدم کو مکہ میں اتارو توحضرت جبریل نے حضرت آدم کو پہاڑ صفا اورحضرت حواّ کو مروہ پراتارا۔(۳)
____________________
(۱) ابراھیم :۱۰
(۲) روایات میں ہر زمین ‘مکہ ‘مدینہ ‘ اردن وفلسطین ‘کا تزکرہ موجودہے۔
(۳)وحی الله تعالی ٰ الیٰ الجبریل ان اهبطهما الی البلا ه المبارکه مکه فهبط بهما جبرئیل والقی آدم علی الصفا والقی حوا علی المروه تفسیر عیاشی جلدا۔ص۲۶
اس روایت کی تائید حضرت امام صادق سے بیان کردہ روایت بھی کرتی جس میں حضرت نے فرمایا۔
جب حضرت آدم مکہ کے ایک پہاڑ پراتارے گئے توحضرت آدم کے ” صفی اللہ “ لقب کی وجہ سے اس پہاڑ کانام صفا رکھا گیااورحضرت حواّ کو صفا کے مقابل پہاڑ پراتاراگیا اسکا نام مروہ رکھا گیا۔
حضرت آدم چالیس دن تک سجدہ کی حالت میں گرایہ کرتے رہے حضرت جبرائیل آئے اورانہوں نے کہا اتنا گرایہ کیوں کررہے ہو توحضرت آدم نے فرمایا میں کیسے کریہ نہ کروں مجھے خدا کے جوارسے نکال دیاگیاہے۔(۱)
جب حضرت آدم ترک اولیٰ کی وجہ سے نکالے جاسکتے ہیں توہم خداکی نافرمانی کرکے کس طرح جنت کے حقدار ہوسکتے ہیں شیطان نے ابتداء سے ہمارے بابا کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیاتھا کیااب بھی ہم اس کے دھوکہ میں آکر خداسے روگرادنی کریں اوراحکام خداکو پس پشت ڈال دیں جبکہ خداکہہ رہاہے کہ صرف میری عبادت کرو اورجوعبادت میری منشاء و مرضی کے خلاف ہوگی میں اسے ہرگز قبول نہ کرونگا۔
اللہ کو صرف وہی عبادت پسند ہے جواسکا بھیجا ہوارسول بتائے اوراس کے بعد اسکا صحیح قائم مقام بتائے ہر من گھڑت عبادت شرف قبولیت حاصل نہیں کرسکتی۔شیطان سجدہ کا منکرنہ تھابلکہ اس طریقہ پرسجدہ کرنے کا مخالف تھا جسکا خدانے کہاتھاجس سے اس نے خلیفة اللہ نافرمانی کی اورتعظیم کرنے سے انکارکیاتھا۔بہرحال خلیفة اللہ کی نافرمانی ہزاروں برس کی عبادت پرپانی پھیر دیتی ہے۔
____________________
(۱) تفسیر ابن ابراھیم۔جلد:۱۔ص:۴۴
لیکن یہ یادرہے کہ شیطان سجدہ کامنکرتھاعبادت کا منکرنہ تھا اسلئے خدانے اسے مشرک نہیں کہا بلکہ کافر کہاہے جبکہ تارک نماز کوخداتعالیٰ نے مشرک کہاہے ارشاد رب العزت ہے۔
( أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ لا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکینَ ) ۔(۲)
نماز قائم کرو اورمشرکین نہ بنو۔لہذا ہمیں نماز جیسے اہم فریضہ کو ترک کرکے مشرک نہیں بننا چاہیے۔
( فَتَلَقَّی آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ )
پس آدم نے اللہ سے (اندازتوبہ کے ) چند کلمات سیکھے اوران کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کیا۔بلاتردید وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اورنہایت رحم کرنے والاہے۔
حقیقت توبہ:
توبہ کا اصلی معنی بازگشت ‘رجوع اورلوٹنا ہے اورحقیقت توبہ کے بارے اگرچہ مفسرین کی آراء مختلف ہیں لیکن ان کی بازگشت ان تین چیزوں کے مجموعے کی طرف ہوتی ہے۔کہ انسان تہہ دل سے اپنے گناہ پرنادم ہواوراس کا تدارک کرلے اورآئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم عزم کرے اگرچہ حقیقی توبہ کرنے کی توفیق انسان کو نصیب ہوجائے اس کانتیجہ حتمی نجات ہے۔لہذا یہ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کے ذریعے اپنے پرورگار کی رحمت کی طرف لوٹ آئے
عقل سلیم کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اصلاًایسا کام نہ انجام دے جس سے اسکو ندامت وپشیمانی کا سامنا کرنے پڑے اورفارسی میں مشہوربھی کہ عامل ًتکند کاری کہ باز آید پشمانی۔اورتوبہ میں بھی ایسے کئے کہ اثرشوم کو دیکھ ندامت کے سرجھکانے پر مجبور ہوجاتاہے۔اوراحادیث معصومین بھی اسی کی طرف راہنمائی کرتی ہیں کہ ”له ترک الزنب اهون من الثوم “ گناہ نہ کرنا توبہ کرنے سے آسان ہے۔
____________________
(۲) روم :۳۱
لیکن اللہ نے توایک طرف انسان میں نمریزہ شہوت وحیوانیت رکھا اوردوسری طرف سے شیطان کو انسان کے پیچھے گمرہ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔تو خداتعالیٰ کو علم تھا کہ انسان سے غلطیاں ہونگیں لغزشیں ہونگیں اگر میں نے اس کے لئے اپنی رحمت کی طرف لوٹنے کے تمام دروازے بند کردیئے وہ مایوس ہوکر تاابدبد بختی کا شکار ہوجائیگاجس کو خود ذات حق پسند نہیں کرتی لہذا اس ذات رحیم وکریم نے گناہ گاروں کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھاہے کہ اگر کسی سے جہالت کی وجہ سے برائی سر زد ہوجائے تووہ اس دروازے سے اپنے رب کی طرف واپس آجائے۔اوراپنے کئے پر پشمان ہوکر اس کی تلافی کرلے اورآئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرلے اورروایات میں ہے آخری ہم تک توبہ قبول ہوسکتی۔
رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ
” من تاب قیل توبه سنة ًتاب الله علیه ‘ثم قال ان السنة لکثیرة ‘ومن تاک قبل توبه بشهر ٍتاب الله علیه ثم قال ان لشهر لکثیر ومن تاب قبل توبه بیوم تاک الله علیه ‘ثم قال وان لیوم کثیر ومن تاک قبل توبه بساعة تاب الله علیه ثم قال وان الساعة لکثیر ومن تاب وقد بلغت نفسه موزاواهویٰ بیده الی حلقهتاب الله علیه
کہ جو شخص اپنی موت سے ایک سال پہلے توبہ کرلے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتاہے۔پھر فرمایا‘ایک بہت زیادہ اگر کوئی شخص اپنی موت سے ایک ماہ پہلے توبہ کرلے تواللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔پھر فرمایا‘ایک ماہ بھی بہت زیادہ ہے اگر کوئی شخص اپنی موت سے ایک دن پہلے توبہ کرلے تواللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔پھر فرمایا‘ایک دن بھی زیادہ ہے اگر کوئی شخص اپنی موت سے ایک گھنٹہ پہلے توبہ کرلے تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتاہے۔پھر فرمایا‘ایک گھنٹہ بھی زیادہ ہے اگر کوئی شخص اس وقت توبہ کرلے جب اس کی جان لب پر آئی ہوتواس کی توبہ قبول کرتاہے۔
اگرچہ یہ حدیث رحمت الہی سے کسی صورت مایوس نہ ہونے کی طرف راہنمائی کرتی ہے اوراللہ نے جس چیز کا آیہ مبارکہ میں ذمہ لیا اس کی وضاحت کررہی ہے کہ ’
( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ )
کو خدا کسی طرح بھی ان لوگوں کی توبہ رد نہیں فرمائیگاجو نادانی کی وجہ سے گناہ کربیٹھیں اورقریب ہی میں توبہ کرلیں۔
رحمت الہی کے اتنا وسیع ہونے کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان توبہ میں جلدی نہ کرے۔کیونکہ انسان کو خبر نہیں ہے کہ اس نے داعی اجل کو کب لبیک کہنا ہے تواسے کب علم ہے کہ میری موت میں کتنا عرصہ باقی ہے کہ وہ اس لحاظ سے توبہ کرے۔اورموت وقت کی تعین نہ کرنے کی وجہ بھی شاید یہی ہو۔
لہذا جتنی جلدی ہوسکے اپنی کوتاہیوں اورلغزشوں پر سچے دل سے پشیمان ہو کر بارہ گاہ الہی میں لوٹ آنا چاہیے اورآیہ مبارکہ ” وسااعواالے مغفرة من ابکم رحمة “ کا حکم بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے‘اور جواانی میں توبہ کرنا شیوہ پیغمبر ی بھی ہے۔اگرچہ یہ حضرات قدسیہ ہرقسم کے گناہ ولغزش سے پاک وپاکیزہ ہوتے ہیں لیکن انکے استغفاروتوبہ کی نظیر نہیں ملتی ہے خود رسول اللہ جو عالمین کی خلقت کی علت نمائی ہیں کے بارے روایات میں آیاہے آپ دن میں تین سو مرتبہ استغفاکرتے تھے۔
توبہ کے بارے روایات میں آیاہے اعمال خیر میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل توبہ ہے اورتوبہ کو شفاعت کرنے والابھی قرار دایا گیاہے۔
لہذا انسان کو چاہیے کہ توبہ کو توہین نہ سمجھے انسان سے گناہ سرزد ہونا بعید نہیں ہے اس گناہ کو توبہ کے ذریعے دھویا جاسکتاہے توبہ کر کے انسان ایسے بن سکتاہے کہ ابھی شکم مادر سے جنا گیاہے۔
حقیقت میں کسی بندے کی توبہ اپنے رب اس شخص سے بھی زیادہ خوش کرتی کہ جس کازاد و راحلہ تاریک رات میں گم ہوجانے کے بعد مل جائے۔
آخر میں خداتعالیٰ سے عاجز ایہ التماس ہے کہ ہمیں اورآپ کو سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عنائت فرمائے اوراسے شرف قبولیت بخش ہمارے لئے شفاعت کرنے والا قراردے۔
حقیقت توبہ کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں لیکن ان سب کی بازگشت ان تین چیزوں کے مجموعے کی طرف ہوتی ہے کہ انسان تہہ دل سے اپنے گناہ پرنادم ہواوراس کا تدارک کرے اورآئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم عزم کرے۔
اگرحقیقی توبہ کرنے کی انسان کو توفیق ہوجائے اس کانتیجہ نجات ہے۔
کلمات توبہ :۔
خداوندعالم نے حضرت آدم کو جن کلمات کی تعلیم فرمائی تھی ان کے متعلق مفسرین میں اختلاف پایاجاتاہے۔بعض مفسرین نے فرمایاہے کہ یہ کلمات قرآنی آیات پر مشتمل ہیں اوربعض نے کہا ہے ان کلمات کاتذکرہ روایات میں موجود ہے مثلاً
بعض کے نزدیک سورہ اعراف کی یہ آیت تھی۔
( قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ۔(۱)
ان دونوں نے کہاخدایا!ہم نے خود پر ظلم کیااگر تو نے ہمیں نہ بخشا (یا) ہم پر رحم نہ کیاتو ہم خسارے میں رہنے والوں میں سے ہوجائیں گے۔
تفسیر عیاشی میں حضرت امام محمد باقر سے روایت کئے گئے مندرجہ ذیل کلمات بیان ہوئے ہیں۔
لااله الاانت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفرلی انک انت الغفور الرحیم
خدا تیرے سواء کوئی معبود نہیں ہے۔توپاک وپاکیزہ ہے۔میں نے خود پر ظلم کیاہے مجھے بخش دے بیشک توہے بخشنے والا اوررحم کرنے والاہے۔
____________________
(۱) اعراف :۲۳
مجمع البیان میں کلمات سے مراد یہ دعاتھی
اللهم لااله الا انت سبحانک وبحمد ک انی ظلمت نفسی فاغفرلی انک خیر الغافرین اللهم لااله الاانت
سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیر الراحمین اللهم لااله الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم ۔(۲)
یااللہ !تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے توپاک وپاکیزہ ہے اورمیں کی ‘ انہیں عصادیا‘ان کے لئے دریاشق کیاان پربادلوں کا سایہ کیا؟
حضرت نے فرمایا!
انسان کے لئے اچھا نہیں ہے کہ خود اپنی تعریف کرے لیکن میں اتنا بتا دینا ضروری سمجھتاہوں کہ حضرت آدم سے خطا سرزد ہوئی تواس کی توبہ کے الفاظ یہ تھے۔
اللهم انی اسئلک بحق محمدوآل محمد لماغفرت
خدایا میں تجھ سے محمد وآل محمد کے حق کاواسطہ دیکر سوال کرتاہوں میری توبہ قبول فرماتوخد انے اسکی توبہ قبول فرمائی۔
حضرت نوح کشتی مین سوارہوئے اورانہیں کشتی کے غرق ہونے کا قطرہ لاحق ہواتوانہوں نے بارگاہ خدا وندی میں عرض کی۔
اللهم انی اسئلک بحق لما نجتتنی من الغرق
میرے اللہ تجھ سے محمد وآل محمد کے حق کے واسطے سوال کرتاہوں کہ مجھے غرق ہونے سے بچا خدانے نجات دی۔
____________________
(۲) مجمع البیان :جلد ۱:ص۲۰۰
اسی طرح جب حضرت ابراھیم کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے بھی یہی الفاظ دہرائے خدا یا محمد وآل محمد کے صدقے مجھے آگ سے نجات عنایت فرمااللہ نے آگ کو ٹھنڈا اورسلامتی کا موجب قراردیااور اسی طرح جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصی ٰپھینکا تو دل مین خوف محسوس ہواتوانہوں نے بھی یہی کلمات دہرائے توارشاد خداوندی ہوا۔
( لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ )
ان سے نہ گھبرا توان سے بلند مرتبہ والاہے۔
آخر میں فرمایا۔
اگر حضرت موسیٰ مجھے پالیتے اورمجھ پرایمان نہ لاتے توان کا ایمان اورنبوت انبیاء کوئی فائدہ نہ دیتی۔
اے یہودی !میری ذریت سے حضرت مہدی ہونگے اسکے مدد کیلئے حضرت مریم ابن اتریں گے اورحضرت مہدی کو آگے کھڑا کرکے اسکی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔
تیری تعریف کرتاہوں میں تیر تعریف کرتاہوں میں نے ظلم کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ توبہترین بخشنے والاہے۔
خدایا !تیرے سواء کوئی معبود نہیں توپاک وپاکیزہ ہے میں تیری تعریف کرتاہوں میں نے خود پر ظلم کیاتومجھ پررحم فرماکیونکہ تو بہترین رحم کرنے والاہے۔
پروردگار!صرف تو ہی معبودہے اورپاک وپاکیزہ ہے میں تیری حمد وثناء کرتاہوں میں نے
اپنے اوپر ظلم کیاہے تواپنی رحمت میرے شامل حال فرمااورمیری توبہ قبول فرما کیونکہ توہی توبہ قبول کرنے والااوررحم کرنے والاہے۔
اسی طرح متواتر روایات ائمہ طاھرین میں ہے یہ خمسہ نجباء (حضرت محمد ‘حضرت علی ‘حضرت فاطمہ ‘حضرت امام حسن اورحضرت امام حسین کا واسطہ دے کرکی گئی دعااور کلمات ذکرکئے گئے تھے
اورانہیں کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اس دعا کے الفاط یہ تھے۔
یارب ّاسئلک بحق محمد وعلی وفافطمة والحسن والحسین ۔
حضرت آدم بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں ‘پروردگار ا!میں تجھ سے محمد ‘علی ‘فاطمہ ‘ حسن اورحسین کے حق کا واسطہ دیکر سوال کرتاہوں میری توبہ قبول فرما۔
تفسیر برھان میں مذکورہے کہ حضرت امام جعفر صادق ایک روایت مذکورہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوااورآپ کے سامنے کھڑے ہوکر آپ کو دیکھنے لگا۔
حضرت نے فرمایا۔کیابات ہے۔
اس نے کہا
میرا ایک سوال ہے کہ آپ افضل ہے یا حضرت موسیٰ بن عمران جبکہ خداوندمتعال نے حضرت موسی ٰبن عمران کیساتھ کلام کیا‘ان پرتورات نازل فرمائی۔
بہرحال یہ تینوں قسم کی تفاسیر ایک دوسرے کیساتھ اختلاف نہیں رکھتی ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت آدم کوان سب کلمات کی تعلیم دی گئی ہوتاکہ ان کلمات کی حقیقت اورباطنی گہرائی پرغور کرنے سے حضرت آدم مکمل طورپر روحانی انقلاب پیدا ہواور خدااپنا لطف وکرم کرتے ہوئے اسکی توبہ قبول فرمائے۔(۱)
ایک سوال اوراسکا جواب !
حضر ت آدم نے غلطی کیوں کی؟
جواب :اگرچہ آیات۔۔۔۔فتکونا من الظالمین۔اور وعصی آدم فعویٰ ‘اورپھر حضرت آدم کا اعتراف جو قرآن میں حکائت ہواہے
( قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )
کاظاہریہی بتلاتاہے کہ حضرت آدم سے لغزش ہوئی ہے۔لیکن اگر اس واقع سے مربوط آیات کے بارے میں تذکرہ کریں اورکل شجرہ سے روکنے والی انہی میں دقت کریں تو واضح ہوجاتاہے کہ حضرت آدم سے گناہ سرزد نہیں ہوا۔کیونکہ یہ نہی صلا ح وخیر کی طرف راہنمائی کے لئے تھی حکم مولیٰ نہ تھا۔اس کی والہ بھی موجودہیں۔
( ۱) اس سورہ مبارکہ اورسورہ اعراف میں اس نہی کی مخالفت کو اللہ تعالی ٰ نے ظلم سے قرار فرمایاہے کہ
( وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ )
( قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا )
____________________
(۱) تفسیر نمونہ :جلد۱:ص۱۶۱
اورسورہ طہ میں اکل شجرہ کے نیچے کو ترک جنت کر کے مشقت دنیوی میں پڑجانے سے تعبیر کیاہے کہ “
( فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ )
ٰ اوراس سے بعد والی آیات ‘آ یات اس جنت ک اوصف بیان کررہی ہیں کہ اس جنت میں نہ بھوک ہے نہ عریانی اور نہ پیاس ہے نہ سورج کی تپش‘اورایسی مرفہ زندگی والی جگہ نکلنے کو اللہ شقادت سے تعبیر کیاہے اس کا معنی یہ بنتاہے کہ اس شینان کے بھکارے میں آکر اکل شجرہ سے نہیں اس دنیا میں جاناپڑیگاجس بھوک پیاس تھکاوٹ وسختی جیسی مشکلات ہونگیں ایسی زندگی سے محفوظ رہنے کی خاطر جو حکم دیاجاتاہے وہ کسی طرح بھی مولوی نہیں ہوسکتابلکہ مختصر ارشاد وراہنمائی ہے اس کی مخالفت اپنے کو مشقت میں ڈالناہے مولیٰ کی نافرمانی نہیں ہے۔
دلیل : ۲
توبہ جب قبول ہوجائے تواس کا معنی یہ ہے کہ عبد پر کوئی گناہ نہیں ہے” التائب من الذنب کمن لاذنب له“ (۱) کویا توبہ کو قبول ہوجانے کے بعد کا وہی مقام تھاجو گناہ کرنے سے پہلے تھا۔
اگر اکل شجرہ والی نہی مولوی تھی اوتوبہ حضرت آدم سے ازگناہ تھی توجب توبہ قبول ہوگئی توحضرت آدم کو اسی جنت میں واپس لایاجاتاجس سے نکالے گئے تھے جبکہ انہیں توبہ کے قبول ہونے کے باوجود زمیں رکھا گیااس کا لازمی نیتجہ یہ ہے کہ وہ توبہ گناہ سے توبہ نہ تھی اووہ نہی جس کی
مخالفت پرانہیں جنت سے نکلاگیاحکم نہ تھا۔بلکہ وہ عرض خلقت آدم کی تکمیل کے لئے ایک سبب تھا جواکل شجرہ کے تکوینی اثر کے طور ظاہر ہوااورتوبہ گناہ کے اثر تکلیفی کو ختم کردیتی ہے لیکن اثر کوینی وضسی کو ختم نہیں کر سکتی۔
_____________________
بحوالہ میزان الحکمہ :ج۱:حدیث :۲۱۱۶
دلیل : ۳
”قلنا اهبطو ۔۔اوراللہ تعالی نے فرمایاہے ”فامایأتینکم منی هدی ۔۔۔۔
یہ کلمہ ان تمام تفصیلی شریتوں کو شامل ہے جو اللہ نے کتب ورسل کے ذریعے دنیا میں رائج کیں یہ اس چیز کی غمازی کرتاہے کہ دنیا میں انسان کے لئے جو پہلا قانون بنا “امایأتیکم منی هدی ً “ کا جملہ اسی طرف اشارہ کرہاہے۔ تواس کا معنی یہ جب حضرت آدم نے اکل شجرہ اس وقت ابھی قوانین شریعیت بطور تکلیف وضع نہیں ہوئے تھے تو پھر اس اکل شجرہ کے گناہ یا معصیت ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے یہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ فرشتے تواس وقت مکلف تھے۔تبھی تو ابلیس کو سجد نہ کرنے پر روندادرگاالہی قرار دیاگیا جواب واضح ہے کہ فرشتوں کا محل تکلیف آسمان ہی تھا لیکن انسان کا محل تکلیف زمین ہے۔
علامہ سید علی نقی (رضوان اللہ علیہ ) کے فرمان کے مطابق نہ یہ حقیقی گناتھا اورنہ ہی توبہ ‘گناہ سے توبہ تھی بلکہ یہ صرف آدم کی جلالت کے لحاظ سے ایک بلند تر مرتبے سے پیچھے رہ جاناتھا۔جس کا احساس خدا کے مقرب بندوں اس سے کہیں زیادہ ہوتاہے جوایک عام آدمی سے بڑے گناہ سرزد ہونے اس کے ضمیر میں پیدا ہوتاہے۔
( قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدًی فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلاَخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَهُمْ یَحْزَنُونَ ) ( ۳۸)
ہم نے کہا! تم سب یہاں سے اترجاو۔اور جب آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جواس کی پیروی کریں گے انہیں خوف ہوگا نہ ملال۔
اھبطواکا تکرارکیوں؟
علماء اعلام نے اس سلسلے میں کئی احتمالات ذکر کئے ہیں بعض علماء کے نزدیک یہ تاکید کے لئے پہلے بھی اترنے کاحکم دیاگیاتھااب دوبارہ تاکیداًحکم دیاجارہا ہے کہ زمین پراترجاو۔
بعض علماء کے نزدیک دوبارہ حکم دینا تاکید کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ کسی اورمقصد کے لئے ہے یعنی حضرت آدم توبہ کے کلمات زبان پر الئے اورانکی توبہ قبول ہوگئی تواسکے بعد آدم سے کہا جارہاہے کہ تم سب زمین پراترو۔ایسا نہیں ہے کہ توبہ قبول ہونے کے بعد جنت میں رہنے دیاجائے اترنے کا پہلا حکم منسوخ ہوگیاہے بلکہ اس مرتبہ اترنے کے حکم کے ذریعے اللہ تبارک وتعالیٰ حکم دے رہاہے کہ توبہ قبول ہوجانے کے بعد بھی تمہیں جنت میں نہیں رہنا بلکہ تمہاری غلت نمائی ”انی جاعل فی الارض خلیفہ ً“ ہے
اس سے یہ بھی ظاہر ہوتاہے کہ حضرت آدم کا زمین پر اترنا سزا کے طور پر نہ تھا بلکہ زمین پر اترنا اس غرض سے تھا جس کے لئے حضرت آدم کو خلق کیاگیاتھا۔
بعض علماء نے یہ احتمال دیاہے کہ یہاں دونوں مرتبہ حکم جداجدا ہے اوراللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت آدم اوران کی اولاد کے لئے دو فیصلے صادر فرمائے ہیں۔
ایک مرتبہ ”اکل شجرہ ‘‘ کے بعد زمین پراترنے کا حکم دیاگیااس صورت میں حضرت آدم اوران کی اولاد کو زمین پر رہنا تھا اوراس کا لازمہ دنیا کی مشقت اور سختی تھا اوردوسری مرتبہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے اترنے کاحکم دیاتویہ حکم چونکہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوجانے کے بعد تھا اورکہاگیا:
تم سب زمین پر اترجاواوراس وقت دنیاوی زندگی کو خوف وحزن سے دور اس شرط کیساتھ دور قرار دیاگیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے جو ھدایت اور راہنمائی آئے گی جو بھی اس کی پیروی کریگا اسکے لئے دنیاوی زندگی میں خوف اورحزن ملال نہیں ہوگا۔
اس کے علاوہ بھی علماء نے احتمالات نقل کئے ہین جو ظاھر اًضعیف ہیں۔(۱)
____________________
(۱) بعض علماء نے کہاہے کہ پہلی مرتبہ اترنے کا حکم بہشت سے پہلے آسمان کی طرف کیلئے تھا اوردوسری مرتبہ اترنے کاحکم آسمان سے زمین کی طرف تھا۔اولاً یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوگا کہ حضرت آدم اسمانی جنت میں تھے جبکہ یہ درست نہیں ہے۔
ثانیاً۔یہ گزشتہ آیات کیساتھ بھی سازگار نہیں ہے کیونکہ پہلی مرتبہ اترنے کے حکم کے ساتھ ہی حضرت آدم سے کہاگیاتھا” ولکم فی الارض متقر ومتاع الی حسین “ ااس سے ظاہر ہوتاہے کہ زمین پراترنے کاحکم ہے کہ پہلے آسمان پر۔لہذا اگر یہ قول درست ہوتاتو اس وقت ضروری تھا کہ ’‘ولکم فی الارض مستقرومتاع الی حین “ والا حکم دوسرے اھبطوا کے بعد ہوتا۔
ھدایت کی پیروی :۔
حضرت آدم اورحواّ کو زمین پر بھیجنے کے بعداللہ تبارک وتعالیٰ اولاد آدم کو مخاطب کرتے ارشاد فرمارہاہے جب بھی تمہارے پاس ہماری ھدایت رسول یا کتاب کی شکل میں آئے تو تم میں سے جو بھی اس ھدایت کی اتباع کریگا اسکے لئے کامیابی وکامرانی کی بشارت ہے۔
یعنی اگر انسان سعادت کی طرف قدم بڑھائے تو وہ صرراہ خدا کی طرف گامزن ہوں۔لہذا جو بھی ارشال رسل اورانزال کتب پر قلبی اعتقاد رکھتاہوگاانبیاء اورائمہ کے فرامین پر عمل بھی کرتاہوگاتواس کے لئے خوف وملال نام کی کوئی چیزنہ ہوگی ‘ وہ عذاب الہی سے محفوظ ومامون ہوگااوراپنی مراد یں برلائے گااورآخرت والے دن ہر قسم کی پریشانی سے دورہوگابلکہ اگر اسکے اعمال درست ہوئے اورخدا کی شریعیت کے مطابق چلتا رہا توجنت الفردوس میں انبیاء اورعلماء کے ساتھ محشور ہوگا۔
بہرحال انسان کو تقوی ٰ اختیار کرنا چاہیے اورشیطان سے دوری اختیار کرنا چاہیے انسان اسے اپنا سخت دشمن سمجھے اوراس سے ہوشیار رہے کیونکہ سب سے خطرناک دشمن وہی ہوتاہے جو نظر نہ آتاہو جبکہ شیطان انسان کو دیکھ رہاہے اورانسان شیطان کو دیکھنے سے قاصر ہے۔لہذا تقوی ٰ اختیار کرنا ‘ شیطانی وسوسوں سے دور رہنا ‘واجبات پر عمل کرنا محرمات ترک کرنا اورشریعت کے دوسرے لوازمات کو ملخوظ خاطر رکھان ہی ھدایت کی پیروی اورکوف ملال سے چھٹکاراکا موجب ہے۔
ایک سوال اوراسکا جواب !
یہاں پر سوال یہ پیداہوتاہے کہ ‘ اس آیہ مبارکہ کی دوسے تودنیا میں حزن وملال نہیں ہونا چاہیے جبکہ دنیا میں مومن کیلئے کافر سے بھی زیادہ خوف وحزن ہے جیسے کہ آیات وروایات اس کو بیان کرتی ہیں کہ دنیا مومن کے لئے دارمشقت اورقید خانہ ہے۔جیسے کہ نبی کریم کا فرمان ہے
”خص البلاء بالانبیاء ثم الاولیا ء ثم الامثل مالامتل “
تو دنیا کی ظاہری صورتحال کو اس آیت مبارکہ کے ساتھ کیسے ہم آھنک کیاجاسکتاہے؟
جواب !
اس کوجواب یوں دیاجاسکتاہے آیات کی روسے دنیا کی سختی اورحزن اس کا لازمہ ہے جس میں کافر اورمومن شریک ہیں لیکن مومن کے عنوان نہیں بلکہ آزمائش وامتحان کے طور پر ہے اورکامیابی کی صورت میں اسکے لئے جنت جیسی نعمت سے نواز ا جائے گا جواس کے مصائب دنیاوی کی تلافی ہے۔
لیکن کافر کے لئے تلافی اورتدارک کاامکان نہیں ہے۔کیونکہ مومن نے تواپنے رب کے مقام ربوبیت کو پہچان کراس کے امکانات کی اس تعین پر پابندی کرکے تکالیف برداشت کیں کہ اسکااجراللہ کے ہاں محفوظ ہے۔تواس کاضمیر مطمن ہے شادی اسی وجہ سے اللہ اپنے مومن خالص بندے کو نفس مطمئنہ سے یاد فرماتاہے۔کہ( یاایها نفس المطمة ارجعی الی ربک راضة ًفرمضیه ) جبکہ کافر اولین مرحلہ اطاعت میں انکار کرکے اس اطمنان سے تہی دامن ہوگیاہے۔اوردنیا میں خوف وحزن مین مبتلاہے اورآخرت میں بھی اس کی تکالیف کاتدارک نہیں ہوگا۔
( وَالَّذِینَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ )
اورجو (ھماری ھدایت کا) انکارکریں گے اورہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہیں اورہمیشہ جہنم میں رہے گے۔
جہنمی کون؟
خداوندمتعال کھلے الفاظ میں فرمارہاہے کہ جہنمی کی دو بنیادی علامتیں ہیں ایک ہماری ھدایت کاانکار اورہماری ھدایت پر عمل نہ کرنے اوواجبات ومحرمات کا خیال نہ رکھنا ‘ضروریات دین کو ملحوظ نہ رکھنا اوردوسرا ہماری آیات کوجھٹلاتاہے یعنی ہماری ظاہری نشانیوں کا انکار کرتایعنی دلائل وحدانیت ‘عبادت خداوندی ‘ انزال کتب ‘ بعثت رسل۔۔۔۔ جیسی نشانیوں کاانکار کرنا یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنے کا باعث ہے۔اورحقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سخت اورتنگ ہونااسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ھدایت الہی سے انحراف کرلیاہے اورہمارے تعیین سرمایہ سوکھ گیاہے۔ہمیں اپنے حالات سے نجات کے لئے اپنی اعتقاد ورفتار پر سوچنا چاہیے اورخدا تعالیٰ سے دنیاوآخرت کی خیروبرکت کاسوال کرناچاہیے۔
خداتعالیٰ ہم سب کو انجام نجیر فرما!
فہرست
سورة الفاتحہ ۳
اسمائے سورہ اور وجہ تسمیہ ۴
خصوصیات سورہ۔ ۵
( ۱) اجما ل قرآن۔ ۵
( ۲) قرآن کا مرادف۔ ۵
( ۳) منفرد لب ولہجہ۔ ۵
( ۴) دعا اور گفتگو کے منفرد انداز کی تعلیم۔ ۵
( ۵) رسول اکرم کے لئے خصوصی اعزاز۔ ۶
( ۶) شیطان کی فریاد کا موجب۔ ۶
( ۷) نماز کا لازمی جز۔ ۶
( ۸) کتاب الہی کا آغاز۔ ۶
( ۹) قرآن میں نازل ہونے والا پہلا سورہ۔ ۶
( ۱۰) آسمانی صحیفوں کا جامع۔ ۷
سورہ حمد کے فضائل ۷
( ۱) اسم اعظم: ۷
( ۲) قرب الہی : ۷
( ۳) دو تہائی قرآن : ۸
( ۴): شفاء : ۸
( ۵) تمام آسمانی کتب کی برکات وثواب۔ ۹
سورہ کے موضوعات۔ ۹
تفسیر آیات ۱۰
۱ ۔خدا شناسی۔ ۱۰
ب استعانت۔ ۱۱
ج اسم خدا۔ ۱۱
( ۶) نماز میں مکرر۔ ۱۲
پہلی آیت کے فضائل ۱۲
( ۱) تمام اعمال پر غالب ہے۔ ۱۳
( ۲) شیطان کی دوری کا موجب۔ ۱۳
( ۳) گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ ۱۳
ب۔تعلیم حمد ۱۵
( ۲) تربیت الہی:۔ ۱۶
الف خدائی پرورش ۱۶
(ب) دیگر ارباب کی نفی ۱۷
( ۳) جہان بینی ۱۷
( ۴) وحدت کلمہ ۱۸
خصوصیات آیت ۱۹
( ۱) تمام انوع حمد کی جامع۔ ۱۹
( ۲) نماز میں الحمدللہ رب عالمین پڑھنا ۲۰
فضائل آیت دوم ۲۱
شکر نعمت ۲۱
خصوصیات۔ ۲۲
سب سے پہلا تکرار ۲۲
الف:استحقاق حمد ۲۲
ب:۔ تربیت کی دلیل۔ ۲۲
(ج)حقیقی مالک اور مجازی مالک میں فرق ۲۳
حاکمیت اعلی۔ ۲۳
الف :۔ ۲۳
ب :۔ ۲۴
معاد ۲۴
الف:۔ آخرت پر ایمان ۲۴
(ب)روز حساب ۲۵
( ۱) عبادت ۲۵
(ب)وہی ذات لائق عبادت ہے ۲۶
(ج)انحصار بندگی ۲۷
خضوع و خشوع ۲۸
ھ۔ خدا کی مر ضی کے مطابق عبادت ۲۹
عبادات کی شرائط اور اقسام ۳۰
احتیاج عبد ۳۲
(ج) عبادت اختیاری ۳۴
اصل خدا ہے ۳۵
عبادت کیوں مقدم ہے ۳۵
لطف حضور ۳۶
( ۲) وحدت کلمہ ۳۶
استعانت ۳۷
الف ضرورت استعانت ۳۷
انحصار استعانت ۳۸
خصوصیات آیت پنجم ۳۸
اولین تکرار لفظ ۳۸
پہلا بلا واسطہ فعل ۳۹
پہلی ضمیر ۳۹
( ۴) پہلا مطلوب الہی ۳۹
( ۵) پہلا اظہار وجود ۴۰
فضائل ۴۰
( ۱) نماز حضرت امام زمانہ میں تکرار ۴۰
( ۱) ھدایت تکوینی ۴۱
( ۲) ہدایت تشریعی ۴۱
دعا ۴۲
( ۳) صراط مستقیم ۴۲
الہی نعمتیں ۴۵
تر بیت الہی ۴۶
مغضوبین کی راہ سے دوری ۴۷
گمراہوں کی راہ سے دوری ۴۸
سورہ بقرہ ۴۹
اسماء وجہ تسمیہ ۴۹
( ۱) بقرہ ۴۹
( ۲) سنام القرآن ۴۹
( ۳) فسطاط القرآن : ۴۹
( ۴) سید القرآن ۵۰
( ۵) سورہ۔ا۔ل۔م: ۵۰
مقام نزول وتعداد آیات ۵۰
خصوصیات سورہ بقرہ ۵۱
( ۴) سب سے زیادہ آیات ۵۱
فضائل سورہ ۵۲
( ۱) افضل ترین سورہ : ۵۲
( ۲) استحقاق رحمت : ۵۲
( ۳) یاد کرنے کا انعام : ۵۳
موضوعات ۵۴
محور بحث،تقوی ۵۴
کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ ۵۵
متقین کی راھنمائی۔ ۵۵
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں تقوی ۵۵
مراتب تقوی ۵۶
قران میں تقوی کی اہمیت۔ ۵۶
ب، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اساس ۵۷
تقوی و آئمہ علیہ السلام ۵۷
تقوی اخلاق کا سردار ہے۔( ۱) ۵۸
تقوی کی علامتیں ۵۸
متقین کی صفات ۵۹
تفسیر آیات ۶۰
تعارف قرآن ۶۳
کتاب ۶۳
معجزہ ۶۴
متقین کی ہدایت ۶۵
پہلا گروہ ۔ متقین ۶۶
غیب پر ایمان ۶۶
ایمان ۶۶
ایمان بالغیب ۶۷
افضل اہل ایمان ۶۹
( ۲) نماز قائم کرنا ۷۰
نماز کے حقوق ۷۰
انفاق فی سبیل اللہ ۷۱
قرآن پر ایمان ۷۳
(الف)قرآن مجید تمام آسمانی کتب کا وارث ہے ۷۳
(ب)آخری کتاب ۷۴
( ۲) سابقہ انبیاء کی کتب پر ایمان ۷۴
وحدت ادیان الہی ۷۴
آخرت کا یقین ۷۵
ہدایت اور کامیابی ۷۷
ایمان اور عمل میں استمرار ۷۷
دوسرا گروہ سرکش کفار۔ ۷۸
شناخت کافر ۷۸
منکر حق ۷۹
ایمان فعل اختیاری ہے ۸۰
کفار کی ضلالت : ۸۰
الف :دلوں اور کانوں پر مہر۔ ۸۱
توبہ و استغفار ۸۲
ب :تشخیص کی قدرت نہیں۔ ۸۳
ج :مستحق عذاب ۸۳
شان نزول ۸۴
تیسرا گروہ : منافقین ۸۴
منافق کی شناخت ۸۴
چال بازی ۸۶
خود فریبی ۸۷
بیمار دل ۸۹
جھوٹ کی سزا ۸۹
فساد فی الارض ۹۰
اصلاح کا دعوی ۹۱
بے شعور مفسد ۹۱
دعوت ایمان ۹۲
مومنین کی تحقیر ان کا شیوا ہے ۹۳
حقیقی بیوقوف ۹۳
شان نزول ۹۴
مومنین کے ساتھ ملاقات کا ریاکارانہ انداز ۹۵
اپنے بزرگوں سے ملاقات کا انداز ۹۶
مومنین کی اہانت ۹۶
مو منین کی حمایت ۹۷
منافقین کا انجام ۱۰۰
(ب)نقصان دہ تجارت ۱۰۱
خصوصیات ۱۰۲
سب سے پہلی مثال : ۱۰۲
ضرب المثل کی اہمیت ۱۰۲
تاریک زندگی ۱۰۳
نور رسالت وامامت سے محروم ۱۰۳
بد ترین مخلوق ۱۰۴
خوف و ہراس پر مشتمل زندگی ۱۰۶
عذاب خدا کا احاطہ ۱۰۶
مضطرب زندگی ۱۰۷
انتخاب ہدایت کی مہلت ۱۰۸
خصوصیات ۱۰۸
پہلا خطاب ۱۰۸
پہلا فرمان الہی ۱۰۹
دعوت عمومی ۱۰۹
عبودیت پروردگار ۱۱۰
الف، معرفت خداوندی ۱۱۰
ب،صحیح عقیدہ ۱۱۱
(ج) احترام اہل بیت علیہم السلام ۱۱۲
خالق اولین و آخرین کی عبادت ۱۱۴
فلسفہ عبادت تقویٰ ہے ۱۱۴
آفرینش کائنات انسان کیلئے ہے۔ ۱۱۵
نعمت زمین ۱۱۵
نعمت آسمان ۱۱۶
شرک کی نفی ۱۱۸
گزشتہ آیات کے ساتھ ربط ۱۱۹
قرآن مجید کا تعارف ۱۲۰
ب عبودیت کا مقام۔ ۱۲۱
قرآن کا چیلنج ۱۲۲
الف۔قرآن مجید تمام شکوک سے پاک ہے ۱۲۲
قرآن ہمیشہ رہنے والا ایک معجزہ ہے ۱۲۴
قرآن کی حقانیت یقینی ہے ۱۲۵
مخالف قرآن جھوٹے ہیں ۱۲۵
الف۔ قرآن کا چیلنج لا جواب ہے ۱۲۶
ب :دعوت ایمان ۱۲۷
ج: اتمام حجت کے بعد انکار کا نتیجہ ۱۲۷
بشارت الہی ۱۲۹
ایمان اور عمل صالح ۱۲۹
بہشت اور اس کی نعمتیں ۱۳۱
الف :بہشت کے باغات ۱۳۱
ب:پاکیزہ بیویاں ۱۳۱
نعمتوں میں دوام و ہمیشگی ۱۳۲
شان نزول ۱۳۳
قرآنی تمثیل ۱۳۴
مچھر کی مثال کیوں ۱۳۴
قرآنی مثالیں اور انسانی رویہ ۱۳۶
ہدایت اور گمراہی ۱۳۶
جبر کی نفی ۱۳۷
( ۱) عہد شکنی ۱۳۸
قطع تعلق ۱۴۰
فساد فی الارض ۱۴۱
فاسق خسارے میں ہیں ۱۴۱
توحید شناسی۔ ۱۴۲
خدا کی سر زنش ۱۴۲
دنیاوی زندگی ۱۴۳
عالم برزخ کی زندگی ۱۴۵
قبر کے سوالات ۱۴۶
عالم آخرت کی زندگی ۱۴۸
عظمت انسان ۱۵۰
نعمت آسمان ۱۵۱
سات آسمان ۱۵۲
علم مطلق خداوند ۱۵۳
نعمت خلافت۔ ۱۵۳
حقیقی خلیفہ کون؟ ۱۵۵
چار خلفاء ۱۵۶
عظمت رسول اعظم۔ ۱۵۸
فساد اور خونریزی۔منافی خلافت ۱۵۹
تقدیس اور تسبیح۔لازمہ خلافت ۱۶۰
لامحدود علم الہی۔ ۱۶۲
علم آدم : ۱۶۴
علم آدم اورخزائن غیب: ۱۶۵
فضیلت آدم۔ ۱۶۷
کیافرشتے سچے نہیں؟ ۱۶۸
خاصان خدا کا انداز گفتگو: ۱۶۹
انسان اورفرشتے میں فرق ۱۷۰
علم معیار خلافت: ۱۷۱
مسجود ملائکہ: ۱۷۴
آیاسجدہ عبادت ذاتی ہے؟ ۱۷۵
حقیقت سجدہ: ۱۷۶
حقیقت ابلیس: ۱۷۸
تشکیل خانوادہ:۔ ۱۸۱
حقیقت جنت: ۱۸۲
د۔ دنیاکی جنت۔ ۱۸۴
انسان مخلوق مختار: ۱۸۴
شیطانی وسوسہ: ۱۸۶
انسانی نسل کا دشمن : ۱۸۸
عارضی قرار گاہ: ۱۸۸
حقیقت توبہ: ۱۹۱
کلمات توبہ :۔ ۱۹۴
ایک سوال اوراسکا جواب ! ۱۹۸
دلیل : ۲ ۱۹۹
دلیل : ۳ ۲۰۰
اھبطواکا تکرارکیوں؟ ۲۰۰
ھدایت کی پیروی :۔ ۲۰۲
ایک سوال اوراسکا جواب ! ۲۰۳
جواب ! ۲۰۳
جہنمی کون؟ ۲۰۴