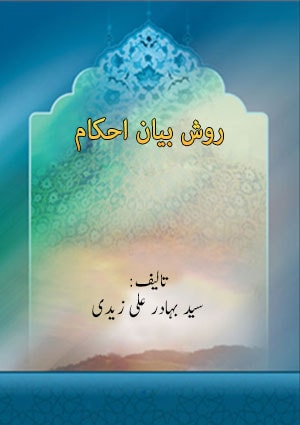یہ کتاب برقی شکل میں نشرہوئی ہے اور شبکہ الامامین الحسنین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں اس کی فنی طورپرتصحیح اور تنظیم ہوئی ہے
روش بیان احکام
تالیف:
سید بہادر علی زیدی
ولایت اکیڈمی سندھ پاکستان
نام کتابٍ:روشِ بیانِ احکام
تألیف: مولانا سید بہادرعلی زیدی قمی
نظر ثانی: حجۃ الاسلام و المسلمین ڈاکٹر سید نسیم حیدر زیدی
کمپوزنگ: سن شائن کمپوزنگ سنٹر
طبع اول: ۲۰۱۴
تعاون:
ناشر: ولایت اکیڈمی سندھ پاکستان
تشکر و امتنان
خداوند عالم کی رحمت کا سلسلہ ازل تا ابد جاری و ساری رہنے والا ہے۔ لائق تحسین ہیں وہ لوگ جو شب و روز دین خدا کی خدمت میں زندگی بسر کررہے ہیں۔
ادارہ ولایت اکیڈمی سندھ پاکستان بھی دین الہی کی خدمت کرنے کا عزم و ارادہ رکھتا ہے لہذا مکتب اہل بیت کی تبلیغ و ترویج میں مصروف عمل ہے اسی عزم و ارادہ کے پیش نظر صاحب قلم حجۃ الاسلام و المسلمین مولانا جناب سید بہادر علی زیدی قمی صاحب کی تالیف کردہ کتاب روش بیان احکام جسے دنیا کی مختلف زبانوں میں کتب نشر کرنے والےبین الاقوامی ادارہ رسالت غدیر نے زیور طباعت سے آراستہ کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ لہذا میں ان تمام افراد کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں بالخصوص رسالت غدیر کے مسئول جناب محمد قربان پور اور ان کے برادرا ن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نیز جناب ہادی منصوری کا مشکور و ممنون ہوں کہ جن کا مسلسل تعاون رہا ہے۔
آخر میں خداوند عالم سے دست بدعا ہوں کہ جن افراد نے اس کتاب کو آپ کے ہاتھوں تک پہنچانے میں کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہے، انکی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
والسلام
شیخ کاظم حسین معصومی
ولایت اکیڈمی سندھ پاکستان
گفتار مقدم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لِلّٰه ربِّ العالَمِین، الحمدُ لِلّٰهِ الواحِدِ الاَحَد، الفَرد الصمد، الذی لم یَلد وَ لَم یولد و لم یکن له کفواً اَحَد و الصلاة علی محمد عبده المجتبی و رسوله المصطفیٰ، اَرسله اِلیٰ کافَّة الوری، بشیراً و نذِیراً و داعیاً اِلیٰ الله باذنه و سراجاً منیراً و علیٰ اهل بیۡتهِ أئمّة الهدیٰ و مصابیح الدجیٰ، الذین اَذهبَ الله عنهم الرجس و طهَّرهم تطهیرا و السلام علیٰ من اتبع الهدیٰ
یوں تو مبلغین حضرات شب و روز احکام اسلامی کی تبلیغ و ترویج میں مصروف عمل ہیں۔ لیکن متعدد مواقع ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ مبلغین حضرات یہ ہیں کہ مسجد میں حاضرین کی تعداد یا نہایت کم ہے یا کم ہوتی جارہی ہے، خصو صاً نوجوانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اس بنا پر وہ مبلغین فکر مند اور پریشان ہوجاتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ اس بحرانی صورت حال کا خاتمہ کیا جاسکے؟
حقیقت یہ ہے کہ ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا بیان کیا جائے؟ کیسے بیان کیاجائے؟ اور مسائل شرعی بیان کرنے کے لئے احکام کو کس طرح تنظیم و ترتیب دیا جائے؟
لہذا اس صورت حال کے پیش نظر خاص اس کتاب کو قلمبند کیا گیا ہے۔
میں مشکور و ممنون ہوں بالخصوص ولایت اکیڈمی سندھ پاکستان کے سرپرست جناب مولانا شیخ کاظم حسین معصومی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کاوشوں کی وجھ سے یہ کتاب آپ کے ہاتھوں تک پہنچے میں دعا کرتا ہو خدا انکی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
امید کرتا ہوں مبلغین حضرات یقیناً اس کاوش سے بہرہ مند ہوں گے۔ آخر میں خداوند عالم سے بحق محمدؐ و آل محمدؑ طالب دعا ہوں کے اہل حق کی نصرت و مدد فرمائے۔
و السلام احقر العباد
بہادر علی زیدی
پہلی نشست
بیان احکام
احکام سیکھنے اور بیان کرنے کی ضرورت و اہمیت
قرآن کریم، علماء و مبلغین کی ذمہ داری کو اِس انداز سے واضح طور پر بیان کر رہا ہے:
( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (۱) ؛
صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لئے نکل پڑیں تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لئے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذاب الٰہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگیں۔
اس آیت کریمہ سے یہ بھی ظاہر ہوجاتا ہے کہ جہاد سے قطع نظر ایک دوسرا سفر بھی واجب ہے کہ جہاد میں نہ جانا ہو تو علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کریں اور واپس آکر اپنی قوم کو تعلیم دیں اور انھیں عذاب الہٰی سے ڈرائیں کہ یہ بھی ایک جہاد ہے اور جہاد ہی کی طرح واجب ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے:
"قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ علیه السلام إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ "(۲)
"میں نے کتاب علی علیہ السلام میں پڑھا ہے کہ خداوند عالم نے جُہلاء سے اس وقت تک علم حاصل کرنے کا عہد نہیں لیا جب تک کہ علماء سے جہلاء کو علم عطاء کرنے کا عہد نہ لے لیا۔ کیونکہ علم، جہل سے پہلے تھا"۔
نیز اکثر فقہاء و مراجع عظام کی توضیح المسائل کے آغاز میں یہ عبارت دیکھنے میں آتی ہے: "جن مسائل کی انسان کو عموماً ضرورت پڑتی ہے ان کا سیکھنا واجب ہے۔(۳) "
تعلیم احکام کی جزاء
پیغمبر اکرم ﷺ سے روایت نقل کی گئی ہے:
" اِنَّما مُعَلِّمَ الْخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَ حِيتَانُ الْبَحْرِ وَ كُلُّ ذِي رُوحٍ فِي الْهَوَاءِ وَ جَمِيعُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ "(۴)
"نیک معلم کے لئے زمین کے چوپائے، سمندر کی مچھلیاں، ہوا میں موجود تمام ذی روح اور بلکہ تمام اہل زمین و آسمان استغفار کرتےہیں"۔
نیز پیغمبر اکرم ﷺ سے روایت نقل کی گئی ہے:
"أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى "(۵)
"یاد رکھوہمارے شیعوں میں سے جو شخص ہمارے علوم سے آشنائی رکھتا ہے اگر وہ ایسے افراد کی ہماری شریعت کی طرف ہدایت کرتا ہے، جنکی رسائی ہم تک نہیں ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کسی یتیم کی اپنے سایہ عاطفت میں سر پرستی کا فریضہ انجام دیا ہو، یاد رکھو جو شخص ایسے افراد کی رشد و ہدایت اور تعلیمِ شریعت کا بندوبست کرے گا وہ ہمارے ساتھ بہترین و برترین مقام و مرتبہ پر ہوگا"۔
تعلیم بغیر علم ممنوع ہے
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپؑ نے فرمایا:
"مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا :اللَّهُ أَعْلَم "(۶)
جو تم جانتے ہو، بیان کردو؛ لیکن جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے کہہ دو کہ خدا بہتر جانتا ہے۔
بلکہ اسی سلسلہ کی بعض روایات میں تو یہ بھی مرقوم ہے کہ صاف کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم۔
"روشِ بیانِ احکام" سیکھنے کی ضرورت
بیشک معارف دین کا ایک خطیر حصہ احکام شرعی اور فقہی مسائل پر مشتمل ہے اور تاریخ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ مدارس و حوزہ ہائے علمیہ میں طلاب کرام کا زیادہ تر وقت فقہ کو سیکھنے اور سمجھنے میں صرف ہو جاتا ہے جو حوزہ ہائے علمیہ کا امتیاز اور ایک بہترین عمل ہے۔
لیکن حصول علم کے بعد دیگر طلاب اور عوام تک منتقل کرنے کا مرحلہ آتا ہے کیونکہ فقہ کو لوگوں کی زندگی مرتب کرنے کے لئے معین کیا گیا ہے لہذا فقہی مسائل سیکھنے کے بعد انھیں عوام تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں تک یہ علوم کس طرح منتقل کئے جائیں؟ کیا اس کے لئے کوئی خاص طریقہ اور روش اختیار کرنی چاہیے۔ یقیناً جواب مثبت ہے۔
لہذا لوگوں کو فقہی تعلیم دینے سے قبل خود طلاب و مبلغین حضرات کو مناسب روش و طریقہ سیکھنا چاہیے کیونکہ مبلغان علوم اسلامی و مروّجان احکام کے تجربات کی روشنی میں یہ امر مسلم ہے کہ تبلیغ میں صرف فقہ کا سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ مبلغ کو بہترین روش سے بھی آشنا ہونا چاہیے۔
ذیل میں دیئے گئے چند سوالات کے ذریعے روش بیان احکام سیکھنے کی ضرورت واضح ہوجاتی ہے،مثلاً
۱. درس احکام سے لوگوں کی دوری کی وجہ کیا ہے؟
۲. عام طور پر درس احکام خستہ کنندہ کیوں ہوتا ہے؟
۳. درس احکام کو کس طرح جذّاب و دلچسپ بنایا جاسکتا ہے؟
۴. بچوں اور نوجوانوں کے لئے کون سے مسائل بیان کرنے چاہئیں؟
۵. مختلف افراد خصوصاً بچوں کے لئے مسائل بیان کرنے کا کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟
۶. لوگوں کو کس طرح احکام سیکھنے کی طرف متوجہ کیا جائے؟
۷. مراجع عظام کے فتاویٰ میں تفاوت کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور ایسی صورت میں کس مرجع کے مسائل بیان کرنا چاہئیں؟
۸. فقہ کی مشکل اصطلاحات اور پیچیدہ عبارات کس طرح عوام کے سامنے بیان کی جائیں؟
۹. فلسفۂ احکام کے بارے میں سوالات کے کس طرح جوابات دیئے جائیں؟
۱۰. اپنے اندر جواب دینے کی مہارت کس طرح پیدا کی جائے؟
۱۱. مسائل پر کس طرح تسلط حاصل کیا جائے، کس طرح مطالعہ کیا جائے کہ مسائل کی جزئیات تک ذہن میں محفوظ رہ جائیں؟
۱۲. احکام کو بہترین منظم اور تقسیم کرنے کا طریقہ اور روشن کیا ہے؟
سوالات
۱. قرآن و سنت کی روشنی میں احکام سیکھنے اور بیان کرنے کی اہمیت و ضرورت بیان کریں؟
۲. دوسروں کو احکام سکھانے کا کیا فائدہ ہے؟
۳. بغیر علم، بیان کرنے کے بارے میں معصوم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟
۴. روش بیان احکام سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
____________________
۱ ۔سورہ توبہ (۹)، آیت ۱۲۲۔
۲ ۔اصول کافی، ج۲، ص ۶۱۳؛ بحار ، ج۲، ص ۶۷۔
۳ ۔توضیح المسائل، امام خمینیؒ، مسئلہ ۱۱۔
۴ ۔بحار، ج۲، ص ۱۷۔
۵ ۔بحار، ج۲، ص ۲۔
۶ ۔اصول کافی، ج۱، کتاب فضل العلم، باب نہی القول بغیر علم۔
دوسری نشست
پہلا باب: بیان احکام کی تیاری کے مراحل
دریچہ:
جو شخص احکام شرعی بیان کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو دینی احکام کی تعلیم دینا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ پہلے خود مسائل سے بھرپور آشنائی حاصل کرے یعنی مسائل بیان کرنے سے قبل اچھی طرح مسائل سمجھ لینا چاہئیں اور اپنی علمی سطح مضبوط و مستحکم کرنی چاہیے۔
علمی سطح کے استحکام و بھرپور آشنائی کے بعد چند مراحل پیش نظر رہنے چاہئیں جو مختلف صنف سے تعلق رکھنے والے افراد کے لئے مسائل بیان کرنے کے لئے نہایت ضروری ہیں لہذا ضروریات سے ہماری مراد یہ ہے کہ "کیا بیان کیا جائے؟، کون سے مطالب و مسائل بیان کرنے چاہئیں؟"
لہذا بیان احکام کی آمادگی و تیاری کے لئے مندرجہ ذیل مراحل طے کرلینا ضروری ہیں:
۱. انتخاب موضوع بحث؛
۲. انتخاب شدہ موضوع بحث کا بغور اور کامل مطالعہ؛
۳. منتخب شدہ موضوع بحث سے مختلف مسائل کا انتخاب؛
۴. مناسب تقسیم بندی؛
۵. خلاصہ نویسی
۶. خلاصہ کا مطالعہ۔
انتخاب موضوع بحث
احکام بیان کرنے سے پہلے موضوع بحث منتخب کرنا ضروری ہے مثلاً تقلید، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد وغیرہ۔ لیکن موضوع بحث منتخب کرتے وقت مندرجہ ذیل نکات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔
۱ ۔ عوام کی ضرورت
موضوع منتخب کرتے وقت لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے کہ منتخب شدہ موضوع آپ کے مخاطبین کی ضرورت ہے یا نہیں؟
۲ ۔ فہم افراد:
اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ جو احکام و مسائل ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ مخاطبین کے لئے قابل فہم ہیں یا نہیں۔ اگر ایسے مسائل بیان کریں جو ان کی سمجھ سے بالا ہوں یا کچھ مسائل سمجھیں اور کچھ نہ سمجھیں تو بیان کا فائدہ کیا رہ جائے گا؟
۳ ۔ مقررہ وقت:
یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس کتنا مقرر وقت موجود ہے۔ اگر مقرر وقت قلیل ہو اور ایسے میں طویل فقہی بحث شروع کردی جائے تو بالکل غیر مناسب اور مشکل ساز ہوجائے۔ لہذا مقررہ وقت کی مناسبت سے موضوع کو ترتیب دینا چاہیے۔
حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے:
"إِنَّ رَأيَكَ لَا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شيءٍ ففرغهُ لِلمُهم "۔(۷)
"بیشک جو کچھ تمہاری نظر میں ہے، وہ سب بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے تو صرف مہم پر اکتفا کرلینا بہتر ہے"۔
مولائے کائنات کے اس فرمان کی روشنی میں مقررہ وقت کی طرف خاص توجہ رکھنا چاہیے اور اس وقت صرف اہم مسائل کا سہارا لینا چاہیے اور بقیہ مسائل کو دیگر اوقات پر موکول کردینا بہتر ہے۔
نیز مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے:
"لَا تَقُلۡ مَا لَمۡ تَعۡلَم "
وہ بات مت کہو جو تم جانتے نہیں ہو؛ یعنی جاہلانہ گفتگو سے پرہیز کرو اور عالمانہ گفتگو کرو۔
پس عالمانہ گفتگو کے لئے بھرپور اور مکمل مطالعہ کرنا ضروری ہے۔
پھر آنجناب ؑ فرماتے ہیں:
"وَ لَا تَقُلۡ کُلُّ مَا تَعۡلَم "(۸) ؛ جو کچھ جانتے ہو سب کا سب بیان مت کرو۔
یعنی گفتگو یقیناً عالمانہ ہونی چاہیے لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ موقع محل اور مخاطب دیکھ کر کلام کرنا چاہیے، ہر بات ہر جگہ اور ہر کس و ناکس کے سامنے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ حاضرین کی ضرورت کو دیکھ کر موضوع منتخب کرنا چاہیے، بیان شدہ مطالب حاضرین کی سمجھ میں آرہے ہیں یا نہیں اور دامن وقت میں گنجائش ہے یا نہیں؟
معیار ضرورت
لوگوں کی ضرورت و احتیاج کے مطابق گفتگو کرنا تبلیغ کے مسلم اصول میں سے ایک اصول ہے۔ لہذا ذہن میں فوراً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت و احتیاج کو کس طرح سمجھا جائے یعنی کون سے مسائل و احکام مخاطبین کی ضرورت ہیں اور کون سے مسائل کی انھیں ضرورت نہیں ہے پس ان کی ضرورت کو سمجھنے کے لئے چند مددگار عوام ذیل میں پیش کئے جا رہے ہیں:
۱ ۔ عمر؛ احکام بیان کرنے میں مخاطبین کی عمر کا خیال رکھنا بیحد مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے بچوں کے لئے الگ مسائل بیان کئے جائیں، نوجوانوں کے لئے ان کی ضرورت کے مطابق اور بزرگوں کے لئے ان کی شایانہ شان مسائل بیان کرنے چاہئیں۔
۲ ۔ صنف مخاطب؛ بیان احکام میں صنف مخاطب کا علم بھی ایک مؤثر عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لڑکے لڑکیوں اور خواتین و حضرات کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں اور کچھ اِن سے مخصوص اور کچھ اُن سے مخصوس ہیں مثلاً طہارت، نماز اور حج وغیرہ میں کچھ مسائل صنف نازک سے مخصوص ہیں جنکی مرد حضرات کو ضرورت پیش نہیں آتی ہے لہذا مردوں کے لئے اس قسم کے مسائل بیان کرنا نہ صرف مفید نہیں بلکہ کبھی کبھی ان کے لئے باعث اذیت و خستگی قرار پائے گا۔ پس مسائل بیان کرتے وقت مخاطبین کی صنف کا خیال رکھنا بیحد ضروری اور مفید ہے۔
۳ ۔ مکانِ مخاطب؛مسائل بیان کرتے وقت مکان مخاطب یعنی لوگوں کے محل زندگی اور علاقے کا خیال رکھنا بھی ایک بہترین عامل کی حیثیت رکھتا ہے مثلاً بعض احکام و مسائل گاؤں ، دیہات کے رہنے والوں کے لئے بیحد ضروری ہوتے ہیں جبکہ شہریوں کے لئے ممکن ہے بالکل غیر ضروری ہوں اور کبھی انھیں ان مسائل کی ضرورت پیش نہ آئے۔ مثلاً کراچی یا اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں رہنے والے نوجواں کے لئے نجاست خور اونت کے پسینے کی نجاست کا مسئلہ بیان کرنا چاہئیے یا نہیں کہ ممکن ہے وہ زندگی بھر اونٹ ہی نہ دیکھ پائے۔ نیز غیر اسلامی ملکوں میں رہنے والے افراد بہت سے ایسے مسائل سے دچار ہوتے ہیں کہ ممکن ہے اسلامی ملکوں میں رہنے والوں کو کبھی ان کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پس مخاطبین کے محل وقوع کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔
۴ ۔ زمان مخاطب؛ احکام کے بیان کرنے میں وقت و زمانہ کا خیال رکھنا بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے مثلاً ایک وقت تھا کہ جب شطرنج کے مسائل آج کی طرح نہ تھے کیونکہ کل تک سب اسے حرام سمجھتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب موضوع تبدیل ہوجاتا ہے تو اس کے مسائل بھی تبدیل ہوجاتے ہیں آج شطرنج ذہنی ورزش اور کھیل میں تبدیل ہوچکی ہے اسے بعض فقہاء نے ہار جیت کی شرط کے بغیر جائز قرار دیا ہے۔
ایک دور تھا جب فقط انگشت شمار افراد ہی اعتکاف کے لئے مساجد کا رخ کرتے تھے جبکہ آج ہزاروں افراد اعتکاف کی سعادت سے شرفیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں لہذا وہ اعتکاف کے مسائل جاننا چاہتے ہیں پس آج اعتکاف کے مسائل بیان کرنے کی خاص ضرورت پیش آتی ہے۔
گذشتہ دور میں نماز مسافر کے مسائل زیادہ پیش نہ آتے تھے کیونکہ لوگ کمی کے ساتھ سفر کرتے تھے لیکن آج کل لوگوں کی زندگی میں سفر کثرت سے داخل ہوچکا ہے لہذا اس کے مسائل بھی بیان کرنے کی ضرورت کثرت سے پیش آتی ہے۔
نیز نئی نئی اشیاء مثلاً موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ گذشہ زمانہ میں لوگوں کے پاس نہ تھے لیکن آج کل یہ تمام وسائل عوام کی دستر س میں موجود ہیں لہذا احکام بیان کرتے وقت "زمانہ" کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے ورنہ لوگوں پر فقہ کی افادیت ظاہر نہ ہوسکے گی۔
اگر آج فقط چند عمومی مسائل و احکام بیان کرنے پر اکتفاء کیا جائے گا تو نہ صرف یہ کہ یہ عصر حاضر کے لئے مفید ثابت نہ ہوں گے بلکہ جدید مسائل میں اپنی تکلیف شرعی سے نابلد رہ جائیں گے لہذا "زمانہ" نے لوگوں کی ضرورت کو تبدیل کردیا ہے۔
۵ ۔مخاطبین کا مشغلہ؛ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ احکام شرعی کی دو قسمیں ہیں مشترک اور مخصوص۔ تقلید، طہارت، نماز، روزہ وغیرہ کے مسائل تقریباً تمام مخاطبین و مکلفین میں مشترک ہوتے ہیں اور سب کے لئے یہ مسائل بیان کئے جاتے ہیں لیکن زراعت، مساقات، مضاربہ ، اجارہ اور وکالت وغیرہ کے مسائل عام مکلفین کو درپیش نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کے مشغلہ کے اعتبار سے ان کی ضرورت پیش آتی ہے۔
مثلاً اگر نرسنگ ڈے Nursing day پرگفتگو کرنے کا موقع ملے اور مبلغ نرسوں سے خطاب کے دوران اگر کچھ شرعی احکام بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے نرسنگ سے مخصوص مسائل بیان کرنے چاہئیں۔ لہذا اگر ان کے شعبہ سے متعلق مسائل بیان کرے گا تو اس کی گفتگو خاطر خواہ مؤثر ثابت ہوگی۔
اسی طرح اگر انجینئرز کے مجمع میں ان سےمتعلق مسائل، ڈاکٹرز کے اجتماع میں ان سے متعلق مسائل، تجارت کے مجمع میں تجارت کے مسائل اور پولیس یا فوج کے درمیان ان سے متعلق مسائل بیان کرنے چاہئیں۔
نکتہ:
اب جبکہ ہمنے بیان احکام میں مؤثر عوامل جان لیئے ہیں تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان عوامل کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کی جائے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس مقام پر احکام بیان کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں تو پہلے وہاں رہنے والے کسی معتبر اور ذمہ داری شخص یا میزبان سے چند سوالات کے جوابات دریافت کرلینے چاہئیں۔ مثلاً:
۱. مخاطبین کی تعداد کتنی ہے؟
۲. مخاطبین کی صنف کیا ہے (مرد یا خواتین، لڑکے یا لڑکیاں یا مشترک)
۳. ان کی عمر کیا ہے؟
۴. ان کا مشغلہ کیا ہے؟
۵. ان کی سطح علمی کیا ہے؟
۶. نشست کی مناسبت کیا ہے؟
۷. آپ کے لئے کتنا وقت مقرر کیا گیا ہے؟
ان کے مطابق درس مرتب کرکےمسائل بیان کرنے چاہئیں۔
معیار فہم
پس احکام بیان کرنے کے لئے پہلے لوگوں کی ضرورت، ان کے فہم اور مقررہ وقت کے مطابق موضوع منتخب کرنا چاہیے۔
ہم نے لوگوں کی ضرورت معلوم کرنے کے لئے تفصیل سے نکات پیش کئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کا فہم و ادراک کس طرح معلوم کیا جائے؟
عام طور پر دو عوامل یعنی عمر اور علمی سطح کو لوگوں کے فہم وادراک کا معیار قرار دیا جاتاہے یعنی نوعمر اور کم علم افراد کے مقابلے میں پکی عمر اور تعلیم یافتہ افراد بہتر مسائل سمجھنے کی صلاحیت رکھتےہیں۔ مثلاً یونیورسٹی اور پرائمری اسکول کے بچوں کے فہم و ادراک میں یقیناً فرق پایا جاتا ہے۔
سوالات
۱. احکام بیان کرنے سے پہلے کن مراحل کا طے کرنا ضروری ہے؟
۲. موضوع منتخب کرتے وقت کن نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟
۳. مخاطبین کی ضرورت معلوم کرنے میں مؤثر عوامل کیا ہیں؟
____________________
۷ ۔غرر الحکم، ح ۳۶۳۸۔
۸ ۔من لا یحضرہ الفقیہ، ج۲، ص ۲۴، ح ۳۲۱۵۔
تیسری نشست
مکمل و بغور مطالعہ
شرعی احکام و مسائل بیان کرتے وقت مبلغ میں خود اعتمادی کا عنصر ہونا بیحد ضروری ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ امتحان کے موقع پر بعض افراد خود اعتمادی نہ ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں اور نتیجتاً امتحان میں ناکام ہوجاتے ہیں۔
کیا آپ نے سوچا کہ انسان میں یہ خود اعتمادی کس طرح پیدا ہوتی ہے؟
اگر انسان امتحان دیتے وقت یا احکام بیان کرنے سے پہلے یا تقریر کرنے سے پہلے بھرپور، مکمل اور بغور مطالعہ کرچکا ہو تو یقیناً اس میں یہ خود اعتمادی پیدا ہوجاتی ہے۔
حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے:
"فَكِّر ثُم تكلّم تَسلمُ من الزّلل "(۹)
"اگر انسان بغور مطالعہ کے بعد کلام کرے گا تو خطاء و لغزش سے محفوظ رہے گا"
لہذا کلام سے پہلے مکمل اور بغور مطالعہ کرلینا ضروری ہے مثلاً اگر ہم تقلید کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتےہیں تو ہمیں درج ذیل صورت میں مطالعہ کرلینا چاہیے:
۱. تقلید کی تعریف،
۲. تقلید کی ضرورت،
۳. تقلید کی اقسام (صحیح تقلید جیسے نما ز وغیرہ، غلط تقلید جیسے توحید، معاد)
۴. تقلید کی شرعی دلیل،
۵. شرائط تقلید،
۶. مجتہد اور اعلم کی پہچان کا طریقہ،
۷. شرائط مجتہد
۸. مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنے کا طریقہ،
۹. مجتہد کے فتویٰ کا دائرہ کار (احکام میں ہے، موضوعات میں نہیں)
۱۰. مرجع کا تبدیل کرنا وغیرہ۔
مبلغ میں خود اعتمادی کے علاوہ لوگوں کا بھی مبلغ پر اعتماد ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر لوگ مبلغ پر اعتماد نہ کریں گے تو اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل بھی نہ کریں گے، نتیجتاً ہماری ساری کوشش بے ثمر ہوکر رہ جائے گی۔
عام طور پر مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنے کے چار مندرجہ ذیل طریقے بیان کئے جاتےہیں:
۱. خود مجتہد سے سننا،
۲. مجتہد کے رسالہ عملیہ (توضیح المسائل) میں دیکھنا،
۳. دو عادل افراد سے سننا،
۴. ایسے شخص سے سننا جو مورد اطمینان اور سچا ہو۔
آج کل مجتہد کا فتویٰ دریافت کرنے کے یہی دو طریقے عام طور پر رائج ہیں:
اول: توضیح المسائل میں دیکھنا،
دوم: ایک مورد اطمینان شخص سے سننا۔
لہذا جب مبلغ تبلیغ کے سلسلہ میں مختلف علاقوں میں جاتا ہے تو لوگ اسی کی زبانی مجتہد کے فتوے دریافت کرکے عمل انجام دیتے ہیں۔
پس اگر مبلغ پر لوگوں کا اعتماد قائم نہ ہوگا تو نہ وہ اس کی بات سنیں گے اور نہ ہی عمل کر سکیں گے اور یہ اعتماد اس وقت قائم ہوسکتا ہے جب مبلغ مکمل اور بھرپور مطالعہ کرکے لوگوں کے سوالات کے صحیح اور اطمینان بخش جواب دے سکے۔
مکمل مطالعہ کے علاوہ بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے کیونکہ بغور مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے بیان احکام میں اشتباہ کریں گے جس کے نتیجے میں مخاطبین بھی اپنے عمل میں اشتباہ کرنے لگیں گے۔ فقہی کتب کا مطالعہ بعض تاریخی اور کہانی کی کتابوں کی طرح سرسری و طائرانہ نظر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بغور مکمل مطالعہ کرکے مسائل بیان کرنے چاہئیں۔
ہم ذیل میں چند ایسی مثالیں پیش کر رہےہیں کہ بغور مطالعہ نہ کیا جائے تو ہم اشتباہ کردیں گے، مثلاً
۱ ۔ اگر کوئی شخص از روئے فراموشی غسل جنابت انجام نہ دے یا عورت غسل حیض کرنا بھول جائے اور اسی حالت میں کچھ روزے رکھ لے اور بعد میں متوجہ ہو تو کیا ان روزوں کی قضاء ہوگی یا نہیں؟ اگر عمداً غسل نہیں کیا تو حکم کیا ہوگا؟ اگر از روئے فراموشی ایسا ہوا ہے تو حکم کیا ہے؟ اگر چند دن کے بعد متوجہ ہو تو وظیفہ کیاہوگا؟ ان تمام صورتوں میں حکم الگ الگ ہوگا لہذا مبلغ کو بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔(۱۰)
۲ ۔ اگر مہمانوں میں سے کسی کو کھانے کی نجاست معلوم ہوجائے تو کیا دیگر مہمانوں کو بتانا ضروری ہے یانہیں؟"اسے ہرگز نہیں بیان کرنا چاہیے" یا "اس پر بیان کرنا لازم نہیں ہے"۔
جی ہاں اسے دیگر مہمانوں کو بتانا ضروری نہیں ہے لیکن اگر میزبان کو معلوم ہوجائے کہ کھانا نجش ہے تو مہمان کو بتانا ضروری ہے کیونکہ مہمانوں کو کھانا کھلانے میں مہمان کا دخل نہیں ہے جبکہ میزبان کا دخل ہوتا ہے اور کھانے میں اور کھلانے میں فرق پایا جاتا ہے۔ جس مہمان کو علم ہوگیا ہے کہ غذا نجس ہے اسے یقیناً کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن میزبان کے لئے کھانا کھلانے کا مسئلہ درپیش ہے اور دوسروں کو نجس غذا کھلانا حرام ہے۔
لیکن مہمان پر بیان کرنا واجب کیوں نہیں ہے؟ کیا نجس غذا کھانا حرامنہیں ہے اور اگر کوئی شخص حرام انجام دے رہا ہو تو کیا اسے اس حرام سے روکنا نہیں چاہیے؟! یہ بھی انہیں موارد میں سے ہے کہ جہاں انسان مکمل اور بغور مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے اشتباہ کر بیٹھتا ہے۔
یاد رہے کہ نہی از منکر وہاں ضروری ہے کہ جب کوئی شخص منکر کا ارتکاب کر رہا ہو۔جب مہمان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ کھانا نجس ہے اور وہ اسے پاک سمجھ کر استعمال کر رہا ہے تو گویا اس نے کوئی حرام کام ہی انجام نہیں دیا ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص عدم علم کی بنا پر نجس لباس میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی تو اسے نہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پس تمام مہمانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔(۱۱)
۳ ۔ پیروں کے مسح کے بارے میں درج ذیل دو عبارتوں پر غور کیجئے:
الف: دائیں پیر کا مسح بائیں پیر کے مسح سے پہلے انجام دینا چاہیے۔
ب: بائیں پیر کے مسح کو دائیں پیر کے مسح سے پہلے انجام نہیں دینا چاہیے۔
بغور پڑھیئے اور دیکھئے کہ کون سی عبارت درست اور کون سی نادرست ہے؟
دوسری عبارت کے مطابق اگر دونوں پیروں کا مسح ایک ساتھ آن واحدمیں انجام دیا تو مسح صحیح رہے گا جبکہ پہلی عبارت کے مطابق مسح درست نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ میں اختلاف فتویٰ بھی پایا جاتا ہے، بعض فقہاء کہتے ہیں کہ ایک ساتھ مسح کرنے میں کوئی ا شکال نہیں جبکہ بعض کہتے ہیں کہ اشکال ہے۔(۱۲)
انتخاب احکام
بیان احکام کے لئے ہم نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے اس کا مکمل اور بغور مطالعہ کرنے کے بعد لوگوں کی ضرورت، ان کے فہم و فراست، زمان و مکان اور مقررہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اہم مسائل انتخاب کرنے چاہئیں جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے:
"إِنَّ رَأيَكَ لَا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شيءٍ فَفَرِّغهُ لِلمُهم "(۱۳)
بیشک جب تمہارے ذہن میں جو کچھ ہے وہ بیان کرنے کی فرصت نہیں تو فقط مہم پر اکتفاء کرلینا بہتر ہے۔
سوالات
۱. مکمل اور بغور مطالعہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟
۲. مکمل اور بغور مطالعہ کی ایک ایک مثال بیان کریں؟
۳. اگر مہمان کو معلوم ہوجائے کہ کھانا نجس ہے تو کیا اسے دیگر مہمانوں کو بتانا ضروری ہے یا نہیں، کیوں؟
۴. انتخاب موضوع و احکام کے لئے حضرت علیعلیہ السلام کی کس روایت سے استفادہ کیا جاتا ہے؟
____________________
۹ ۔فہرست غرر ، ص ۳۱۵۔
۱۰ ۔توضیح المسائل مراجع، م ۱۶۱۹۔
۱۱ ۔توضیح المسائل مراجع، م ۱۴۳۔ ۱۴۵۔
۱۲ ۔تحریر الوسیلہ، ج۱، ص ۲۸۔
۱۳ ۔غرر الحکم، ح ۳۶۳۸۔
چوتھی نشست
احکام کی تنظیم و تقسیم بندی ۱
یقیناً بہترین و برترین کلام وہی ہوتا ہے جس سے خواص بھی بہرہ مند ہوں اور عوام بھی استفادہ کرسکیں۔
حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے:
"أَحۡسَنُ الكلامِ مَا زَانَهُ حُسنُ النظام و فَهِمَهُ الخاص و العام "(۱۴) ۔
بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو منظم ہو اور اسے خاص و عام سمجھ سکیں۔
پس حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے واضح ہوتا ہے کہ مفید و بہترین کلام وہی ہوتا ہے جس سے خاص لوگوں کے علاوہ عام لوگ بھی بہرہ مند ہوسکیں۔
نیز آنجنابؑ کے اس فرمان سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ کلام منظم و مرتب ہونا چاہیے، کیونکہ جو مسائل و احکام ہم مخاطبین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اگر انھیں منظم و مرتب کرکے مناسب تقسیم بندی کرلی جائے تو یقیناً لوگوں کے لئے سمجھنا آسان ہوجائے گا ، اور یاد رہے کہ بیان احکام کا اوّلین مقصد لوگوں کا سمجھنا ہے اور پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے۔
لہذا اگر ہم مسائل انتخاب کرنے کے بعد ان کی مناسب تقسیم بندی کریں تو ہم خود بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتے ہیں اور مخاطبین بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور انھیں یاد رکھ سکتے ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منتخب شدہ مسائل کو کس طرح منظم کیا اور ان کی تقسیم بندی کے لئے کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔
ہم یہاں تنظیم بندی و تقسیم بندی کے چند طریقے پیش کر رہے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:
۱ ۔نموداری یا درختی ۲ ۔ سوالی
۳ ۔ عنوانی ۴ ۔ ترکیبی
٭روش نموداری یا درختی
منتخب شدہ مسائل کو متعارف نمودار یا درختی انداز پر منظم اور تقسیم کرنا ہے یعنی کُل اس طرح کو اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ تقسیم کرتے کرتے ہم کُل سے آخری مطلوبہ جُز تک پہنچ جائیں۔مطالب کی یہ تقسیم بندی عام و نسبتاً آسان سمجھی جاتی ہے اور بعض مقامات پر زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔
٭ روش سوالی
اس روش کے مطابق ہم منتخب شدہ مطالب کو مختلف سوالات کے قالب میں ڈھالتے ہیں اور اس طرح ان کی منطقی ترتیب و تنظیم سے آراستہ کرکے خود ان کے جوابات فراہم کرتے ہیں۔
٭روش عنوانی
اس روش کے مطابق ایک مخصوص عنوان منتخب کرکے مختلف ابواب میں اس سے متعلق مسائل تلاش کرکے مطالب کو منظم و مرتب کیا جاتا ہے مثلاً احکام لباس وغیرہ۔
٭روش تلفیقی
درحقیقت روش تلفیقی الگ سے کوئی مخصوص روش نہیں ہے بلکہ گذشتہ تین روشوں کا باہمی ملاپ ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک نشست میں ہم مطالب بیان کرنے کے لئے تینوں روشوں سے بیک وقت استفادہ کرلیں۔ مثلاً کسی موضوع کے بارے میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز سوالی روش سے کریں اور پھر چند سوالات پیش کرنے کے بعد نموداری اور درختی روش سے استفادہ کریں۔
روش نموداری یا درختی
گذشتہ مطالب کے بہتر فہم و تعلم کے خاطر روش نموداری یا درختی کے مطابق احکام کی تقسیم بندی کی ایک دو مثالیں بطور نمونہ پیش کی جا رہی ہیں:
خمس
خمس سات چیزوں پر واجب ہے:
۱. وہ نفع جو کسب (کارو بار) سے حاصل ہو،
۲. معدن (کان)،
۳. گنج (خزانہ)،
۴. جب حلال مال، حرام سے مل جائے،
۵. وہ جواہرات جو دریا میں غوطہ لگانے سے ہاتھ آئیں،
۶. جنگ میں مال غنیمت،
۷. وہ زمین جو کافر ذمی نے مسلمان سے خریدی ہو۔
ان سات موارد میں سے اکثر معاشرے کے لوگوں کے لئے جو مورد ابتلاء ہے وہ منفعت کسب ہے یعنی لوگ تجارت، صنعت اور مختلف کام کاج کرکے جو منافع حاصل کرتے ہیں اس پر واجب ہونے والا خمس ہے اور کیونکہ اس کے مسائل چندان مشکل بھی سمجھے جاتے ہیں اس لئے یہاں صرف منفعت کسب کی تقسیم بندی پیش کی جا رہی ہے۔
خمس واجب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے لوگوں کے اموال کی تین قسمیں ہیں:
۱. وہ اموال جن پر قطعا خمس واجب ہے،
۲. وہ اموال جن پر قطعا خمس واجب نہیں ہے،
۳. مشکوک اموال یعنی جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ ان پر خمس واجب ہوا ہے یا نہیں۔
پہلی قسم (وہ اموال جن پر قطعا خمس واجب ہے)
۱ ۔ سرمایہ، ۲ ۔ زائد بر مخارج روزمرہ، ۳ ۔ سالانہ بچت۔
۱ ۔ سرمایہ و کسب؛ وہ اصلی مال جو درآمد کے لئے بطور سرمایہ اور منبع استعمال کیا جائے جیسے دکان، آلات، کھیتی باڑی کے آلات، زراعت کی زمین، سلائی کا سامان، ویلڈنگ کا سامان، کارخانہ، ٹرک، بس اور ٹیکسی وغیرہ وغیرہ۔
۲ ۔ زائد بر مخارج روزمرّہ؛یعنی وہ اشیاء صرف جو انسان دوران سال زندگی بسر کرنے کے لئے خریدتا ہے اور وہ تمام یا ان کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے جیسے چاول، گھی، آٹا، چینی، پتی اور دالیں وغیرہ۔
زندگی بسر کرنے کے لئے عام طور پر انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اسے اصطلاح میں مؤونہ کہتے ہیں (یعنی ضروریات زندگی) اور اس کی دو قسمیں ہیں:
۱ ۔ اشیاء صرف،
۲ ۔ اشیاء غیر صرف۔
اشیاء صرف سے مراد وہ اشیاء ہیں جو استعمال کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی رہتی ہیں جیسے آٹا، چینی، پتی، گھی ،دالیں وغیرہ۔ اگر استعمال کرتے کرتے ان اشیاء میں سے سال کے آخر میں کچھ بچ جائے تو ان پر خمس واجب ہوگا۔
اشیاء غیر صرف سے مراد وہ اشیاء ہیں جو سال بھر استعمال ہونے کے باوجود باقی رہتی ہیں جیسے مکان جس میں سالہا سال رہتا ہے لیکن پھر بھی باقی رہتا ہے اسی طرح قالین، ریفریجریٹر، ٹی وی، کمپیوٹر، گاڑی وغیرہ بھی ہیں۔ جو شخص پابندی سے خمس کا حساب کتاب رکھتا ہے اگر وہ سالانہ مخارج میں سے یہ اشیاء مہیا کرتا ہے تو ان پر خمس نہیں ہے لیکن جس نے کبھی خمس کا حساب نہیں کیا اور مشکوک ہو تو ان اشیاء کے سلسلہ میں مصالحہ کرنا پڑے گا۔
۳ ۔ سالانہ بچت؛ یعنی وہ نقدی رقم جو انسان قناعت کی وجہ سے اپنی سالانہ آمدنی میں سے بچا لیتا ہے چاہے اس نے وہ رقم اپنے پاس رکھی ہو یا بینک وغیرہ میں محفوظ کی ہو، یہاں تک کہ اگر اس نے وہ رقم کسی کو بطور قرض دی ہو۔
دوسری قسم (وہ اموال جن پر خمس نہیں ہے)
۱ ۔ ارث، ۲ ۔ دیت، ۳ ۔ ہبہ، ۴ ۔ شہریہ، ۵ ۔ مہر، ۶ ۔ جہیز۔
۱ ۔ ارث؛ جو چیز انسان کو بطور میراث ملتی ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے مگر یہ کہ اسے یقین ہو کہ مالک نے اس مال کا خمس ادا نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر ہم جانتے ہوں کہ مالک خمس کا پابند تھا یا اس نے اس مال کا خمس ادا کردیا تھا یا ہمیں نہیں معلوم کہ اس مال پر خمس واجب ہوا تھا یا نہیں تو ایسی صورت میں خمس واجب نہیں ہوگا۔
۲ ۔ دیت؛ جو چیز انسان کو بطور دیت حاصل ہوتی ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے۔
۳ ۔ ہبہ؛ جو چیز انسان کو بخش دی جاتی ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ مثلاً انعام و اکرام، عیدی، سوغات اور تحفہ وغیرہ۔
۴ ۔ مہر؛ عورت کو جو رقم بطور مہر ملتی ہے اس پر خمس نہیں ہے۔
۵ ۔ شہریہ؛ حوزہ علمیہ اور مدارس و یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلاب کو بطور شہریہ و وظیفہ جو رقم ملتی ہے اس پر خمس نہیں ہے۔
۶ ۔ جہیز؛ اگر جہیز کی اشیاء بیٹی کو بخش دی جائیں تو ہبہ شمار ہوتی ہیں اور ان پر خمس نہیں ہوگا۔
نکتہ
مذکورہ بالا موارد میں اختلاف فتویٰ بھی پایا جاتا ہے لہذا خمس کا حساب کرتے وقت ا س بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ خصوصاً ہبہ کے بارے میں بہت سے فقہاء کی نظریہ ہے کہ اگر سال بھر استعمال نہ ہو تو اس پر خمس واجب ہے۔
تیسری قسم (اموال مشکوک)
گھر کی جن اشیاء غیر صرف کے بارے میں علم نہ ہو کہ ان پر خمس واجب ہے یا نہیں یعنی معلوم نہ ہو کہ یہ اشیاء مخمس رقم سے خریدی ہیں یا غیر مخمس رقم سے تو ان میں مصالحت کرنا پڑے گی یعنی فقیہ یا اس کے نمائندے سے رضایت لینا پڑے گی۔
مسئلہ کی وضاحت کے لئے اس مثال پر غور کیجئے۔
مثلاً عادل کی طرف احمد کی کچھ رقم ہے اور دونوں واجب الاداء رقم کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن مقدار دونوں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے اور کسی صورت نہ رقم کی مقدار انھیں یاد آتی ہے اور نہ ہی معلوم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں صرف مصالحت ہی راہِ حل ہے۔ یعنی ایک دوسرے کو کسی بھی مخصوص مقدار کی ادائیگی پر راضی کرلیں۔
خمس میں بھی ایک طرف طلبگار ہے اوردوسری طرف وہ شخص ہے جس پر واجب الاداء ہے۔ طلبکار ارباب خمس ہوتا ہے اور عصر غیبت میں فقہاءِ جامع الشرائط ارباب خمس قرار پاتے ہیں۔ اور چونکہ مرجع تقلید فرداً فرداً ہر شخص سے مصالحت نہیں کرسکتے ہیں لہذا وہ اپنے نمائندے معین کرتے ہیں جو ان کی جانب سے اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بغیر مصالحت اموال مشکوک میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔
اگرچہ خمس کے مسائل مذکورہ مقدار سے یقینا بہت زیادہ ہیں لیکن اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے اور نموداری روش سمجھانے کے لئے اسی مقدار پر اکتفاء کیا جا رہا ہے۔
مسائل خمس کی نموداری تنظیم و تقسیم بندی
۱ ۔ سرمایہ کسب
جن پر خمس واجب ہے ۲ ۔ زائد بر مخارج روز مرّہ (اشیاء صرف)
۳ ۔ سالانہ بچت
۱ ۔ ارث
۲ ۔ دیت
اموال جن پر خمس واجب نہیں ۳ ۔ ہبہ
۴ ۔ شہریہ
۵ ۔ مہر
۶ ۔ جہیز
مشکوک اموال گھریلو اشیاء غیر صرف جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ مخمس رقم سے خریدی ہیں یا غیر مخمس رقم سے۔ ان کو مصالحت کرنا پڑے گی۔
وضو جبیرہ کے احکام
وہ چیزیں جن سے زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو باندھا جائے اور وہ دوائی جو زخم وغیرہ پر لگائی جائے اُسے "جبیرہ" کہتے ہیں۔
معمولاً جن افراد کو وضو جبیرہ کرنا پڑتا ہے ان کا زخم یا ٹوٹا ہوا عضو یا ان اعضاء میں سے ہوتا ہے جنہیں وضو میں دھونا پڑتا ہے جیسے چہرہ اور ہاتھ، یا ان اعضاء میں سے ہوتا ہے جن پر مسح کیا جاتا ہے جیسے سر اور پاؤں، ان دونوں کے احکام جدا ہیں اور بعض مسائل میں جزئی تفاوت بھی پایا جاتا ہے۔ ذیل میں وضو جبیرہ کے احکام کی نموداری و درختی تقسیم بندی پیش کی جا رہی ہے۔
زخم، پھنسی یا شکستگی(۱۵)
۲ ۔ مسح مضر نہیں عضو مسح کھلا ہے تو معمول کے مطابق وضو کرے گا۔
عضو مسح بند ہے۔ اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر معمول کے مطابق وضو کرے ورنہ وضو جبیرہ کرے گااور بنا بر احتیاط واجب تیمم بھی کرے گا۔
اسی طرح ہم فقہ کے مختلف ابواب میں سے احکام و مسائل منتخب کرکے مناسب تنظیم و ترتیب اور ان کی تقسیم بندی کرسکتے ہیں مثلاً توضیح المسائل میں نماز آیات کے اگرچہ عام طور پر دو ہی عناوین بیان کئے جاتے ہیں اول: "نماز آیات" دوم" "نماز آیات کا طریقہ" لیکن ہم انھیں اپنی سہولت کے لئے مختلف عناوین میں تقسیم کرکے تنظیم و ترتیب دے سکتے ہیں۔ مثلاً
۱. وجوب نماز آیات کے اسباب و عوامل،
۲. نماز آیات کا وقت،
۳. نماز آیات کی کیفیت،
۴. جن افراد پر نماز آیات واجب ہے وغیرہ وغیرہ۔
سوالات
۱. احکام کس طرح ذہن میں محفوظ رہ سکتے ہیں اور انھیں کس طرح لوگوں کے سامنے کے لئے آسان بنایا جاسکتا ہے؟
۲. احکام کی تنظیم و تقسیم بندی کے لئے حضرت علی علیہ السلام کے کس فرمان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے؟
۳. احکام کی تنظیم بندی کس طرح کی جاسکتی ہے اور متداول تقسیم بندی کون سی ہے؟
۴. مؤنہ (ضروریات زندگی) کی کتنی قسمیں ہیں اور کس پر خمس واجب ہوتا ہے؟
۵. اعضائے وضو پر زخم یا شکستگی ہونے کے باوجود مکلف کے لئے کس صورت میں معمول کے مطابق وضو کرنا ضروری ہے؟
____________________
۱۴ ۔غرر الحکم، ح ۳۳۰۴۔
۱۵ ۔تحریر الوسیلہ، ج۱، ص ۳۴، فصل فی الوضو الجبیرہ، توضیح المسائل، م ۳۲۴ تا ۳۲۹۔
پانچویں نشست
احکام کی تنظیم و تقسیم بندی ۲
سوالی تنظیم و تقسیم بندی
کیا آپ نے اس بات کے بارے میں سوچا ہے کہ لوگوں میں احکام سیکھنے اور اس قسم کے درس میں شرکت کرنے کا جذبہ کس طرح بیدار کیا جاے اور ان میں شوق و ترغیبت کا عنصر پیدا کیا جائے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لوگوں میں کسی چیز کی ضرورت کا احساس پیدا کر دیا جائے تو یقیناً وہ اس کی افادیت و ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس کے حصول کی جستجو کرتے ہیں مثلاً اگر کسی کو اس بات کا ا حساس ہوجائے کہ انگلش وقت کی ضرورت ہے ا ور اس کے بغیر بہترین ڈاکٹر، انجینئر، سائنس دان وغیرہ بننا ممکن نہیں ہے تو وہ یقیناً اس کے لئے جستجو کرتا ہے۔ انسان بہت سے کام صرف احساس بیدار ہونے کی بنیاد پر ہی انجام دیتا ہے۔
یاد رہے کہ سوال انسان میں احساس بیدار کرنے کا بہترین و مؤثر عمل ہے۔ مثلاً جب کسی سے سوال کرتے ہیں تو فوراً سوچتا ہے کہ اس کا جواب معلوم ہے یا نہیں؟ لہذا اس درس میں ہم احکام کو سوالی روش کے مطابق تنظیم و ترتیب دیتے ہوئے ان کی مناسب تقسیم بندی کریں گے۔
وضو
۱. واجبات وضو کیا ہیں؟
۲. وضو میں چہرے کی کتنی مقدار دھونا واجب ہے؟
۳. وضو میں ہاتھوں کی کتنی مقدار دھونا واجب ہے؟
۴. چہرہ یا ہاتھ کسی بھی انداز سے دھو لینا کافی ہے؟
۵. چہرہ اور ہاتھ کا کتنی مرتبہ دھونا واجب ہے؟
۶. سر کا مسح کتنی مقدارمیں واجب ہے؟
۷. کیا بالوں میں مسح کرنا صحیح ہے؟
۸. پاؤں کے مسح کی مقدار (لمبائی اور چوڑائی) کتنی ہے؟
۹. جوراب اور جوتے پر مسح کرنا کیسا ہے؟
۱۰. وضو کے کتنے طریقے ہیں؟
۱۱. وضو کی شرائط کیا ہیں؟
۱۲. کن چیزوں کے لئے وضو کرنا ضروری ہے؟
۱۳. کن چیزوں سے وضو باطل ہوجاتا ہے؟
جوابات
۱ ۔ واجبات وضو، نیت کے ساتھ منہ اور ہاتھ دھوئے جائیں اور سر کے اگلے حصے اور پاؤں کے اوپر والے حصے میں مسح کیا جائے۔ ( )
۲ ۔ چہرے کا طول پیشانی کے اوپر والے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک اور عرض میں چہرے کا جتنا حصہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان آجائے دھونا واجب ہے۔(۱۶)
۳ ۔ ہاتھوں کو کہنیوں سے لیکر انگلیوں کے سروں تک دھونا واجب ہے۔(۱۷)
۴ ۔ چہرہ اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے اور اگر اوپر سے نیچے کی طر دھویا جائے تو وضو باطل ہے۔(۱۸)
۵ ۔ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کو ایک دفعہ دھوناو واجب ، دوسری مرتبہ مستحب اور تیسری مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ دھونا حرام ہے۔(۱۹)
۶ ۔ مسح کی جگہ پیشانی کے مد مقابل سر کا چوتھائی حصہ ہے اور اس حصہ کی جس جگہ پر مسح ہوجائے کافی ہے۔ اگر احتیاط مستحب یہ ہے کہ لمبائی میں ایک انگلی اور چوڑائی میں ملی ہوئی تین انگلیوں کے برابر ہو۔(۲۰)
۷ ۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو صحیح ہے لیکن اگر بال چہرے پر آپڑیں یا (ایک جگہ کے بال دوسری جگہ پہنچ جائیں تو جلد پر مسح کرنا ضروری ہے۔(۲۱)
۸ ۔ کسی ایک انگلی کے سرے سے لیکر پاؤں پر ابھری ہوئی جگہ تک لمبائی میں مسح کرے اور چوڑائی جتنی مقدار بھی ہو کافی ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ تین ملی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پورے پاؤں کا مسح کیا جائے۔(۲۲)
۹ ۔ جوراب اور جوتے پر مسح کرنا باطل ہے، ہاں اگر سخت سردی یا چور اور درندہ وغیرہ کے خوف سے جوراب یا جوتا نہیں اتار سکتا تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے اور اگر جوتے کا اوپر کا حصہ نجس ہو تو پھر اس پر کوئی پاک چیز ڈال کر اس کے اوپر مسح کیا جائے۔(۲۳)
۱۰ ۔ وضو دو طرح سے انجام دیا جاسکتا ہے، ترتیبی اور ارتماسی۔(۲۴)
۱۱ ۔ شرائط وضو مندرجہ ذیل ہیں۔(۲۵)
۱. پانی پاک ہو،
۲. پانی مطلق ہو،
۳. پانی مباح ہو،
۴. پانی کا برتن بھی مباح ہو،
۵. پانی کا برتن سونے چاندی کا نہ ہو،
۶. اعضاء وضو دھونے اور مسح کرتے وقت پاک ہونے چاہئیں،
۷. وضو اور نماز کے لئے وقت کافی ہو،
۸. وضو کو قصد قربت سے انجام دے،
۹. ترتیب کے مطابق انجام دے،
۱۰. موالات کا خیال رکھے،
۱۱. افعال وضو خود انجام دے،
۱۲. پانی کے استعمال سے کوئی چیز مانع نہ ہو مثلاً بیماری،
۱۳. پانی کے وضو کے عضو تک پہنچنے سے کوئی امر مانع نہ ہو مثلاً میل وغیرہ۔
۱۲ ۔ چھ چیزوں کے لئے وضو کرنا چاہیے۔(۲۶)
۱. نماز میت کے علاوہ تمام واجب نمازوں کے لئے،
۲. بھولا ہوا سجدہ اور تشہد اگر اس کے اور نماز کے درمیان کوئی حدث مثل پیشاب وغیرہ کے سرزد ہوجائے،
۳. خانہ کعبہ میں واجب طواف کے لئے،
۴. اگر نذر، عہد یا قسم کھائے کہ میں وضو کروں گا،
۵. قرآن کے حروف کو مس کرنے کے لئے،
۶. نجس شدہ قرآن کو پاک کرنے یا بیت الخلاء سے نکالنے کے لئے جبکہ مجبور ہو کہ اس کا ہاتھ قرآن کے حروف سے مس ہوجائے گا۔
۱۳ ۔ وضو کو باطل کرنے والی چیزیں سات ہیں۔(۲۷)
۱. پیشاب،
۲. پاخانہ،
۳. وہ ریح جو مقام پاخانہ سے خارج ہو،
۴. وہ نیند جو آنکھوں اور کانوں پر غالب آجائے،
۵. وہ چیزیں جو عقل کو زائل کردیتی ہیں مثلاً دیوانگی، مستی، بے ہوشی،
۶. خون استحاضہ
۷. وہ کام جس کی وجہ سے غسل کرنا پڑتا ہے جیسے جنابت۔
اسی طرح مختلف سوالات پیش کرکے ان کے جوابات دیتے جائیں اور جہاں وضاحت کی ضرورت محسوس کریں، وضاحت بھی کریں اور دوران وضاحت مزید سوالات پیش کرکے ان کے جوابات دے سکتے ہیں۔
سوالات
۱. لوگوں میں احکام سیکھنے اور درس احکام میں شرکت کرنے کا احساس کس طرح پیدا کیا جاسکتا ہے؟
۲. فقہی مباحث میں کسی بھی موضوع کو منتخب کرکے سوالی روش کے مطابق تنظیم و ترتیب دیں۔
____________________
۱۶ ۔توضیح المسائل، م۲۳۶۔
۱۷ ۔ توضیح المسائل، م ۲۳۷۔
۱۸ ۔ توضیح المسائل، م ۲۴۵۔
۱۹ ۔ توضیح المسائل، م ۲۴۳۔
۲۰ ۔ توضیح المسائل، م ۲۴۸۔
۲۱ ۔ توضیح المسائل، م ۲۵۰۔
۲۲ ۔ توضیح المسائل، م ۲۵۱۔
۲۳ ۔ توضیح المسائل، م ۲۵۲، ۲۵۳۔
۲۴ ۔ توضیح المسائل، م ۲۵۹۔
۲۵ ۔ توضیح المسائل، م ۲۳۶و ۲۶۱۔
۲۶ ۔ توضیح المسائل، م ۲۶۵ تا ۲۹۸۔
۲۷ ۔توضیح المسائل، م ۳۱۶۔
چھٹی نشست
احکام کی تنظیم و تقسیم بندی ۳
عنوانی تنظیم و ترتیب
احکام کی عنوانی تنظیم سے مراد یہ ہے کہ چند جذاب اور مبتلا بہ عناوین منتخب کریں اور مختلف فقہی مباحث میں سے ان سے مربوط مسائل جمع کرلیں مثلاً بطور نمونہ ہم یہاں لباس اور لڑکے اور لڑکیوں کے روابط کے بارے میں مسائل پیش کر رہے ہیں۔
احکام لباس
اگرچہ عام طور پر فقہی کتب میں احکام لباس کا عنوان بیان نہیں کیا گیا ہے لیکن کتبِ اخلاق میں لباس پہننے کے آداب اور فقہی کتب میں نمازی کے لباس کے احکام بیان کئے جاتے ہیں۔
پس لباس کے احکام کو مندرجہ ذیل عناوین میں تقسیم کرتے ہیں۔
۱. نمازی کا لباس،
۲. عام لباس،
۳. لباس احرام،
۴. لباس آخر (لباس میت)۔
آخری دو عناوین صرف مخصوص افراد کے لئے بیان کئے جاتے ہیں۔
نمازی کے لباس کی شرائط(۲۸)
۱ ۔ پاک ہو،
۲ ۔ مباح ہو،
۳ ۔ مردار کا جزو نہ ہو،
۴ ۔ حرام گوشت جانور کے اجزاء سے نہ ہو،
۵ و ۶ ۔ نمازی مرد ہے تو خالص ریشم و سونے کے تاروں سے بُنا ہوا نہ ہو۔
عام لباس (لباس حجاب)
یعنی عام طور پر بدن چھپانے کے لئے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔
۱ ۔ مباح ہو، یعنی انسان یا اس لباس کا خود مالک ہو یا اس لباس کے استعمال کا اسے اختیار حاصل ہو۔ (لباس نماز اور لباس حجاب دونوں کا مباح ہونا شرط ہے)۔
۲ ۔ لباس بدن کی مقدار واجب کو چھپا سکتا ہو، خواتین کے لئے تمام بدن کا چھپانا واجب ہے البتہ وضو میں جتنا چہرہ دھونا واجب ہے اور کلائی تک ہاتھ چھپانا واجب نہیں ہے۔
۳ ۔ لباس شہرت نہ ہو، یعنی ایسا لباس جس کا رنگ یا سلائی کڑھائی لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچے اور لوگوں کی انگشت نمائی کا سبب بن جائے۔
۴ ۔ صنف مخالف کا لباس نہ ہو، یعنی مرد کے لئے جائزنہیں ہے کہ وہ مخصوص زنانہ لباس پہنے اور اسی طرح عورت کے لئے لیے مخصوص مردانہ لباس پہننا جائز نہیں ہے مثلاً چادر خواتین کا مخصوص لباس ہے اسی طرح شیروانی مردوں کا مخصوص لباس ہے، نیز ہیل والی شوز خواتین کا لباس ہے۔
۵ ۔ ایسا باریک لباس نہ ہو جس میں سے بدن جھلکتا ہو۔
۶ ۔ لباس ہیجان آور نہ ہو، ایسا لباس پہننا جس کی وجہ سے لوگوں کی نازیبا نگاہیں اس کی طرف کھنچ جائیں مثلاً بعض چست لباس، بعض رنگ یا کم لباس وغیرہ۔
۷ ۔ کافروں کا مخصوص لباس نہ ہو، جیسے صلیب کا نشان، ٹائی وغیرہ۔
لڑکے لڑکیوں کے باہمی روابط
آج کل کے جذاب و مبتلا بہ موضوعات میں سے ایک لڑکے اور لڑکیوں کے باہمی روابط ہیں اور ان کے احکام پانچ قسموں میں تقسیم کئے جا رہے ہیں:
۱ ۔ خیال؛ کسی نا محرم کو دل و دماغ میں لانا، اس کے بارے میں سوچنا اور اس کا عاشق و دیوانہ ہونا،
۲ ۔ گفتگو؛ یعنی نامحرم سے روبرو گفتگو کرنا، فون پر گفتگو کرنا یا چیٹنگ کرنا،
۳ ۔ تحریر؛ خط و کتابت اور SMS کرنا،
۴ ۔ دیدار؛ ایک دوسرے کو دیکھنا،
۵ ۔ مس؛ یعنی ایک دوسرے کو مس کرنا مثلاً ہاتھ ملانا وغیرہ۔
ذیل میں ہر ایک کے احکام بیان کئے جا رہے ہیں۔
٭ خیال؛ مندرجہ ذٰل شرائط کے ساتھ ذہنی رابطہ میں اشکال نہیں ہے۔
۱. جنسی شہوت کا سبب نہ ہو؛
۲. بہ قصد لذت نباشد؛
۳. فساد کا باعث نہ ہو۔
٭گفتگو اور تحریر ؛ان دونوں کے احکام مشترک ہیں اور مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔
۱. ردّ و بدل ہونے والے مطالب حرام و مبتذل نہ ہوں،
۲. جنسی شہوت کی تحریک کا باعث نہ ہوں،
۳. فساد کا باعث نہ ہوں۔
٭دیدار ؛دیداری رابطہ سے مراد وہی "نگاہ کرنے کے احکام" ہیں جنکی تفصیلات توضیح المسائل وغیرہ میں درج ہیں۔
٭مس؛ یعنی بدن کے کسی بھی حصہ کا نامحرم سے مس کرنا چاہے لذت کی غرض سے نہ ہو اور اسی طرح چاہے ہیجان آور بھی نہ ہو۔
اسی طرح مختلف اصناف سے متعلق عناوین تیار کرکے ان کے مسائل تنظیم کرسکتے ہیں۔ مثلاً درزی کے احکام، ہیئر ڈریسنگ کے احکام، وڈیو میکر کے احکام، نرسنگ کے احکام، ڈاکٹرز اور علاج و معالجہ کے احکام وغیرہ۔
اگر ان شعبوں سے متعلق مسائل جمع کرکے بیان کئے جائیں تو یقیناً جذاب اور قابل توجہ قرار پائیں گے۔
تلفیقی تنظیم و ترتیب
تلفیقی تنظیم و ترتیب درحقیقت دو مختلف شعبوں سے بیک وقت استفادہ ہے مثلاً کسی بھی موضوع کو منتخب کرکے سوال سے شروع کریں اور پھر نموداری روش سے استفادہ کریں یا ایک مخصوص عنوان منتخب کرکے پھر نموداری روش سے استفادہ کریں جیسا کہ ہم نے عنوانی تنظیم میں کیا ہے کہ عنوان سے شروع کیا ہے اور پھر نموداری روش سے استفادہ کیا ہے۔
خلاصہ نویسی اور اس کا مطالعہ
نسخہ برداری و خلاصہ نویسی کلاس کے اصولوں میں سے ہے لیکن یہ سوال درپیش ہے کہ احکام شرعی میں کس طرح خلاصۃ نویسی قلم بند کی جائے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ احکام کی خلاصہ نویسی نموداری روش کے مطابق کریں یا کلی سوالات منتخب کئے جائیں یا جن مسائل کے فراموش ہونے کا اندیشہ ہو انھیں یاد داشت کے طور پر بطور خلاصہ تحریر کرلینا چاہیے۔
یاد داشت نویسی و خلاصہ نویسی کے بعد انھیں پھر ایک بار بغور مطالعہ کرلینا چاہیے، اس طرح ذہن میں مطالب محفوظ رہ جائیں گے اور تبلیغ کے موقع پا انسان گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔
سوالات
۱. لباس نماز و حجاب کی مشترک شرائط کیا ہیں؟
۲. نامحرم کے ساتھ گفتاری و تحریر روابط کی کیا شرائط ہیں؟
۳. کسی ایک جذاب عنوان کو منتخب کرکے اس کی تقسیم بندی کیجئے۔
۴. خلاصہ نویسی کا ضابطہ اور فائدہ بیان کریں؟
____________________
۲۸ ۔توضیح المسائل، م ۳۲۳۔
ساتویں نشست
تقسیم بندی پر ایک نظر
ڈاکٹر سے مربوط احکام کی تقسیم بندی
ذیل میں ڈاکٹرز سے مربوط احکام کی مختلف تقسیم بندی پیش کی جارہی ہے۔
۱ ۔ ڈاکٹر کے مشترک احکام
۲ ۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز سے مربوط احکام
۳ ۔ اعضائے بدن کے احکام
۴ ۔ طبابت سے مربوط مشاغل کے احکام
ہم یہاں پر فقط ڈاکٹرز کے مشترک احکام کی نموداری تقسیم بندی و جدول پیش کر رہے ہیں۔
۱ ۔ معائنہ و علاج
۲ ۔ معائنہ فیس وغیرہ
معائنہ علاج ۱ ۔ نگاہ و مس کرنا
۲ ۔ علاج اور تجویز دوا
۳ ۔ ڈاکٹر کا ضامن ہونا یا نہ ہونا
۴ ۔ ڈاکٹر کی نظر کی حیثیت
٭نگاہ و مس ۱ ۔ مریض کے بدن کو دیکھنا اور مس کرنا
۲ ۔ مریض کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا
٭علاج اور تجویز دوا
۱ ۔ حلال چیزوں سے علاج جائز ہے
علاج حرام پر منحصر نہیں ہے حرام ہے
۲ ۔ حرام اشیاء سے علاج
علاج حرام پر منحصر ہے حرام نہیں
۳ ۔ ایسی چیز سے علاج جس سے قطعی ضرر واقع ہو مثلاً زندگی بچانے کے لئے ہاتھ یا پاؤں کا کاٹنا جائز ہے
ملحقات ۱ ۔ مقدار استفادہ از حرام؟ بمقدار ضرورت جائز ہے
۲ ۔ حفظ جان بیمار؟ واجب ہے
۳ ۔ بیمار کی موت میں جلدی؟ جائز نہیں ہے
٭ڈاکٹر (معالج) کا ضامن یا غیر ضامن ہونا
۱ ۔ ڈاکٹر کے ضامن ہونے کے موارد
۱ ۔ اگر ڈاکٹر اپنے ہاتھ سے آپریشن نہ کرے یا دوا نہ دے بلکہ فقط دوا کی توصیف بیان کرے تو ضامن نہیں ہے
۲ ۔ اگر براہ راست خود آپریشن کرے
۱ ۔ اگرعلاج میں خطا کرے ضامن ہے ، چاہے مہارت رکھتا ہو۔
۲ ۔ اگر مہارت علمی و عملی رکھتا ہو توضامن ہے چاہے مریض کی اجازت سے علاج کرے یا بغیر اجازت۔
۳ ۔ علمی مہارت رکھتا ہے
۱ ۔ اگر بیمار یا اس کے ولی کی اجازت سے علاج کرے تو مالی نقصان کا ضامن ہے۔
۲ ۔ اگر بغیرت اجازت انجام دے تو ضامن ہے۔
۳ ۔ معمولاً اورمتعارف علاج میں بعید نہیں کہ ڈاکٹر ضامن ہو
۲ ۔ جن موارد میں ڈاکٹر ضامن نہیں (رفع مسئولیت)
۱ ۔ اگر مریض بالغ و عاقل نہ ہو تو ولی کی اجازت معتبر ہے
۲ ۔ اگر مریض بالغ و عاقل ہوتو خود اس کی اجازت معتبر ہے اگرچہ موت کا سبب بن جائے۔
۳ ۔ مریض بالغ و عاقل لیکن کامل العقل نہ ہو۔
مریض کی اجازت صرف اس حد تک معتبر ہے کہ موت کا سبب نہ بنے۔
ولی کی اجازت اگرچہ موت کا سبب بنے معتبر ہے۔
٭ڈاکٹر کی نظر کی حیثیت
اسے ہم سوالی تنظیم کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔
روزہ: س: کیا ڈاکٹر کے کہنے اور اس کی تشخیص کی بنا پر روزہ افطار کرنا جائز ہے؟
ج: روزہ کھولنے میں عام عاقل مکلفین کا یقین، گمان یا احتمال کافی ہے اگرچہ ڈاکٹر کی نظر اس کے برخلاف ہو۔
اثبات ِموت:
س:کیا ڈاکٹر کی تشخیص پر کسی کو دفن کرنا جائز ہے؟
ج: اگر ڈاکٹر کے کہنے پر موت کا یقین حاصل ہوجائے تو دفن جائز ہے۔
ڈاکٹر کی معائنہ فیس
اسے بھی سوالی تنظیم کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔
س: کیا علاج کے لئے معائنہ فیس لینا جائز ہے؟
ج: اگرچہ علاج واجب ہے لیکن اس کے باوجود فیس لینا جائز ہے۔
س: کتنی فیس لینا جائز ہے؟
ج: اگر آپریش وغیرہ سے قبل فیس معین کی گئی تھی تو اتنی ہی ادا کرنا ہوگی اور اگر معین نہیں کی گئی یا باہمی موافقت نہیں کی گئی تو اجرت المثل ادا کرنا ہوگی۔
ضمان کی عنوانی تنظیم: مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد جن مواردمیں ضامن ہوتے ہیں تنظیم عنوانی کی صورت میں ایک جھلک میں پیش کئے جا رہے ہیں اگرچہ ضامن ہونے کے موارد بہت زیادہ ہیں:
ڈاکٹر اگر علمی و عملی مہارت سے عاری ہو یا اپنے فریضہ میں کوتاہی کرے تو قطعا ضامن ہے مثلاً انسان کے انجکشن کے بجائے گھوڑے کا انجکشن لکھ دے۔
میڈیکل اسٹور اگر غفلت و کوتاہی کی بنا پرغلط دوا دیدے تو ضامن ہوگا۔
ڈسپنسر اگر غلط انجکشن یا ڈرپ لگا دے تو ضامن ہے۔
اگر پولیس کسی کو اس طرح مارے کہ اس کے بدن پر ضرب لگ جائے تو ضامن ہے۔
اگر چالان کی دھمکی دیکر کسی سے ناحق پیسے وصول کریں توپولیس والا اس رقم کا مالک نہیں ہوسکتا اور وہ اسم رقم کا ضامن رہے گا۔
اگر پولیس وغیرہ No Parking سے کسی کی گاڑی کسی دوسری جگہ منتقل کریں تو گاڑی پر وارد ہونے والے نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔
اگرعمارت میں دونمبر مصالحہ استعمال کریں اور عمارت گر جائے تو نقصان کے ذمہ دار ہیں
اگر آٹھ گھنٹے کے بجائے چار گھنٹے کام کریں تو ضامن ہوں گے۔
اگر مسافر حضرات بس وغیرہ کی سیٹوں کو خراب کریں تو نقصان کے ذمے دار ہوں گے۔
اگر مسافر ٹرین وغیرہ میں سے بلب وغیرہ غائب کرکے لے آئیں تو ضامن ہوں گے۔
آٹھویں نشست
دوسرا باب: کیفیت بیان
پہلی فصل: ضروریات
یہاں ضروریات سے مراد ایسے اصول اور روشیں ہیں ، جن کا احکام بیان کرتے وقت خیال رکھنا ضروری ہے۔
الف: اصول
اصول اول۔ سادہ گوئی
یہ شریعت ، شریعت سہلہ ہے اور اسے احکام قابل فہم ہیں خود پروردگار عالم کا ارشاد پاک ہے( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) (۲۹) "اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کردیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے"۔
پس پیچیدہ اور مشکل الفاظ کے بجائے اسے سادہ اور آسان زبان ہی میں بیان کرنا چاہیے۔ ہم اس سے قبل حضرت علی علیہ السلام کا فرمان نقل کرچکے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں: "بہترین کلام وہی ہے جو منظم ہو اور اسے خاص و عام بآسانی سمجھ لیں"۔
حضور سرور کائناتﷺ نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا: "یَسِّرۡ وَلَا تُعَسِّر "(۳۰) آسان کرو ان پر سختی نہ کرو۔
حضور ؐ نے معاذ کو یمن کا حاکم، ولی یا گورنر بنا کر نہیں بھیجا تھا بلکہ انھیں مبلغ کی حیثیت سے وہاں اعزام کیا تھا اور آنحضرتؐ کا مقصد ظاہراً تبلیغ دین تھا یعنی تبلیغ دین میں ایسی روش اور طریقہ کار اپناؤ کہ جس کے ذریعے لوگوں کے لئے دین سمجھنا مشکل نہ رہے یعنی وہ دین کو مشکل اور سخت نہ سمجھیں۔ پس ہمیں بھی احکام بیان کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم احتیاط واجب کو احتیاط مستحب یا واجب کو مباح کہہ دیں۔ بلکہ مطالب اتنے آسان اور سادہ کرکے بیان کرنے چاہئیں کہ مخاطبین بآسانی سمجھ لیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:
"أَحۡسَنُ الكلام ما لا تَمَجُّهُ الآذان وَ لَا يُتۡعِبُ فَهۡمُهُ الأفهام "(۳۱) ۔
"بہترین کلام وہ ہے جو گوش نواز اور قابل فہم ہو"۔
یاد رہے کہ ہم احکام کو دو چیزوں کے ذریعے مخاطبین کے لئے آسان اور قابل فہم بنا سکتے ہیں:
(الف) غیر ضروری ناموس الفاظ و اصطلاحات سے اجتناب۔
(ب) چھوٹے اور رواں جملوں کا استعمال۔
سالہا سال مدارس میں پڑھتے پڑھتے اور اپنے ہم جماعت طلاب وغیرہ کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے کرتے علمی و فقہی اور فنی اصطلاحات ہماری زبان اوور روزمرہ محاورہ کا حصہ بن جاتی ہیں لیکن عوام کے اکثر افراد ان چیزوں سے نا آشنا ہوتے ہیں لہذا جب ہم اپنے درس اور تقریر وغیرہ میں یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو عوام کے لئے خاطر خواہ قابل استفادہ نہیں ہوتیں لہذا ہم درس دینے کے لئے چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کرنے اور غیر ضروری ناموس الفاظ و اصطلاحات سے اجتناب کی باقاعدہ مشق کرنی چاہیے۔
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم قرآنی و روائی اور علمی اصطلاحات سے بالکل دوری اختیار کرلیں اور انھیں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں! بلکہ صرف ایسی اصطلاحات جو غیر مانوس اور غیر ضروری ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔
ہمارے بزرگ فقہاء بھی اسی ر وش سے استفادہ کرتے ہیں اور توضیح المسائل میں ایسے الفاط و اصطلاحات بیان کرنے کی بجائے دوسرے الفاظ سے استفادہ کرتے ہیں مثلاً: صلاۃ کے بجائے نماز اورصوم کے بجائے روزہ استعمال کرتے ہیں نیز فقاع کے بجائے آب جو۔
فریضہ = واجب
بیع و شرع = خرید و فروش وغیرہ
بعض اصطلاحات و الفاظ عربی ہونے کے باوجود ان کو اسی صورت میں استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ لوگ ان سے مانوس ہوتے ہیں جیسے وضو، غسل، نماز ظہر و عصر، خمس و زکات وغیرہ۔
بعض اصطلاحات اور کلمات ایسے ہوتے ہیں اگرچہ مخاطبین ان سے نا آشنا ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے یعنی اگر اہم یہ الفاظ استعمال نہ کریں تو ان کا بدل پیدا نہ کرسکیں گے جیسے غسل کا بدل نہیں ہے اور اگر ہم اس کا بدل بنا بھی لیں تو ممکن ہے وہ اس کے معنی و مفہوم کو کما حقہ بیان نہ کرسکے۔
ذیل میں ایسی ہی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں:
حد ترخّص، حد نصاب، وقف، وصیت، استحالہ، تبعیّت۔
پس فقہی اصطلاحات و لغات کی تین قسمیں ہیں:
۱ ۔ اصطلاحات و لغات مانوس: ایسی لغات و اصطلاحات جن سے مخاطبین آشنا اور مانوس ہوتے ہیں اور ان کے معنی و مفہوم کو خاطر خواہ سمجھتے ہیں جیسے نماز ظہر و نماز عصر ، خمس و زکات وغیرہ۔
۲ ۔ اصطلاحات و لغات نامانوس لیکن ضروری: ایسی اصطلاحات و لغات جن سے مخاطبین نا آشنا ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا استعمال ضروری ہوتا ہے جیسے حد ترخص اور حد نصاب وغیرہ۔
۳ ۔ اصطلاحات و لغات نامانوس و غیر ضروری: یعنی ایسی اصطلاحات و لغات جن سے مخاطبین مانوس نہیں ہوتے اور ان کے لئے ان کا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے جیسے: استحالہ، شارع مقدس، قصد انشاء، جلالہ، تذکیہ، مسکرات، محجور، موجر، راہن، بایع ومشتری، جہرو اخفات، ثمن و مثمن، ربح سال، نقدین، عصیر عنبی، اکل و شرب وغیرہ۔
لیکن یاد رہے کہ اگر مخاطبین کی علمی سطح بلند ہے اور اس قسم کی اصطلاحات کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں یا اگر ان اصطلاحات کے معنی بیان کئے جائیں اور مخاطبین کے لئے اکتاہٹ کا باعث نہ ہو تو آہستہ آہستہ یہ اصطلاحات استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
چھوٹے چھوٹے اور رواں جملوں سے استفادہ
علمی نقطۂ نظر سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مخاطبین کے لئے چھوٹے اور مختصر جملے سمجھنا آسان ہوتا ہے اور جلد ہی ان کے ذہن نشین ہوجاتے ہیں۔ یہاں بطور مثال ایک فقہی مسئلہ اصطلاحات سے پُر پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے اور رواں جملوں میں تبدیل کرکے پیش کریں گے توجہ فرمایئے:
"اگر حیوان کی اوداج اربعہ، مستقبلاً الی القبلہ، بذریعہ آہنی آلہ، بوسیلہ یدِ مسلمان اور ذکر اسم جلالہ کے ہمراہ کاٹا جائے تو حلال ورنہ حرام ہے"۔
اس قسم کی گفتگو طلاب اور صاحبان علم کے لئے توضیح اور مناسب ہے لیکن عوام کے لئے عام طور پر قابل فہم و استفادہ نہیں ہے اس لئے کہ اگر پورے مسئلہ میں وہ ایک اصطلاح بھی سمجھنے سے قاصر رہا تو حکم بیان کرنے کا مقصد حاصل نہ ہوسکے گا لہذا اسی مسئلہ کو مندرجہ ذیل طریقے سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے:
اگر جانور کو مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ ذبح کیا جائے تو حلال ہے ورنہ حرام ہوگا:
۱. چاروں معروف رگیں مکمل طور پر کاٹ دی جائیں،
۲. ذبح کرتے وقت حیوان کا گلا اور اگلا حصہ قبلہ کی طرف ہو،
۳. لوہے سے بنی ہوئی چیز سے ذبح کیا جائے،
۴. ذبح کرنے والا مسلمان ہو (چاہے مرد ہو یا عورت)،
۵. ذبح کے وقت اللہ کا نام یعنی "بسم اللہ" کہا جائے۔
اسی طرح ہم دیگرمفصل مسائل کو چند مختصر مسائل میں تبدیل کرکے آسان و رواں زبان میں پیش کرسکتے ہیں مثلاً آیت اللہ خمینیؒ کی توضیح المسائل سے مسئلہ نمبر ۷۴۴ منتخب کرکے یہی کام انجام دے رہے ہیں۔
"اگر دو عادل مرد وقت کے داخل ہونے کی خبر دیں یا انسان خود یقین کرکے کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے اور نماز شروع کرے اور اثناء نماز میں اسے معلوم ہوجائے کہ ابھی تک وقت داخل نہیں ہوا تو اس کی نماز باطل ہے اور یہی حکم ہے اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہو کہ پوری نماز وقت سے پہلے پڑھی ہے البتہ اگر اثناء نماز میں اسے معلوم ہو کہ وقت داخل ہوگیا ہے یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہو کہ اثناءِ نماز میں وقت داخل ہوگیا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے"
یہ مفصل مسئلہ مندرجہ ذیل چار مختصر مسائل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جن میں سے دو کا تعلق اثناءِ نماز سے ہے اور دو کا تعلق نماز سے فراغت کے بعد سے ہے:
۱ ۔ اگر نماز گزار کو اثناء نماز میں معلوم ہوجائے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تو اس کی نماز باطل ہے۔
۲ ۔ اگر اثناء نماز میں نماز گزار کو معلوم ہوجائے کہ وقت داخل ہوگیا ہے (یعنی ابھی تک نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تھا اب شروع ہوا ہے) تو اس کی نماز صحیح ہے۔
۳ ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہو کہ پوری نماز وقت سے پہلے پڑھی ہے تو نماز باطل ہے۔
۴ ۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہو کہ نماز کا کچھ حصہ وقت سے پہلے پڑھا گیا ہے ؛ یعنی نماز کے دوران وقت داخل ہوا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے۔
سوالات
۱. معاذ بن جبل سے نبی کریم ﷺ کا فرمان "یَسِّر وَلَا تُعَسِّر " کس طرح احکام میں سادہ گوئی پر دلالت کر رہا ہے؟
۲. بیان احکام میں سادہ گوئی سے کیا مراد ہے؟
۳. فقہی اصطلاحات و لغات کی کتنی قسمیں ہیں؟ مثال کے ساتھ بیان کریں۔
۴. توضیح المسائل سے کوئی ایک مفصل مسئلہ منتخب کرکے اسے مختصر، رواں اور سادہ زبان میں بیان کریں۔
____________________
۲۹ ۔توضیح المسائل، م ۷۹۷۔
۳۰ ۔سورہ قمر (۵۴) آیت ۱۷۔
۳۱ ۔سیرہ ابن ہشام، ج۲، ص ۵۹۰۔
نویں نشست
اصول دوم۔بشارت دِہی
جب حضور ؐ سرور کائنات نے معاذ بن جبل کو تبلیغ کے لئے بھیجا تو آپؐ نے ان سے یہ بھی فرمایا: "بَشِّر وَ لَا تُنَفِّر " اے معاذ جب تم لوگوں میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کرو تو اس نکتہ کی طرف متوجہ رہنا کہ تم احکام و معارف دین اس طرح بیان کرنا کہ ان میں دین کی نسبت تنفر پیدا ہوجائے بلکہ تمہارا طریقہ کار بشارت دہندہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے ان میں امید کی کرن پیدا ہو اور وہ معارف دین و احکام شریعت کو مشکل سمجھنے کے بجائے آسان سمجھیں اور اس طرح وہ احکام سیکھنے میں دلچسپی پیدا کرنے لگیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان میں کس طرح یہ بشارت اور امید کی کرن پیدا کرسکتے ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مندرجہ ذیل نکات کی پابندی کریں تو یقیناً ان میں بشارت و امید پیدا کی جاسکتی ہے:
(الف) اس طرح احکام بیان نہ کئے جائیں کہ مخاطبین سلب آزادی محسوس کریں۔ اگر مخاطبین خصوصاً نوجوان طبقہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ہر چیز حرام ہے، ہر چیز ممنوع ہے، ہر جگہ خطرہ ہے کی علامت ہے تو وہ یقیناً احکام دین سے فرار کرنے لگیں گے۔ حالانکہ اسلام نے ممنوع و محرمات کی نسبت مباح اور جائز چیزوں کا دائرہ بہت وسیع قرار دیا ہے۔
یاد رہے کہ اسلام نے چار اصول متعارف کروائے ہیں جنکی بنیاد پر ہم لوگوں میں سے سلب آزاد کے احسا س کا خاتمہ کرسکتے ہیں؛ جو مندرجہ ذیل ہیں:
۱ ۔ اصل طہارت: "کُلّ شیءٍ طاهرٌ حتی تَعۡلَم انه قَذِر ؛ یعنی ہر چیز پاک ہے جب تک کہ اس کی نجاست کا علم نہ ہوجائے۔
۲ ۔ اصل اباحت: اسلام کا قانون یہ ہے کہ عام طور پر تمام اعمال اور کام کاج مباح اور جائز ہیں مگر یہ کہ کسی عمل یا کام کو نص و دلیل کے ذریعے خارج کر دیا جائے۔ جیسے تمام چیزوں مثلاً دریا، درخت، پہاڑ، گلشن، سبزہ، قدرتی نظارے سب کچھ دیکھنا جائز ہے صرف نامحروم کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ اسی طرح تمام کھیل Games جائز ہیں صرف دو شرائط کے ساتھ جائز نہیں ہیں:
۱. اگر کھیل کے وسائل جوئے سے مخصوص ہو۔
۲. ہار جیت کی شرط کے ساتھ ہو۔
۳ ۔ اصل حلیت:یعنی خداوند عالم نے تمام پاک وپاکیزہ کھانے پینے کی اشیاء کو حلال قرار دیا ہے۔ اسلام میں جو غذا حرام ہے وہ سب کے لئے حرام ہے اور ہر جگہ حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی مریض ہے یا کوئی غذا بدن کے لئے مضر ہو تو حرام ہوجاتی ہے ورنہ حلال ہے۔
۴ ۔ اصل صحت: یعنی اسلام کا قانون یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کے اعمال صحیح ہیں یعنی مسلمان جو کام انجام دیتا ہے اسلام نے اسے صحیح قرار دیا ہے مثلاً مسلمان کے ہاتھوں دُھلے ہوئے کپڑوں کے بارے میں شک ہو کہ پاک ہوئے ہیں یا نہیں تو اسلام اس عمل کو صحیح قرار دیتا ہے لہذا کپڑے پاک ہیں۔
بازار کے خریدے گئے گوشت کے بارے میں اگر شک کریں کہ اسے ذبح کے وقت "بسم اللہ" کہا یا نہیں؟ جانو قبلہ رخ تھا یانہیں؟، چاروں رگیں کاٹی تھیں یا نہیں؟، اسلام نے صحیح قرار دیا ہے لہذا گوشت حلال و پاک ہے۔
اگر اس طرح مسائل بیان کئے جائیں گے تو یقیناً مخاطبین کے دل میں سلب آزادی کے احساس کا خاتمہ ہوگا احکام سیکھنے کی طرف رغبت بڑھے گی اور دلچسپی کے ساتھ درس احکام میں شرکت کریں گے۔
لیکن اگر اس طرح بیان کئے جائیں کہ وہ یہ سمجھنے لگیں کہ اسلام کی نظر میں ہر کام ناجائز ہے، ہر چیز ناپاک ہے، ہر چیز حرام ہے اور ہر کام غلط ہے تو یقیناً وہ احکام دین سے دوری کرنے لگیں گے اور رفتہ رفتہ وہ اسلام ہی سے دور ہوجائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے مثلاً اگر ہم طہارت و نجاست کے مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ اسلام کی نظر م یں صرف گیاہ چیزوں کے علاوہ تمام چیزیں پاک ہیں۔ اس طرح مخاطب کی نظرمیں خود بخود وسعت پیدا ہوجائے گی اور وہ خوشی محسوس کرےگا کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے جس نے تمام اشیاء کو پاک قرار دیا ہے؛ اور ان گیارہ چیزوں میں بھی کسی چیز کو نجس کرنے کے لئے یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں:
۱. دونوں یا کوئی ایک تر ہو۔
۲. تری اتنی ہو کہ دوسرے پر سرایت کر جائے۔
(ب) گرہ گشاء: احکام بیان کرتے وقت آپ کی روش گرہ گشاء ہونی چاہیے یعنی مشکل اور مبہم مسائل کو حل کرنا چاہیے مثلاً بعض لوگ چوہے، لال بیگ وغیرہ کو نجس سمجھتے ہیں حالانکہ نجس نہیں ہیں۔
بعض لوگ خرگوش کو حلال سمجھتےہیں حالانکہ حرام ہے۔
نیز بعض لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں مثلاً:
دوران جماعت شرکت کرنے پر تشہد پڑھنا چاہیے یا نہیں؟
تسبیحات اربعہ میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟
سجدۂ سہو میں تکبیرۃ الاحرام ہے یا نہیں؟
زمین پر چپکے ہوئے کار پیٹ کو کس طرح پاک کیا جائے؟
کیا واشنگ مشین کپڑوں کو پاک کر دیتی ہے یا نہیں؟
پس اس طرح احکام بیان کرنا چاہیں کہ لوگ درس احکام کو گرہ گشاء خیال کریں اور اس بات کا یقین حاصل کرلیں کہ بہرحال اسلام ہماری بہت سی مشکلات کو حل کرتا ہے۔
(ج) بیان احکام کلی و کلیدی: یعنی احکام عمومی اور کلیدی عنوان سے بیان کرنے چاہئیں جس کی بنا پر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس نے بہت سے مسائل سیکھ لئے ہیں مثلاً بعض لوگ جب عمل صالح کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اسے صرف نماز روزہ میں محدود کر دیتے ہیں حالانکہ عمل صالح صرف نماز روزہ میں محدود نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچتا ہے یا کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں بھی عمل صالح درکار ہے اس لئے کہ اگر وہ شخص بیچنے میں یا بنانے میں خیانت کرتا ہے تو اس کا وہ عمل ، صالح نہیں ہوگا اور اسلام کی نظر میں قابل مذمت و ملامت ہے۔
پس اسے بعض مسائل کلی طور پر بیان کرنے چاہئیں تاکہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوکہ اس نے بہت سے مسائل سیکھ لیئے ہیں۔ مثلاً:
o نماز میت کے سوا تمام نمازوں میں طہارت شرط ہے۔
o تمام غسل کیفیت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں صرف نیت میں فرق ہوتا ہے۔
o جو اعمال وضو کے ساتھ صحیح ہیں وہ وضو کے بدلے تیمم سے بھی صحیح ہوتے ہیں۔
o جو اعمال غسل کے ساتھ صحیح ہیں وہ و ضو کے بدلے تیمم سے بھی صحیح ہوتے ہیں۔
o ہر نجس چیز حرام ہے لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔
o صرف نماز پنجگانہ اور ان کی قضاء کے علاوہ کسی واجب یا مستحب نماز کے لئے اذان و اقامت نہیں ہے۔
o نماز وتر کے علاوہ تمام مستحب نماز دو رکعت ہوتی ہیں۔
سوالات
۱. احکام بیان کرتے وقت بشارت دہی سے استفادہ کا کیا فائدہ ہے؟
۲. مخاطبین میں کن عوامل کے ذریعے امید کی کرن پیدا کی جاسکتی ہے؟
۳. سلب آزادی کے احساس کا خاتمہ کن اصولو ں کے ذریعے کیا جاسکتا ہے؟
۴. چار کلی و کلیدی احکام بیان کریں۔
دسویں نشست
اصول سوم۔کلیدی و کلّی احکام اور بیان مثال
احکام بیان کرتے وقت مثال و مصداق بیان کرنے کی افادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اگر ان کے لئے مثال و مصداق بیان نہ کیا جائے تو احکام نہیں سمجھ پاتے۔ لہذا استاد احکام کے لئے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل نکات کی پابندی کرے:
۱. احکام سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے،
۲. احکام کے مصادیق سے مکمل آشنائی رکھتا ہو،
۳. حکم کے مطابق مصداق بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
اگر ہم احکام بیان کرتے وقت مثال و مصداق بیان کرتے رہیں تو ہمارا یہ طریقہ کار لوگوں کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگا اور وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ یقیناً فقہ کا کام ہماری زندگی کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔
شرائط مثال و مصداق
ہم جن احکام کے لئے جو مصداق و مثال بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی کرنی چاہیے:
۱ ۔ مصداق ، حکم کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ حکم کچھ اور بیان کیا جائے اور مثال کا تعلق کسی اور حکم سے ہو۔
۲ ۔ مخاطبین کی احتیاج کے مطابق ہو۔ یعنی مصداق بیان کرتے وقت زمان و مکان کا خیال رکھا جائے اور قدیمی و پرانی مثالوں سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ مثلاً
۱ ۔ اشیاء، دیوار یا ظروف کی کیفیت تطہیر میں نجس تنور کی تطہیر کے طریقے کی مثال بھی پیش کی جاتی ہے(۳۳) لیکن یہ مثال اس وقت بالکل مناسب و بروقت تھی جب گھر گھر تنور بنے ہوئے تھے اور کسی بچہ یا جانور کا پیشاب سے وہ نجس ہوجاتا تھا جبکہ آج کے دور میں یہ مثال بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
۲ ۔ احکام طہارت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کپڑا وغیرہ دھونے کے بعد اس میں تھوری سی مٹی یا اُشنان کے ٹکڑے نظر آئیں تو وہ پاک ہیں ہاں اگر نجس پانی مٹی یا اشنان کے اندر والے حصہ کو لگا ہے تو متی اور اشنان کا ظاہر پاک اور باطن نجس ہوگا۔(۳۴)
اشنان صحرائی گھاس ہے جو خود بخود اُگ آتی ہے، گذشتہ زمانے میں لوگ اس سے اپنے کپڑے دھو لیتے تھے اگر اسے اچھی طرح مَل کر صاف نہ کیا جاتا تواس کے ٹکڑے کپڑوں پر لگے رہ جاتے تھے لیکن آج لوگ بالکل اُشنان سے نا آشنا ہیں لہذا آج کل تو سرف کی مثال بیان کرنی چاہیے۔
۳ ۔ احکام جعالہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر جو شخص بھی میرا گم شدہ گھوڑا ڈھونڈ کر لائے گا تومیں اسے یہ گندم دوں گا۔(۳۵)
آج کل یہ مثال دینا موقع و محل کی مناسبت سے صحیح نہیں ہے بلکہ آج کل جو چیزیں گم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں مثلاً پرس، اے ٹی ایم کارڈ، گاڑی کی چابی، موٹر سائیکل، گاڑی اور مکان وغیرہ کے کاغذات۔
۴ ۔ ضمانت کے عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے:
اجارہ؛ اگر کسی کا جانو کرایہ پر لیا جائے اور مالک معین کردے کہ اس جانور پر صرف اتنا وزن لادنا۔ پس اگر کرائے پر لینے والا شخص اس شرط کی خلاف ورزی کرے جس کی وجہ سے حیوان مر جائے یا عیب دار ہوجائے تو کرائے پر لینے والا شخص ضامن ہوگا۔(۳۶)
آج اس مثال کا دور تقریباً ختم ہوچکا ہے لہذا آج گاڑی وغیرہ کی مثال دینی چاہیے۔
اگر ہمارے مخاطب اسکول کے بچے ہوں تو ہمیں پین، کاپی، شارپنر، ربڑ وغیرہ کی مثال دینی چاہیے کیونکہ بچے عام طور پر ایک دوسرے سے یہ چیزیں لیتے ہیں لہذا انھیں بتانا چاہیے کہ اگر ہم نے بد احتیاطی کی تو نقصان بھرنا پڑے گا۔
اسی طرح نوجوان ایک دوسرے سے سائیکل یا موٹر سائیکل وغیرہ عاریۃً لے لیتے ہیں یا مہمان داری کے لئے پڑوسیوں سے برتن وغیرہ لے لئے جاتے ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے گی تو نقصان بھرنا پڑے گا لیکن اگر احتیاط سے کام لیا ہے تو نقصان کی صورت میں ضامن نہیں ہوگا یعنی اسے نقصان نہیں بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ امانت ہے اور امین ضامن نہیں ہوا کرتا۔
آفس اور دفتر وغیرہ میں کام کرنے والوں کے لئے دفتری اشیاء کی مثال دینی چاہیے جیسے: کمپیوٹر، گاڑی، ٹیلیفون اور فرنیچر وغیرہ، یعنی اگر ان کی بد احتیاطی سے کسی چیز کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ ضامن ہے اور اسے نقصان بھرنا پڑے گا۔
اگر پولیس والے بلا جواز دروازہ توڑ کر گھر میں گھستے ہیں اور گھریلو یا طلائی زیورات ناجائز لے جاتے ہیں تو تمام تر نقصان کے ذمہ دار ہیں۔
نیز سڑک پر No Parking کی جگہ پر کھڑی گاڑی کو اگر متعلقہ محکمہ اٹھا کر لے جاتا ہے، اگر گاڑی کو نقصان پہنچتا ہے تو اٹھانے والا یا نقصان پہنچانے والا ضامن ہے اور نقصان بھرنا پڑے گا۔
ضمانت ایک ایسا حکم شرعی ہے جس کے مختلف مصادیق پائے جاتے ہیں لہذا مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لئے ان کے پیشوں کی مناسبت سے مثالیں بیان کرنی چاہئیں۔
روش تحریر: اگر درس احکام میں بعض مطالب بورڈ پر لکھے جائیں تو یہ بیان کرنے سے زیادہ موثر اور سودمند ثابت ہوتا ہے لہذا بعض مسائل میں صرف سوال لکھ دینا چاہیے یا بعض مطالب کی جدول و نموداری ترسیم بنادینی چاہیے، یا بعض نہایت تاکیدی مطالب لکھ دینے چاہئیں مثلاً جب ہم یہ مسئلہ بیان کریں "جن مسائل کی انسان کو عام طور پر ضرورت پڑتی ہے تو ان کا سیکھنا واجب ہے" تو اس میں صرف دو الفاظ "ضرورت" اور "واجب" لکھ دیا جائے۔
سوالات
۱. استاد احکام کو بیان مثال کے لئے کس قسم کی مہارت درکار ہوتی ہے۔
۲. مثال و مصداق بیان کی شرط کیا ہے؟
۳. ضمانت کی چار مختلف شعبوں سے سے مربوط مثالیں بیان کریں۔
____________________
۳۲ ۔غرر الحکم، ح ۳۳۷۱۔
۳۳ ۔توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۸۔
۳۴ ۔توضیح المسائل، م ۱۶۹۔
۳۵ ۔توضیح المسائل، م ۲۲۱۵۔
۳۶ ۔توضیح المسائل، م ۲۱۹۹۔
گیارھویں نشست
ب:روشیں
روش عملی
احکام کی تعلیم کے لئے جس طرح ہر چیز کی تصویر بنانا ممکن نہیں ہے اسی طرح تمام احکام کی عملی تعلیم نہیں دی جاسکتی البتہ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ اگر ان کی عملی تعلیم نہ دی جائے تو کسی صورت صحیح عمل انجام نہیں دیا جاسکتا مثلاً وضو جبیرہ، نماز جماعت، نماز آیات، حج وغیرہ۔ جب تک تیمم کی عملی تعلیم نہ دی جائے چاہے جتنی وضاحت بیان کرتے رہیں صحیح تیمم کرنے میں اشتباہ کرتے رہتے ہیں۔
آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ دو سال کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اسے نماز نہیں آتی ہے کیا اس کا ا س طرح کھڑے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے؟ نہیں کیونکہ اسے حمد و سورہ نہیں آتی ہیں۔ لیکن وہ جس طرح اپنی والدہ کو عمل انجام دیتے ہوئے دیکھتا ہے وہ عمل دہراتا رہتا ہے۔
اور اس طرح وہ رفتہ رفتہ قیام، رکوع اور سجود سیکھ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بچہ عمل تیزی سے سیکھ لیتا ہے۔
حدیث میں وارد ہوا ہے: "دُعَاةَ النَّاسِ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ "(۳۷) لوگوں کو بغیر زبان کے دین کی طرف دعوت دو۔
اگرچہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ تم نیکو کار بن جاؤ تاکہ لوگ تمہارے نیک کردار سے متاثر ہوکر دین کی طرف کِھچنا شروع ہو جائیں۔ لیکن ہم اس حدیث سے یہ استفادہ بھی کر سکتے ہیں کہ تبلیغ دین میں فقط گفتار و کلام سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ لوگوں کو احکام دین کی عملی تعلیم بھی دینی چاہیے۔
جب ہم حضور ؐ سرور کائنات اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں عملی تعلیم کے نمونہ جابجا نظر آتے ہیں مثلاً:
پیغمبر گرامی قدر ﷺ نے فرمایا:
"صَلُّوا کَمَا رَأَیۡتُمُونِی اُصَلِّی "(۳۸) جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتےہو اس طرح نماز پڑھو۔
جب آپ مخاطبین کو نماز کی تعلیم دینا چاہیں اور ان سے کہیں کہ نماز کے لئے روبقلبہ کھڑے ہوجاؤ، نیت کرو، تکبیرۃ الاحرام کہو پھر سورہ حمد پھر کوئی دوسرا سورہ پڑھو، پھر رکوع کرو پھر کھرے ہوکر سجدے میں جاؤ وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ نے انھیں صرف زبانی تعلیم دی ہے جبکہ آپ انھیں عملی تعلیم بھی دے سکتے ہیں کہ ان سے کہیں جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔
نیز جب امام حسن ؑ و امام حسین ؑ نے بچپن میں ایک شخص کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپؑ نے اس سے براہ راست یہ نہیں کہا کہ تمہارا وضو غلط ہے اور صحیح وضو کا طریقہ اس اس طرح ہے ، آپ نے اس کی زبانی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ فرمایا: اے شیخ! ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں آپ دیکھ کر بتائیے کہ کس کا وضو زیادہ اچھا ہے۔(۳۹)
امام علیہما السلام نے یہاں دو کام انجام دیئے ہیں:
(الف) عملی تعلیم،
(ب) غیر مستقیم تعلیم۔
اگر براہ راست اس سے یہ کہہ دیتے کہ تمہارا وضو غلط ہے تو شاید وہ ان کی بات کی بالکل پرواہ بھی نہ کرتا لیکن ائمہ علیہما السلام کے اس انداز تبلیغ کی وجہ سے اس کی اصلاح بھی ہوگئی اور اس نے ان کی بات مان بھی لی۔
ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے پانی اور تشت طلب کیا اور لوگوں کو وضو پیغمبر کی عملی تعلیم دی۔(۴۰)
نیز کتب حدیث میں نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے اونٹ پر سوا ر ہوکر کعبہ کا طواف انجام دیا۔(۴۱)
پوچھنے والوں نے پوچھا: پیدل طواف کرنا افضل ہے یا سوار؟ جواب دیا گیا کہ پیدل۔
سوال کیا: اگر پیدل طواف کرنا افضل ہے تو آنحضرت نے سوار ہوکر طواف کیوں کیا ہے؟ جبکہ آنحضرتؐ افضل کو ترک نہیں کرسکتے ہیں!
فرمایا: یہ طواف، تعلیمی طواف تھا یعنی ہمیں یہ بات تعلیم دینا چاہتے تھے کہ سواری پر بھی طواف میں مضائقہ نہیں ہے۔ آنحضرتؐ زبانی بھی بیان کرسکتے لیکن اس لئے خود سوار ہوکر طواف کرکے دکھایا تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔
یاد رہے کہ منابع فقہ میں سے ایک سنت معصومینعلیہم السلام ہےاور سنت، معصوم ؑ کے قول، فعل اور تقریر کا نام ہے۔ یعنی فعل معصوم ؑ بھی منابع فقہ میں سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم ؑ کے عمل کو دیکھ کر ہم اپنے عمل کی اصلاح کرسکتے ہیں۔
نیز احکام کی عملی تعلیم کا ایک بہترین اور واضح نمونہ مندرجہ ذیل روایت حماد بن عیسیٰ ہے۔
"حماد بن عیسیٰ کہتےہیں: ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا:تحسن أن تُصلی یا حماد ۔ اے حماد! کتنا اچھا ہوگا کہ تم کھرے ہو کر ذرا میرے سامنے نماز پڑھو۔
میں نے عرض کیا:
یا سیدی اَنا أحفظ کتاب حریز فی الصلاة ۔
مجھے حریز کی پوری کتاب صلاۃ حفظ ہے اور میں اسی کے مطابق نماز پڑھتا ہوں۔
فرمایا: لا علیک، قم صلّ؛ کوئی بات نہیں، کھڑے ہوجاؤ اور نماز پڑھو۔
کہا: پس میں نے کھڑے ہوکر ایک نماز پڑھی ۔۔۔(۴۲) "
امام ؑ نے ان کی نماز کی کیفیت دیکھ کر فرمایا:تم ہمارے اصحاب میں سے ہو اور تمہاری نماز کی یہ حالت ہے۔ اس کے بعد آنجناب ؑ خود کھرے ہوئے اور فرمایا: اب تم ہماری نماز کی کیفیت دیکھو اور آئندہ اسی طرح نماز پڑھنا۔
اس کے بعد حماد نے امام ؑ کے تکبیر کہنے، قرائت و ذکر وغیرہ کی مکمل کیفیت نقل کی ہے۔
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض احکام و مسائل کی تعلیم لازمی طور پر عملی ہونی چاہیے۔
سوالات
۱. احکام کی عملی تعلیم کے بارے میں نبی کریم ؐ کی روایت بیان کریں۔
۲. سیرہ معصومین ؑ میں سے احکام کی عملی تعلیم کا ایک نمونہ بیان کریں۔
۳. احکام کی عملی تعلیم کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟
____________________
۳۷ ۔وسائل الشیعہ، ج۱۱، ص ۱۹۴۔
۳۸ ۔بحار الانوار، ج۸۵، ص ۲۷۹۔
۳۹ ۔بحار الانوار، ج۱۰، ص ۸۹۔
۴۰ ۔بحار الانوار، ج۱۰، ص ۸۹۔
۴۱ ۔کافی، ج۳، ص ۲۵۔
۴۲ ۔وسایل الشیعہ، ج۵، ابواب افعال الصلاۃ، ص ۴۵۹؛ من لا یحضرہ الفقیہ، ج۱، ص ۳۰۰۔
روش ہُنری
کبھی کبھی یہ مشاہد ہ کیا جاتا ہے کہ احکام کا درس خستہ کنندہ ہوجاتا ہے ایسے موقع پر خستگی کو دور کرنے اور درس کو دلچسپ اور جاذب بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
یاد رہے کہ خستگی کو دور کرنے اور درس احکام کو دلچسپ اور جاذب بنانے کا ایک مؤثر طریقہ ہنر سے استفادہ کرنا ہے۔ ذیل میں بعض مختلف ہنر پیش کئے جا رہے ہیں جن سے مبلغ مختلف مواقع پر موقع و محل کی مناسبت سے استفادہ کرسکتا ہے:
۱. نقاشی
۲. معمّا
۳. شعر
۴. داستان
۵. فیلم و نمائش
۶. خوشخط
۱ ۔ نقاشی: اگر نقاشی سے استفادہ کرنا فقہی مسائل کی تفہیم میں بہترین اور مؤثر کردار ادا کرتا ہے لیکن یاد رہے کہ بہت سے مسائل کی تصویر کشی نہیں کی جاسکتی مثلاً اجتہاد و تقلید کے احکام قابل نقاشی نہیں ہیں البتہ طہارت کے بہت سے مسائل کو نقاشی کے ذریعہ سمجھایا جا سکتا ہے مثلاً باب مطہرات میں پانی اور سورج وغیرہ کی تصویریں بنائی جاسکتی ہیں یہاں تک کے بعض جزئی احکام بھی تصویر کے ذریعے سمجھائے جاسکتے ہیں۔
پانی کی اقسام
۱. بارش کا پانی
۲. جاری پانی جو زمین سے پھوٹ کر زمین پر بہہ رہا ہو
۳. کنوئیں کا پانی
۴. ٹھہرا ہوا پانی، جو نہ زمین سے پھوٹے اور نہ آسمان سے برسے
کُر پانی وہ ٹھہرا ہوا پانی جس کی مقدار زیادہ ہو
قلیل پانی وہ ٹھہرا ہوا پانی جس کی مقدار کم ہو
مطہرات میں سے ایک سورج ہے
سورج درخت اور پودوں کو پاک کرتا ہے
نیز مکانات کو بھی کرتا ہے
نکتہ:احکام کے استاد کا ڈرائنگ ماسٹر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر کلاس میں کوئی فرد اچھی ڈرائنگ جانتا ہو تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ پہلے سے ڈرائنگ شیٹ پر تصاویر بنی ہوئی ہوں اور ان کا چارٹ اپنے ساتھ لے جائے۔
اسی طرح نماز آیات میں چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ، طوفان وغیرہ کی بھی تصاویر بناکر پیش کی جاسکتی ہیں۔
۲ ۔ معما: کلاس کے جمود کو توڑنے کے لئے کوئی سوال اٹھا دیا جائے مثلاً وہ کون سی نماز ہے جو بغیر وضو بھی جائز ہے؟ (نماز میت)
۳ ۔ شعر: مطالب کے نقل و انتقال میں اشعار کی تاثیر کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آج بہت بہت سی کمپنیاں اپنی مصنوعات کی شہرت کے لئے شعر پر مبنی ایڈوَرٹائز بناتے ہیں۔ نیز علمائے اسلام نے بھی اس ہنر سے خاطر خواہ استفادہ کیا ہے۔
توجہ: وہ درس جس میں ہم صرف ایک جگہ زانو طے کرکے یا کرسی پر بیٹھ کر اور چہرہ پر رعب ڈال کر سیدھے سیدھے مسائل بیان کرتے رہیں۔ نہ اس میں کوئی معما ہو، نہ نقاشی و تصویر ہو یا شعر وغیرہ سے بالکل خالی ہو تو ایسا درس دلچسپ اور جاذب کیسے ہوسکتا ہے؟!
سوالات
۱. احکام کے درس میں مختلف ہنر سے استفادہ کا کیا فائدہ کیا ہے؟
۲. احکام کے درس میں نقاشی (ڈرائنگ) کی اہمیت بیان کریں؟
۳. پانی کے احکام یا مطہرات نقاشی کے ذریعے بیان کریں۔
بارھویں نشست
روش سوال و جواب
مخاطبین سے سوال
کبھی کبھی درس احکام کے خستہ کنندہ ہونے کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ احکام کے استاد محترم یا مبلغ محترم صرف خود اپنے بولنے اور بیان کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں اور مخاطبین کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے جس کی وجہ سے مخاطبین سنتے سنتے تھک جاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ا یسے درس سے فرار کرتے ہیں۔ لہذا درس کے دوران وقتاً فوقتاً مخاطبین سے سوال کرکے انھیں اپنے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے پس مخاطبین سے سوال کرنے کی دو قسمیں ہیں۔
۱ ۔ تعلیمی سوال ۲ ۔ آزمائشی سوال
تعلیمی سوال عام طور پر بیان نشدہ چیزوں کے بارے میں کیا جاتا ہے جبکہ آزمائشی سوال بیان شدہ چیزوں کے بارے میں کیا جاتا ہے تاکہ یہ اندازہ ہوسکے کہ ہم نے جو چیزیں انھیں سکھائی ہیں وہ کس حد تک سمجھ سکے ہیں لیکن تعلیمی سوال انھیں نئے مطالب سکھانے اور سمجھانے کے لئے پیش کئے جاتے ہیں مثلاً شرائط وضو میں سے کچھ ہم خود بیان کریں گے اور پھر کچھ مخاطبین سے سوال کریں اور اس کے بعد انھیں بتادیں۔
اس عمل سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے:
۱. کلاس کی خستگی زائل ہوگی اور مخاطبین ، استاد کے ساتھ شریک ہوجائیں گے۔
۲. مخاطبین کے ذہن میں تجسس پیدا ہوگا اور ان کی توجہ بڑھے گی۔
سوالِ مخاطبین
جب ہم احکام کے درس کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ درس احکام سیاسی، تاریخی یا اخلاقی تقریر نہیں ہے بلکہ ہم جب چند منٹ احکام و مسائل بیان کرتے ہیں تو مخاطبین کی جانب سے سوالات ہونا شروع ہوجاتے ہیں لہذا ہمیں ان کے سوالات کی نوعیت سمجھنی چاہیے۔ یاد رہے کہ مخاطبین کے سوالات کی دو قسمیں ہیں:
۱. سوال برائے دریافت؛
۲. سوال برائے سوال۔
اکثر مخاطبین کے سوالات، جواب دریافت کرنے کے لئے ہوتے ہیں، بہت کم افراد سوال برائے سوال کرتے ہیں اور ان کے سوالات کبھی شفاہی ہوتے ہیں اور کتبی، اسی طرح کبھی درس کے شروع میں سوال کرتے ہیں، کبھی وسط درس میں اور کبھی آخر میں۔
مہارت جواب
مخاطبین کی جانب سے سوال برائے سوال کم کرنے کے لئے استاد یا مبلغ کو مندرجہ ذیل نکات کا تذکر دیدینا چاہیے۔
۱ ۔ جواب کا طریقہ: یعنی اپنے جواب دینے کا طریقہ کار درس کے آغاز میں بیان کردینا چاہیے مثلاً جس کے ذہن میں جو سوال بھی آئے برائے مہربانی وہ درس کے آخرمیں یا تحریری طور پر پیش کردے کیونکہ جواب صرف درس کے آخری میں یا تحریری دیئے جائیں گے۔
۲ ۔ سوال کا فائدہ عمومی ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کے ذہن میں کوئی انفرادی سوال آتا ہے جو تمام لوگوں کے لئے فائدہ مند نہیں ہے تو برائے کرم دوسروں کا وقت ضائع نہ کیا جائے بلکہ درس کے بعد سوال پیش کیا جائے تاکہ جواب دیا جاسکے۔
جب ہم یہ بات کہہ دیں گے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال برائے سوال موجود ہو تو وہ سوال کرنے سے باز رہے گا کیونکہ سمجھ جائے گا کہ اگر سوال کرے گا تو صرف استاد ہی نہیں بلکہ مخاطبین بھی اس کی طرف انگشت نمائی کریں گے۔
۳ ۔ سوال صرف درس سے متعلق ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں صرف فقہی سوال پیش کئے جائیں بصورت دیگر درس کے بعد سوال کیا جائے تاکہ جواب حاصل کرسکیں۔
اقسام جواب
مخاطبین کی جانب سے کئے گئے سوالات کے جوابات دو طرح دیئے جاسکتے ہیں:
(الف) شفاہی جواب:مندرجہ ذیل مختلف اوقات میں شفاہی جواب دیئے جاسکتے ہیں:
۱ ۔ اثنائے گفتگو؛ یعنی ہم درس کے آغاز میں اعلان کردیں کہ جو صاحب بھی سوال کرنا چاہیں وہ سوال کرنے میں آزاد ہیں کسی وقت بھی سوال کرسکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس روش کو اختیار کرنے کے لئے کافی علمی توانائی درکار ہوتی ہے نیز اس کے ساتھ ساتھ مبلغ میں حاضرین پر حاوی ہونے اور انھیں ادارہ کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے ورنہ علم کی کمی یا مخاطبین کی کثرت کی بنا پر وہ اس روش سے استفادہ نہیں کرسکتا ہے۔
۲ ۔ موضوع کے اختتام پر؛ جب ہم درس میں چند جزئی موضوعات پیش کرنا چاہیں تو جب ایک موضوع ختم ہوجائے تو اعلان کریں کہ اگر یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پیش کرسکتا ہے، اس طرح ہر موضوع کے اختتام پر ایک دو سوال پیش ہوں گے اور آخر میں کثرت سوالات سے چھٹکارا ملے گا۔
مثلاً جب ہم وضوع کے بارے میں درس دینا چاہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے موضوعات بنالیں جیسے وضو کا طریقہ، شرائط وضو، موجبات وضو، مبطلات وضو وغیرہ ان میں سے ہر موضوع کے اختتام پر سوال و جواب پیش کئے جاسکتے ہیں۔
۳ ۔ درس کے اختتام پر؛ ہر درس کے اختتام پر سوال و جواب کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔
۴ ۔ بعد والے درس میں؛ یہ طریقہ صرف کتبی سوالات کی صورت میں اختیار کرنا پڑتا ہے کہ تحریر شیدہ سوالات کو جمع کرلیا جائے، جو سوالات، سوال برائے سوال ہوں انھیں چھوڑ دیا جائے اور باقی سوالات کے جوابات مہیا کرکے بعد والے درس میں بیان کرنے چاہئیں۔ نیز تکراری سوالات بھی حذف کر دینے چاہئیں۔
(ب) کتبی جواب؛
دو مندرجہ ذیل صورتوں میں کتبی جواب دینا چاہیے:
۱ ۔ سائل کی درخواست پر؛ جب سوال کرنے والا یہ تقاضا کرے کہ اس کے سوال کا جواب کتبی دیا جائے تو اگرچہ زبانی جواب بیان کرنا ممکن ہو اور سب کے لئے زبانی بیان بھی کردیا جائے لیکن بہرحال سوال کرنے والے کو تحریری جواب دینا چاہیے۔
۲ ۔ استاد کی صلاح دید؛ کبھی ممکن ہے کہ سائل نے تو کتبی جواب کا تقاضا نہیں کیا لیکن استاد مجمع میں زبانی جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا تو وہ اعلان کرے گا کہ بعض سوالات کے جوابات زبانی بیان نہیں کئے جا رہے ہیں بلکہ تحریری لکھ دیئے گئے ہیں وہ اپنے جوابات دریافت کرسکتےہیں۔
سوال برائے سوال
اگر ہم جواب دینے کی مہارت سے بہرہ مندہ ہوں تو یقیناً سوال برائے سوال کی تعدد کم ہوجاتی ہے۔
جیسا ہم نے جواب دینے کی مہارت کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ مخاطبین کو اس نکتہ کا تذکر دیدینا چاہیے کہ ایسا سوال کیا جائے جس کا فائدہ عمومی ہو کیونکہ اگر ایک سوال کے جواب میں ایک منٹ صرف ہوگا اور ہمارے درس میں ۶۰ افراد ہیں تو گویا ہم نے ان کے ۶۰ منٹ لے لئے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر سوال برائے سوال کرنے والے کے اندر ذرا بھی ضمیر زندہ ہوگا تو یقیناً وہ سوال کرنے سے باز رہے گا۔
لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سوال برائے سوال کا جواب دینے کے لئے کوئی خاص قاعدہ یا قانون نہیں ہے۔ کبھی اس کے جواب میں خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، کبھی اس کے ذہن کو دوسری طرف موڑ دیا جاتا ہے اور کبھی نقضی جواب دیدیا جاتا ہے جو اس کو خاموش کرسکے۔
مرحوم حجۃ الاسلام و المسلمین جناب شیخ محمد تقی فلسفی فرماتے ہیں:
میں ایک مرتبہ جیسے ہی تقریر کرکے منبر سے اترا ایک نوجوان میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا آپ جو ہمیں یہ اتنی بڑی بڑی وعظ و نصیحت کر رہے ہیں آپ خود بھی ان پر عمل کرتے ہیں؟
میں سمجھ گیا کہ یہ فقط مجھے پھنسانے اور اپنی شرعی ذمہ داری سے فرار کرنے کے لئے سوال برائےسوال کر رہا ہے؛ میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا پیشہ کیا ہے؟
اس نے کہا: جوتے بناتا ہوں۔میں نے فوراً اس سے کہا: تم جتنے بھی جوتے بناتے ہو خود بھی پہنتے ہو؟ کہا: نہیں حضور، میں نے کہا: میرا پیشہ بھی تقریر کرنا ہے!
(البتہ یاد رہے کہ یہ جواب صرف مخاطب کو خاموش کرنے کے لئے تھا)
سوالات
۱. مخاطبین سے سوال کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہے؟
۲. مخاطبین کے سوالات کی کتنی قسمیں ہیں؟
۳. سوال برائے دریافت کا جواب دینے کے لئے کن نکات کا تذکر دینا چاہیے؟
۴. سوال برائے سوال کا جواب دینے کا کیا قاعدہ و قانون ہے؟
۵. سوال برائے دریافت کے جواب کی کتنی قسمیں ہیں؟
تیرھویں نشست
دوسری فصل: ممنوعات
گذشتہ فصل ان امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے درس احکام کی تیاری میں جنکا خیال رکھنا ضروری ہے اور اس فصل میں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جنہیں درس احکام میں بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور وہ چار چیزیں ہیں:
۱ ۔ وسواسی مسائل، ۲ ۔ اختلاف و تفاوت فتویٰ، ۳ ۔ دلائل احکام،
۴ ۔فلسفہ احکام، ان کی تفصیلات آگے بیان کی جائیں گی۔
۱ ۔ وسواسی مسائل
ایسے مسائل بیان کرنے سے پرہیزکرنا چاہیے کہ جنکی وجہ سے لوگ ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنے لگیں اور شک کرتے کرتے وسواسی بن جائیں۔
احتیاط اگرچہ اچھی چیز ہے لیکن ہمیشہ اور ہر جگہ نہیں بلکہ بعض مواقع پر احتیاط کا ترک کرنا ہی بہتر ہوتا ہے،نیز شک و وسوسہ بالکل غیر مناسب چیز ہے۔ بعض مسائل صحیح ہونے کے باوجود کبھی کبھی ان کا بیان کرنا مشکل ساز ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں شک و وسوسہ اور بلاوجہ کی احتیاط جیسی چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں مثلاً؛
٭اگر مکھی یا اس قسم کا کوئی جانور کسی تر چیز پر بیٹھ جائے اور اس کے بعد کسی پاک تر چیز پر بیٹھے تو اب اگر انسان کو یقین ہو کہ اس جانور کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی تو وہ پاک چیز نجس ہوجائے گی ورنہ وہ پاک رہے گی۔(۴۳)
احکام کے درس کے لئے اس قسم کے مسائل کا انتخاب بالکل غیر مناسب ہے کیونکہ اس قسم کے مسائل کی وجہ سے لوگوں میں ضرورت سے زیادہ احتیاط اور شک و وسواس پیدا ہوجائیں گے۔
لیکن اگر اس قسم کے مسائل بیان کرنا بھی چاہیں تو تصویر کا دوسرا رخ بیان کرنا چاہیے یعنی اس طرح بیان کریں جب تک نجاست کے منتقل ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ چیز پاک رہے گی۔
٭غسل میں بال کے برابر بھی اگر کوئی جگہ دھونے کےبغیر رہ جائے تو غسل باطل ہے۔(۴۴)
اس مسئلہ کے سلسلہ میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے :"غسل میں تمام بدن کا دھونا ضروری ہے اور کوئی حصہ بغیر دھوئے نہیں رہنا چاہیے"۔
توضیح المسائل میں بال کے سر کی طرف اشارہ صرف احکام میں دقت نظر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے تاکہ مکلفین اس امر کی پابندی کرتے رہیں اور پورے بدن کو دھونے کی طرف متوجہ رہیں۔
لیکن اگر اس قسم کے مسائل بیان کئے جائیں گے تو مخاطبین رفتہ رفتہ غسل میں چند منٹ کے بجائے ایک گھنٹہ صرف کردیں گے اور ایک بالٹی پانی کے بجائے ایک ٹنکی پانی خرچ کرنے لگیں گے۔
اکثر لوگ ہمارے انداز بیان کی وجہ سے وسواسی ہوجاتے ہیں، خوردبین لیکر نہایت باریک بینی کے ساتھ مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فقہی مسائل میں اس طرح کاغور و فکر اور دقت نظر کی ضرورت نہیں ہے خصوصاً جبکہ لوگوں کے وسواسی ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس قسم کے مسائل میں عرف عام کی نظر کافی سمجھی جاتی ہے۔
٭گوشوارہ وغیرہ کے لئے کان میں جو سوراخ کیا جاتا ہے اگر وہ اتنا کشادہ ہو کہ اس کے اندر کا حصہ نظر آئے تو اس کو دھو لینا چاہیے اگر نظر نہیں آتا تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔(۴۵)
پانی مایع ہوتا ہے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب کسی چیز پر ڈالا جاتا ہے تو اس کے تمام اطراف کو گھیر لیتا ہے مثلاً انگلیوں وغیرہ کا درمیانی حصہ پانی ڈالنے سے تر ہوجاتا ہے کیا اس قسم کی دقت نظر اور احتیاط کی ضرورت ہے؟ جبکہ پیغمبر اکرم ﷺ نے وضو کے لئے ایک مد ( ۷۵۰ گرام) پانی اور غسل کے لئے ایک صاع (تین کلو) سے زیادہ پانی استعال کرنے کو منع فرمایا ہے۔(۴۶)
لہذا اس طرح بیان مسائل سے پرہیز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ احکام سے دور ہوجائیں اور شک و وسوسہ کا شکار ہوجائیں۔
۲ ۔ اختلاف فتویٰ
عام طور پر رسالہ عملیہ میں جن مسائل میں تفاوت دیکھنے میں آتا ہے وہ فتویٰ میں اختلا ف نہیں ہوتا بلکہ:
(الف) کبھی کبھی طرز نگارش و عبارت میں اختلاف ہوتا ہے۔
(ب) کبھی تعبیر میں اختلاف ہوتا ہے لیکن فتویٰ دونوں مراجع کا ایک ہی ہوتا ہے مثلاً اظہر و ظاہر وغیرہ۔
(ج) کبھی فتویٰ میں اختلاف ہوتا ہے لیکن قابل جمع ہوتا ہے۔
(د) کبھی فتویٰ میں اختلاف ہوتا ہے اور قابل جمع بھی نہیں ہوتا ہے۔
اگر توضیح المسائل میں ہم دیکھیں کہ مسائل میں قسم "الف" والا اختلاف و تفاوت ہے تو اس کا کوئی علمی و عملی ثمرہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہر مرجع اپنے ذوق کے مطابق رساتر عبارت استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے لئے مسائل سمجھنا آسان ہوجائیں۔
اگر قسم "ب" والا اختلاف نظر آئے تو اگرچہ اس کا علمی ثمرہ پایا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی عملی ثمرہ نہیں ہوتا لہذا اسے رسالۂ عملیہ کے بجائے رسالۂ علمیہ میں بیان کرنا چاہیے مثلاً ایک مجتہد فرماتے ہیں کہ "واجب ہے" جبکہ دوسرے مجتہد فرمائیں کہ "وجوب ، قوت سے خالی نہیں ہے"۔
یہ دو تعبیریں ہیں اور دونوں فتویٰ ہیں، مقام عمل میں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے یہ صرف ایک علمی تعبیر ہے جو حوزہ علمیہ میں اہل فن کے لئے بہتر و مفید ہے لیکن مقامِ عمل میں مقلِّد کے لئے اس پر عمل کرنا بہرحال ضروری ہے۔
نیز اسی جیسی دیگر تعابیر مثلاً، بعید نہیں ہے، مشہور ہے، اشہر ہے، بظاہر ایسا ہی ہے ، قوت سے خالی نہیں، وجہ سے خالی نہیں، ان تمام اختلاف و تفاوت کا کوئی عملی اثر نہیں ہے، اس طرح یہ تعابیر مثلاً محل اشکال ہے، اشکال سے خالی نہیں یا احتیاط واجب وغیرہ ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔
قابل جمع اختلاف فتویٰ
درحقیقت مراجع تقلید کے جن فتاویٰ میں عمل کے اعتبار سے اختلاف نظر پایا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں یا یہ اختلاف قابل حل اور قابل جمع ہوتا ہے یا نا قابل جمع ہوتا ہے۔ قابل جمع سے مراد یہ ہے کہ ایک فتویٰ بیان کرکے بقیہ دیگر فتاویٰ سے قطع نظر کرتے ہیں لیکن اس صورت میں دوسرے مجتہد کے مقلدین اگر اس پر عمل کرلیں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔
یعنی جب ہم ایک فتویٰ بیان کریں اور دیگر مجتہد کے مقلدین بھی اس پر عمل کریں تو گویا انھوں نے:
۱ ۔ کوئی واجب ترک نہیں کیا،
۲ ۔ کسی حرام کا ا رتکاب نہیں کیا ہے۔
پس یہاں اختلاف بیان کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر انھوں نے اس بیان کردہ مسئلہ پر عمل کرلیا ہے تو گویا انھوں نے اپنے وظیفہ کو انجام دیا ہے، گرچہ ممکن ہے مستحب ترک ہوجائے، لیکن حرام کا مرتکب نہ پائے گا۔
البتہ جہاں اختلاف فتویٰ غیر قابل جمع ہو تو وہاں اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ پس تمام اختلاف و تفاوت فتاویٰ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
ذیل میں اختلاف فتاویٰ کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جن کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے:
۱ ۔ "نجس برتن کو قلیل پانی میں تین مرتبہ دھونا ہوگا بلکہ کُر اور جاری پانی میں بھی احتیاط یہ ہے کہ تین مرتبہ دھویا جائے"(۴۷) ۔
بعض مراجع تقلید فرماتے ہیں کہ کُر اور جاری پانی میں ایک مرتبہ دھونا کافی ہے۔ اب اگر ہم یہ فتویٰ بیان کریں کہ کُر اور جاری میں تین مرتبہ دھونا چاہیے، اگر وہ شخص جو ایسے مجتہد کی تقلید کرتا ہے جو ایک مرتبہ دھونے کو کافی سمجھتا ہے؛ تین مرتبہ دھوئے تو کیا برتن پاک نہیں ہوگا؟ حتماً ہوجائے گا۔
لہذا یہاں اختلاف فتویٰ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
۲ ۔ دونوں ہاتھ دھو لینے کے بعد وضو کے پانی کی تری سے جو کہ ہاتھ میں رہ گئی ہے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا جائے۔(۴۸)
بعض مراجع تقلید کے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ مسح دائیں ہاتھ سے کیا جائے جبکہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے ضروری ہے۔
اب اگر ہم اس طرح مسئلہ بیان کریں اور کہیں: "مسح دائیں ہاتھ سے کرنا ضروری ہے" اور دوسرے مرجع عالی کے مقلد نے جاکر ہمارے کہنے کے مطابق وضو کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے مسح انجام دیا تو کیا اس نے کسی واجب کو ترک کیا ہے اور اس کا وضو باطل ہو جائے گا؟
۳ ۔ پاؤں کے مسح میں بھی بعض مراجع پاؤں پر اُبھری ہوئی جگہ تک جبکہ بعض ٹخنوں تک ضروری سمجھتے ہیں۔(۴۹)
اگر ہم نے دوسری نظر کے مطابق مسئلہ بیان کیا تو پہلی نظر کے مطابق بھی کوئی مشکل پیش آئے گی۔
۴ ۔ غسل جبیرہ کا حکم وضو جبیرہ کی طرح ہے لیکن احتیاط واجب کی بنا پر اسے ترتیبی انجام دیا جائے نہ ارتماسی۔ جبکہ بعض ترتیبی کو احتیاط مستحب قرار دیتے ہیں۔(۵۰)
اگر پہلا فتویٰ بیان کردیا جائے تو دوسرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
۵ ۔ انسان رکوع میں جو ذکر بھی پڑھے کافی ہے بشرطیہ کہ تین مرتبہ "سبحان اللہ" کی مقدار سے کمتر نہ ہو۔(۵۱)
جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ ذکر احتیاط واجب کی بنا پر تین مرتبہ "سبحان اللہ" کی مقدار سے کمتر نہ ہو۔
اگر ہم اس طرح صحیح فتویٰ بیان کریں: "ذکر تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سے کمتر نہ ہو" تو کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ اگر دوسرے مجتہد کا مقلد بھی اس پر عمل کرے گا تو اس نے احتیاط واجب پر عمل کرلیا ہے۔
ناقابل جمع اختلاف فتویٰ
کبھی کبھی مراجع تقلید کے فتاویٰ میں اس طرح تفاوت و اختلاف نظر پایا جاتا ہے جو ناقابل جمع ہوتا ہے؛ ایسی صورت میں تذکر دینا ضروری ہوتا ہے۔ مسئلہ کی وضاحت کے لئے ذیل میں چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں:
۱ ۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا نذر کرنا باطل ہے چاہے نذر کا تعلق مال سے ہو یا غیر مال سے، چاہے حق شوہر کی منافی ہو یا منافی نہ ہو۔(۵۲)
جبکہ اس کے مد مقابل یہ فتویٰ ہے کہ جب حق شوہر کے منافی ہو تو باطل ہے۔
ان دونوں فتووں کے اختلاف و تفاوت میں علمی اثر پایا جاتا ہے اور یہ قابل جمع بھی نہیں ہے۔
اگر اس موقع پر آپ کہہ دیں کہ تمہاری نذر باطل ہے تو جس مجتہد کا کہنا ہے کہ تمہاری نذر صحیح ہے اگر آپ کے بیان کردہ فتوی کے مطابق اپنی نذر پر عمل نہ کرے تو اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے۔
۲ ۔ حرام گوشت پرندوں کا فضلہ (بِیٹھ) نجس ہے(۵۳) ۔ جبکہ بعض مراجع کی نظر کے مطابق نجس نہیں ہے۔
۳ ۔ اگر عورت مرد کے برابر یا اس سے آگے کھڑی ہو تونماز باطل نہیں ہے جبکہ بعض مراجع تقلید فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہے۔(۵۴)
۴ ۔ اگر نامحرم عورت اور مرد خلوت میں نماز پڑھیں تو نماز باطل نہیں ہے ، جبکہ بعض مراجع عظام کے نزدیک باطل ہے۔(۵۵)
۵ ۔ سفر جس کا شغل ہے جیسے ڈرائیور وغیرہ تمام مراجع فرماتے ہیں کہ وہ سفر میں پوری نماز پڑھے لیکن سفر جس کے شغل کا مقدمہ ہے جیسے ڈاکٹر ایک شہر میں رہتا ہے لیکن اس کا مطب دوسرے شہر میں ہو تو اس مسئلہ میں بعض مراجع فرماتے ہیں کہ پوری نماز پڑھے گا جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قصر ہے۔(۵۶)
پس اگر یہاں ایک فتویٰ بیان کردیا جائے تو دوسرے مرجع کا مقلد اس پر عمل نہیں کرسکتا ہے اور اگر عمل کرے گا تو واجب ترک ہوجائے گا لہذا یہاں اختلافِ فتویٰ بیان کرنا ضروری ہے۔
یہ مختلف فتاویٰ میں ناقابل جمع ، تفاوت کی چند مثالیں پیش کی گئی ہیں جنکے بارے میں تذکر دینا ضروری ہے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ فتویٰ میں اس قسم کا تفاوت بہت کم موارد میں پایا جاتا ہے؛ لوگوں کو کس طرح خبردار کیا جائے؟
اگر موقع و محل اجازت دیں کلاس ہی میں اعلان کر دینا چاہیے اور اگر مصلحت کے خلاف ہو تو پھر مختلف مراجع کے مقلدین کو کاغذ پر لکھ کر دیدینا چاہیے۔یا مثلاً لفظ اختلافِ فتویٰ کے بجائے تفاوت اورفرق جیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیں اور اعلان کر دینا چاہیے کہ اس مسئلہ میں فرق یا تفاوت پایا جاتا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔
سوالات
۱. احکام کے درس میں کن چیزوں کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے؟
۲. وسواسی مسائل سے کیا مراد ہے مثال کے ساتھ بیان کریں؟
۳. اختلاف فتویٰ کی کتنی قسمیں ہیں مثال کے ساتھ بیان کریں؟
۴. کون سے تفاوت فتویٰ کے بارے میں مخاطبین کو تذکر دینا اور بتانا ضروری ہے مثال کے ساتھ بیان کریں؟
۵. قابل جمع تفاوت فتویٰ کی دو مثالیں بیان کریں۔
____________________
۴۳ ۔توضیح المسائل، م ۱۳۰۔
۴۴ ۔توضیح المسائل، م ۳۷۴۔
۴۵ ۔توضیح المسائل، م ۳۷۶۔
۴۶ ۔من لا یحضرہ الفقیہ، ج۱، ص ۳۴۔
۴۷ ۔توضیح المسائل، م ۱۵۰۔
۴۸ ۔توضیح المسائل، م ۲۴۹۔
۴۹ ۔توضیح المسائل ، م ۲۵۲۔
۵۰ ۔توضیح المسائل، م ۲۳۹۔
۵۱ ۔توضیح المسائل، م ۱۰۲۷۔
۵۲ ۔تحریر الوسیلہ، ج۲، القول فی النذر، م۳؛ توضیح المسائل، م ۲۶۴۰۔
۵۳ ۔توضیح المسائل، م ۸۵۔
۵۴ ۔توضیح المسائل، م ۸۸۶۔
۵۵ ۔توضیح المسائل، م ۸۸۸۔
۵۶ ۔توضیح المسائل، م نماز مسافر، ساتویں شرط۔
چودھویں نشست
۳ ۔ دلائل احکام
احکام کے درس میں جن چیزوں کے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ان میں سے ایک احکام کے دلائل ہیں۔
یاد رہے کہ حوزہ علمیہ میں درس احکام کی تدریس کے لئے تین مراحل طے کئے جاتے ہیں:
پہلا مرحلہ: فقہ غیر استدلالی؛ یعنی پہلے مرحلہ میں طالب علموں کو صرف مسائل پڑھائے جاتے ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کی دلیل بیان کرنے سے گریز کیا جاتا ہے کیونکہ طالب علم ابھی ابتدائی مرحلہ میں ہوتا ہے اس لئے وہ احکام کی دلائل کو سمجھنے کی خاطر خواہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے لہذا صرف توضیح المسائل وغیرہ سے مسائل بیان کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔
دوسرا مرحلہ: فقہ نیمہ استدلالی؛جب طالب علم اچھی طرح مسائل ذہن نشین کرلیتا ہے اور انھیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرلیتا ہے تو پھر اسے استدلال کے ساتھ فقہ پڑھانا شروع کردیتے ہیں جیسے شرح لمعہ، شرایع الاسلام۔ ان کتب کے ذریعے وہ کسی حد تک احکام کی دلائل سے واقف ہوجاتا ہے۔
تیسرا مرحلہ: فقہ تمام استدلالی؛ نیمہ استدلالی کے بعد تمام استدلالی فقہ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کتاب مکاسب اور درس خارج وغیرہ جو مکمل طور پر استدلال پر مشتمل ہوتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ نئے داخل ہونے والے طالب علم کے لئے پہلے مرحلہ سے درس کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے یا تیسرے مرحلہ سے؟
آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی ڈاکٹر مریض کے لئے جب نسخہ لکھتا ہے تو دلیل کے ساتھ دوا نہیں لکھتا ہے۔کیا کبھی کسی مریض نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس دوا کی دلیل بھی لکھ دیجئے! کیا آپ نے کبھی کسی مریض کی اس بات پرمذمت کی ہے کہ جب تمہیں دوا کی دلیل معلوم نہیں تھی تو دوا کیسے استعمال کرلی ہے؟ نہیں! کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کومتخصّص و ماہر اور قابل اطمینان سمجھتا ہوں کہ وہ بغیر دلیل کے نسخہ نہیں لکھ سکتا۔
شرعی احکام میں بھی یہی معاملہ پایا جاتا ہے جس طرح مریض کے لئے نسخہ لکھتے وقت دلیل بیان نہیں کرتے ہیں لیکن طبیب کالج میں اپنے شاگردوں کے لئے مرحلہ بمرحلہ استدلال پیش کرتے رہتے ہیں؛ اسی طرح عالم، عوام کے لئے احکام بیان کرتے وقت دلائل سے گریز کرتے ہیں لیکن مدارس و حوزہ علمیہ میں مرحلہ بمرحلہ استدلال پیش کرتے اور سکھاتے رہتے ہیں۔
بنابر ایں عوام کے لئے احکام کی دلائل بیان کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ غیر اہل فن کے لئے استدلال بیان کرنا نہ صرف مفید نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی مشکل ساز بھی ہوجاتا ہے۔کیونکہ مذکورہ مراحل طے نہ کرنے کی وجہ سے ان میں فہم دلائل کی قدرت نہیں پائی جاتی۔
ثانیاً غلط استفادہ کا احتمال بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے مثلاً اگر کوئی سائل کہے کہ معلوم نہیں مجھ پر کسی روزہ کی قضا ہے یا نہیں، مجھے یاد نہیں ہے اور آپ اس کے جواب میں کہیں کہ تم پر روزہ کی قضا نہیں ہے پھر استدلال بیان کرتے ہوئے کہہ دیں کہ اصلِ برائت کی بنا پر تم پر روزہ کی نسبت کوئی تکلیف نہیں ہے۔
آپ کے اس جواب پر وہ فوراً سوال کرے گا: یہ اصل برائت کیا چیز ہوتی ہے؟ ممکن ہے آپ جواباً کہیں کہ جب انسان شک کرے کہ اس پر کوئی تکلیف ہے یا نہیں تو اصل برائت جاری کرتے ہیں یعنی اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔
یہ شخص جو حوزہ علمیہ کا طالب علم نہیں ہے اور اس نے معالم، اصول فقہ، رسائل اور کفایہ جیسی کتب نہیں پڑھی ہیں بھلا اسے کیا معلوم کہ اصل برائت کہاں جاری ہوتا ہے اور کہاں نہیں؟! ایک دن بس یا ٹرین میں سفر کرتے ہوئے سخت سردی میں جب نماز صبح کے لئے سواری رکی تو دل میں کہنے لگا کہ مجھ پر نماز صبح واجب ہے یا نہیں؟ فوراً کہنے لگا کہ فلاں صاحب نے کہا تھا کہ جب کسی تکلیف کے بارے میں شک ہو کہ مجھے پر تکلیف ہے یا نہیں؟ تو اصل برائت کی بنا پر تکلیف نہیں ہے۔ لہذا مجھ پر نماز صبح واجب نہیں ہے۔
پس اس طرح لوگوں میں ناقص اور غلط استدلال قائم کرنے کا رواج پیدا ہوجائے گا۔ حوزہ علمیہ میں اتنا طویل عرصہ درس پڑھنے کا مقصد ہی عام و خاص، مطلق و مقید اور متعارض وغیرہ روایات کو سمجھ کر حکم خداوند کو حاصل کرنا ہے۔
آج ایسے افراد نظر آتے ہیں جو اہل فن بھی نہیں ہیں، نہ انھوں نے فقہ پڑھی ہے، نہ اصول سے واقف ہیں، نہ علم حدیث سے آشنائی رکھتےہیں،نہ علم رجال و درایہ جانتے ہیں، نہ حدیث صحیح و غیر صحیح میں تشخیص کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک حدیث پڑھ کر اپنے فہم ناقص کی روشنی میں اظہار نظر کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جو بات انھوں نے کہہ دی ہے وہی حرف آخر ہے۔ لیکن اہل فن خوب جانتے ہیں کہ یہ اہل علم نہیں ہیں۔
ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس طرح تو آپ لوگوں کی فکری سطح کو نیچا رکھنا چاہتے ہیں۔
اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ درحقیقت احکام بیان کرنے کا مقصد لوگوں کی فکری سطح ہی کو بلند کرنا ہے۔ جب آپ غیر استدلالی فقہ کا ایک دور مکمل کرلیں گے تو پھر استدلالی فقہ کی نوبت آئے گی۔
نیز ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس کا علان یہ ہے:"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ "(۵۷) مرد عورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ دین کا علان ہے: "اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّين "(۵۸) یعنی سرح کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ دین آواز دے رہا ہے: "اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ المَهۡدِ اِلیٰ اللَّحد "(۵۹) یعنی وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔
پس یہ وہ دین ہے جو معاشرے کے افراد کی فکری سطح کو ہر دور اور ہر حال میں بلند دیکھنا چاہتا ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے:
"لَیۡتَ السیّاط علیٰ رُئُوسِ اَصۡحَابِی حتّی یَتَفَقَّهُوا فِی الحلالِ و الحرامِ "(۶۰)
کاش میرے اصحاب کے سروں پر تازیانہ ہو تاکہ حلال و حرام کو سیکھ سکیں۔
بتائیے اس مکتب میں کہاں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی فکری سطح نیچی رہے، کون کہتا ہے کہ لوگ استدلال سے بے بہرہ رہیں؟!
ہمارا کہنا تو صرف یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اہل فن اور ماہرین سے رجوع کریں اور بیجا استفادہ سے پرہیز کریں۔
علوم دین کے حصول کے لئے شایان شان مدارس کھلے ہوئے ہیں اور اگر نگاہِ غائر سے دیکھا جائے تو تقلید مطلوب اصلی نہیں ہے بلکہ اجتہاد مطلوب اصلی ہے، تقلید تو درد کی دوا کا نام ہے کیونکہ تمام لوگوں میں حوزہ ہائے علمیہ میں جاکر تحصیل علوم دین کی استعداد نہیں پائی جاتی، کوئی اپنی معاشرتی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی اپنے گھریلوں مسائل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اجتماعی مسائل میں گھرا ہوا ہے، کسی کو شوق نہیں ہے۔
لہذا جو لوگ مدارس و حوزہ علمیہ میں نہیں جاسکتے ہیں اور احکام دین میں علمی مہارت سے بہرہ مند نہیں ہیں تو کم از کم انھیں دینی معلومات اور مسائل و احکام دریافت کرنے کے لئے ماہرین علوم دین اور متخصص افراد سے رجوع کرنا چاہیے۔
پس اہل فن اور باشعور افراد کے سامنے فقہی استدلال پیش کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور دیگر افراد کے لئے ضرورت نہیں ہے۔
یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ "کیا احکام بیان کرتے وقت آیت و روایت سے بالکل استفادہ نہیں کرنا چاہیے؟"
اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آیات و روایات جن میں قطعی متفق علیہ حکم بیان کیا گیا ہو یا کسی حکم کی فضیلت و آثار بیان کئے گئے ہیں تو انھیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (۶۱) ؛ تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کئے گئے تھے کہ شاید تم پرہیز گار بن جاؤ۔
اس آیت کریمہ میں روز کا قطعی حکم بیان کیا گیا ہے اور پوری تاریخ فقاہت میں کسی نے اس کے برخلاف فتویٰ نہیں دیا ہے۔ لہذا اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یا مثلاً خمس کے بارے میں آیت موجود ہے:
( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل ) (۶۲) ؛ "اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ اللہ، رسول، رسول کے قرابتدار، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لئے ہے"۔
یہ آیت خمس کے مصرف کو بیان کر رہی ہے اور تمام فقہاء کے نزدیک مصارف خمس یہی ہیں۔
نیز کسی حکم کی فضیلت و آثار بیان کرنے والی آیات یا روایات بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے مثلاً:"الْوُضُوءَ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ "(۶۳) وضو پر وضو کرنا نور بالائے نور ہے۔
اسی طرح جیسے( إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ) (۶۴) ؛اگرتم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے دو گنا بنا دے گا اور تمہیں معاف بھی کردے گا کہ وہ بڑا قدر دان اور برداشت کرنے والا ہے۔
اس قسم کی آیات و روایات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
۴ ۔ فلسفۂ احکام
فقہی و دینی احکام بیان کرتے وقت ہمیں تین قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
(الف)اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے حکم شرعی کو دریافت کرنا مثلاً سونے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ یا کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔
(ب) دلیل حکم کے بارے میں سوال کرنا جیسے وضو میں مسح کس آیات یا روایت سے ثابت ہے؟
(ج) فلسفۂ حکم کے بارے میں سوال جیسے:
۱. وضو میں مسح کیوں رکھا گیا ہے؟
۲. صبح کی نماز دو رکعت کیوں ہے؟
۳. روزہ کیوں واجب ہے؟
۴. ہر رکعت میں دو سجدے کیوں ہیں؟
یہ اور اس قسم کے دیگر بہت سے سوالات کئے جاتے ہیں جن کا تعلق فلسفۂ احکام سے ہے اور یہ سوالات آج کے دور میں نہیں بلکہ حضور سرور کائنات اور ائمہ علیہم السلام سے بھی کئے جاتے رہے ہیں۔
شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فلسفۂ احکام کے بارے میں مروی روایات کو علل الشرایع نامی کتاب میں یکجا کیا ہے۔ فلسفہ احکام کے لئے علیحدہ درس کا اہتمام کرنے یا فلسفہ احکام کے بارے میں کئے گئے سوال کا جوب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ احکام کی کلاس میں فلسفہ احکام بیان کرنےسے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے مگر یہ کہ کسی حکم کا فلسفہ قطعی اور بالکل واضح و روشن ہو کیونکہ بہت سے شرعی احکام و معارف دین ایسے ہیں جنکا فلسفہ بیان نہیں کیا گیا ہے لہذا اگر ہم فلسفہ بیان کرنا شروع کردیں گے تو لوگ پھر ہر حکم شرعی کا فلسفہ دریافت کرنا شروع کردیں گے اور جب ہم تمام احکام کا فلسفہ بیان کرنے سے قاصر رہیں گے تو لوگوں میں ایمان کمزور ہونا شروع ہوجائے گا اور رفتہ رفتہ عمل کا جذبہ جاتا رہے گا لہذا لوگوں کو پہلے اس بات کی طرف متوجہ کر دینا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کوئی بات اور حکم ، مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہے لہذا ہم شریعت اور قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ اللہ و رسول ؐ کی جانب سے ہمیں جو بھی حکم دیا گیا ہے ہم اسے بجا لانے کے پابند ہیں چاہے ہم اس کی علت و فلسفہ سے واقف ہوں یا نہ ہوں۔
جب چودہ سو سال قبل لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا:( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا ) (۶۵) ؛ "اے میرے حبیب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو آپؐ کہہ دیجئے کہ یہ امورِ الٰہی میں سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے"۔
یعنی اگر تم خدا پر اعتقاد رکھتے ہو تو یہ روح بھی اسی سے مربوط ہے۔ اگرچہ پیغمبر اکرم ﷺ روح کی حقیقت سے آشنا تھے اور قدرت تبین بھی رکھتے تھے لیکن فہم بشریت اس منزل پر نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو درک کرسکے مثلاً اگر آپ فقہی و منطقی یا فلسفہ وغیرہ کے کچھ احکام کسی پرندے کو سکھانا چاہیں تو بتائیے کہ یہ مسائل سمجھنے کی صلاحیت اس پرندے میں نہیں ہے یا آپ اسے سمجھانے سے قاصر ہیں؟!
نیز حضرت علی علیہ السلام سےنقل کیا گیا ہے کہ ہر رکعت میں دو سجدے بجا لانے کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ اول میں زمین پر پیشانی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاک سے ہیں، سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاک ہی سے وجود میں آئے ہیں دوسرے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مٹی ہی میں چلے جائیں گے اور دوبارہ سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن دوبارہ زمین سے اٹھائے جائیں گے۔
یہ حکمت قطعی اور بیان شدہ ہے لہذا اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور لوگوں کے ایمان میں استحکام کا باعث ہے۔
نیز پیغمبر اکرم ﷺ نے جیسے روزہ کے بارے میں فرمایا:"صُوموا تَصِحُّوا؛ روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہو(۶۶) "
یہ بھی روزہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے جیسا کہ قرآن کریم نے بھی روزہ کی حکمت کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (۶۷) صاحبان ایمان روزے تمہارے اوپر اسی طرح لکھ دیئے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے کہ شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔
سوالات
۱. شرعی احکام کے درس و تدریس کے مراحل کیا ہیں؟
۲. درس احکام میں دلائل احکام بیان کرنے سے پرہیز کی کیا وجہ ہے؟
۳. کون سے دلائل احکام بیان کرنا مناسب اور کون سے غیر مناسب ہیں؟
۴. احکام بیان کرتے وقت کتنے قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
۵. فلسفہ احکام بیان کرنے سے اجتناب کی کیا وجہ ہے؟
۶. کس صورت میں فلسفہ احکام بیان کرنا ٹھیک ہے؟
۱۸ رمضان المبارک ۱۴۳۳ ھ، بروز منگل ۷ اگست ۲۰۱۲ ء
____________________
۵۷ ۔امالی شیخ طوسی، ص ۴۸۸، ح ۱۰۶۹۔
۵۸ ۔میزان الحکمۃ، ج۸، ص ۲۶، ح ۱۳۸۵۷۔
۵۹ ۔بحار ا لا نوار، ج۱، ص ۳۵۸، ح ۷۶۵۔
۶۰ ۔۔
۶۱ ۔بقرہ (۲) آیت ۱۸۳۔
۶۲ ۔سورہ انفال (۸) آیت ۴۱۔
۶۳ ۔وسائل الشیعہ، ج۱، ص ۲۶۵، ح ۸۔
۶۴ ۔سورہ تغابن (۶۴) آیت ۱۷۔
۶۵ ۔سورہ اسراء (۱۷) آیت ۸۵۔
۶۶ ۔بحار الانوار، ج۹۳، ص ۲۵۵۔
۶۷ ۔سورہ بقرہ (۲) آیت ۱۸۳۔
فہرست
تشکر و امتنان ۵
گفتار مقدم ۶
پہلی نشست ۷
بیان احکام ۷
احکام سیکھنے اور بیان کرنے کی ضرورت و اہمیت ۷
تعلیم احکام کی جزاء ۷
تعلیم بغیر علم ممنوع ہے ۸
"روشِ بیانِ احکام" سیکھنے کی ضرورت ۸
سوالات ۹
دوسری نشست ۱۱
پہلا باب: بیان احکام کی تیاری کے مراحل ۱۱
دریچہ: ۱۱
۱ ۔ عوام کی ضرورت ۱۱
۲ ۔ فہم افراد: ۱۲
۳ ۔ مقررہ وقت: ۱۲
معیار ضرورت ۱۳
معیار فہم ۱۵
سوالات ۱۶
تیسری نشست ۱۷
مکمل و بغور مطالعہ ۱۷
انتخاب احکام ۲۰
سوالات ۲۰
چوتھی نشست ۲۱
احکام کی تنظیم و تقسیم بندی ۱ ۲۱
٭روش نموداری یا درختی ۲۱
٭ روش سوالی ۲۲
٭روش عنوانی ۲۲
٭روش تلفیقی ۲۲
روش نموداری یا درختی ۲۲
خمس ۲۲
دوسری قسم (وہ اموال جن پر خمس نہیں ہے) ۲۴
نکتہ ۲۴
تیسری قسم (اموال مشکوک) ۲۵
مسئلہ کی وضاحت کے لئے اس مثال پر غور کیجئے۔ ۲۵
مسائل خمس کی نموداری تنظیم و تقسیم بندی ۲۵
وضو جبیرہ کے احکام ۲۶
زخم، پھنسی یا شکستگی(۱۵) ۲۶
سوالات ۲۷
پانچویں نشست ۲۸
احکام کی تنظیم و تقسیم بندی ۲ ۲۸
سوالی تنظیم و تقسیم بندی ۲۸
وضو ۲۸
جوابات ۲۹
۱۱ ۔ شرائط وضو مندرجہ ذیل ہیں۔(۲۵) ۳۰
۱۲ ۔ چھ چیزوں کے لئے وضو کرنا چاہیے۔(۲۶) ۳۰
۱۳ ۔ وضو کو باطل کرنے والی چیزیں سات ہیں۔(۲۷) ۳۱
سوالات ۳۱
چھٹی نشست ۳۳
احکام کی تنظیم و تقسیم بندی ۳ ۳۳
عنوانی تنظیم و ترتیب ۳۳
احکام لباس ۳۳
نمازی کے لباس کی شرائط(۲۸) ۳۳
عام لباس (لباس حجاب) ۳۴
لڑکے لڑکیوں کے باہمی روابط ۳۴
تلفیقی تنظیم و ترتیب ۳۵
خلاصہ نویسی اور اس کا مطالعہ ۳۶
سوالات ۳۶
ساتویں نشست ۳۷
تقسیم بندی پر ایک نظر ۳۷
ڈاکٹر سے مربوط احکام کی تقسیم بندی ۳۷
٭علاج اور تجویز دوا ۳۷
٭ڈاکٹر (معالج) کا ضامن یا غیر ضامن ہونا ۳۸
۱ ۔ ڈاکٹر کے ضامن ہونے کے موارد ۳۸
۲ ۔ جن موارد میں ڈاکٹر ضامن نہیں (رفع مسئولیت) ۳۸
٭ڈاکٹر کی نظر کی حیثیت ۳۹
اثبات ِموت: ۳۹
ڈاکٹر کی معائنہ فیس ۳۹
آٹھویں نشست ۴۱
دوسرا باب: کیفیت بیان ۴۱
پہلی فصل: ضروریات ۴۱
الف: اصول ۴۱
اصول اول۔ سادہ گوئی ۴۱
چھوٹے چھوٹے اور رواں جملوں سے استفادہ ۴۳
سوالات ۴۴
نویں نشست ۴۶
اصول دوم۔بشارت دِہی ۴۶
سوالات ۴۹
دسویں نشست ۵۰
اصول سوم۔کلیدی و کلّی احکام اور بیان مثال ۵۰
شرائط مثال و مصداق ۵۰
سوالات ۵۲
گیارھویں نشست ۵۳
ب:روشیں ۵۳
روش عملی ۵۳
سوالات ۵۵
روش ہُنری ۵۷
پانی کی اقسام ۵۷
سوالات ۵۸
بارھویں نشست ۵۹
روش سوال و جواب ۵۹
مخاطبین سے سوال ۵۹
سوالِ مخاطبین ۵۹
مہارت جواب ۶۰
اقسام جواب ۶۰
(ب) کتبی جواب؛ ۶۱
سوال برائے سوال ۶۱
سوالات ۶۲
تیرھویں نشست ۶۳
دوسری فصل: ممنوعات ۶۳
۱ ۔ وسواسی مسائل ۶۳
۲ ۔ اختلاف فتویٰ ۶۴
قابل جمع اختلاف فتویٰ ۶۵
ناقابل جمع اختلاف فتویٰ ۶۷
سوالات ۶۸
چودھویں نشست ۷۰
۳ ۔ دلائل احکام ۷۰
۴ ۔ فلسفۂ احکام ۷۳
سوالات ۷۵