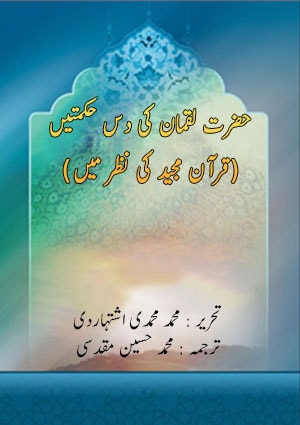یہ کتاب برقی شکل میں نشرہوئی ہے اور شبکہ الامامین الحسنین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں تنظیم ہوئی ہے
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
حضرت لقمان کی دس حکمتیں
(قرآن مجید کی نظر میں)
تحریر : محمد محمدی اشتہاردی
ترجمہ : محمد حسین مقدسی
حضرت لقمان کون ہے ؟
تاریخ کے عظیم اور سچے حکماء میں سے ایک حضرت لقمان علیہ السلام ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں دو مرتبہ بہت ہی عظمت کے ساتھ بیان ہوا ہے ۔(۱)
اور قرآن مجید کی اکیسویں سورہ اسی کے نام سے آئی ہے ۔ خدا وند متعال نے قرآن مجید میں اس کو اس لئے یاد کیا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت ہی اہم دس نصیحتیں کی ہیں جن کو سورہ لقمان میں پانچ آیتوں کےضمن میں بیان فرمایا ہے ۔(۲)
حضرت لقمان کی یاد اور ان کی دس نصیحتوں کو قرآن میں بیان کرنا اور قرآن کا ایک مکمل سورہ ان کے نام پر ہونا اور وہ بھی ایسی کتاب میں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ لقمان کا نام اور ان کی وہ حکیمانہ باتیں نصیحتوں کے طور پر قرآن میں ثبت کردے تاکہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں حق او رعرفان کے عاشقوں کیلئے ایک نمونہ عمل اورہدایت قرار پائے اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں ۔
اسی بنا پر یہاں پر سب سے پہلا سؤال یہ پیش آتا ہے کہ یہ لقمان کون تھے؟ کہاں پر رہےا تھے ؟ اور کس زمانے میں زندگی کزار رہے تھے ؟ کیا وہ کوئی پیغمبر تھے یا نہیں ؟
ان سؤالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لئے ہم درجہ ذیل مطالب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے ۔
۱۔ اس کا نام لقمان اور اس کا کنیہ ابو الاسود تھا ۔ وہ سرزمین سوڈان سے تھے جو افریقہ میں نوبہ نامی ایک شہر میں متولد ہوئے ۔
وہ رنگ کے اعتبار سے گندمی اور تقریبا کالے رنگ کا تھا اور تاریخ لکھنے والوں نے اس کو سیاہ رنگ اور بلند قامت والا جانا ہے۔
پس وہ افریقی نسل کا تھا لیکن بعض نے اس کو سرزمین فلسطین میں دریا کے کنارے (ایلہ ) نام کے ایک شہر سے ہونے کا ذکر کیا ہے۔(۳)
اس بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ حضرت لقمان کی عمر بہت ہی طولانی تھی اس نے بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ زندگی کی ہے حتی بعض روایات کے مطابق چار سو پیغمبروں کے ساتھ اس نے ملاقات کی ہے ۔(۴)
اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہےکہ وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے اور ظاہر بھی یہی ہوتا ہے ۔
بعض کے عقیدے کے مطابق حضرت داؤد کی حکومت سے کئی سال پہلے اور بعض کے مطابق حضرت داؤد کی حکومت کے دس سال بعد میں لقمان کی ولادت ہوئی ہے اور اس کی عمر حضرت یونس کے پیغمبر بننے تک جاری رہی ۔
حضرت داؤد کی حکومت کے دوران جالوت کے ساتھ جنگ کرنے میں لقمان نے شرکت کی اور جالوت کو قتل کرنے میں شریک ہوئے ۔
حضرت لقمان کے نسب کے بارے میں اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ :
(لقمان بن عنقی بن مزید بن صارون ) اور بعض نے ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کا خالہ زاد یا خواہر زاد قرار دیا ہے اور اس کا سلسلہ نسب میں ( ناحور بن تارخ ) کو جو کہ حضرت ابراہیم کے بھائی تھے بیان کیا ہے ۔
اس کی عمر بہت ہی طولانی تھی تقریبا دوسو سال سے پانچ سو ساٹھ سال تک اور اسی طرح سے ایک ہزار سے تین ہزار پانچ سو سال تک لکھی گئی ہے ۔
حضرت لقمان بہت ہی زاہد تھا اس کے نزدیک اس دنیا کی مثال ایک سایہ جیسی تھی ۔
وہ کچھ عرصے تک بنی اسرائیل کے ثروتمندترین شخص ( قین بن حسر ) کا غلام رہا اور اس کیلئے چوپانی کرتا رہا لیکن لقمان کی حکیمانہ باتوں سے متاثر ہو کر اس نے لقمان کو آزاد کر دیا ۔(۵)(۶)
لگتا ہے حضرت سلیمان نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ فلسطین بیت المقدس میں گزارا ہے اور اس کی قبر مبارک بھی فلسطین کے کسی ساحل ( ایلہ ) کے مقام پر واقع ہے ۔
کہتے ہیں کہ ان کی بہت ساری اولاد تھی ان سب کو اپنے ارد گرد جمع کرکے انکو نصیحتیں کرتے تھے اور بعض کے کہنے کے مطابق وہ ( یا بنی ! ) اے میرے بیٹے کہہ کر اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہوتے تھے لیکن حقیقت میں وہ اپنے سارے بیٹوں کو مخاطب قرار دیتے تھے بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب قرار دیتے تھے ۔
وہ اپنی اس محبت آمیز تعبیر سے ان کی محبت کو جلب کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو یہ سمجھائیں کہ میں آپ کے لئے دلسوز اور مہربان ہوں اور میری ان دلسوز نصیحتوں کو اپنی اچھائی کے خاطر قبول کریں ۔(۷)
جیسا کہ یہی طریقہ امام علی علیہ السلام کی اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کی ہوئی نصیحتوں میں دیکھا جا سکتا ہے ۔(۸)
استادمحقق آیت اللہ جوادی آملی لکھتا ہے کہ : لفظ ابن کا تصغیر بنی کی صورت میں ہونا ان کی دلجوئی اور اپنی محبت کی اظہار کے لئے ہے جیسا کہ امام علی علیہ کا کا وہ خط جو اپنے بیٹے امام حسن کو لکھا ( نہج البلاغہ مکتوب ۳۱ ) میں دیکھا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کس عاطفہ اور مہربانی کے ساتھ ان کی راہنمائی کی ہے اسی بنا پر ایسی فائدہ مند باتیں اور نصیحتیں کہ جن میں عطوفت اور رحمت موجود ہو وہ صرف امام علی اور حضرت لقمان کی باتوں میں ہی دیکھی جاسکتی ہے ۔(۹)
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے اگرچہ راوایات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں اگر ان سب نصیحتوں کو ہم جمع کرنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں بن جائیں گی ۔ لیکن پھر بھی حضرت لقمان کواچھی طرح سے پہچاننے کے لئے ایک حدیث کی طرف آپکی توجہ مبذول کرائیں گے ۔
وہ اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں :( يا بُنَيَ إِنِّي خدمت أَرْبَعَمِأَةِ نبي وَ أَخَذْت مِنْ كَلَامِهِم أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ , و هى : اذا كنت فى الصلوه فاحفظ قلبك, و اذا كنت على المائده فاحفظ حلقك, و اذا كنت فى بيت الغير فاحفظ عينك, واذا كنت بين الخلق فاحفظ لسانك ) ;
اے بیٹے میں نے چار سو پیغمبروں کی خدمت کی ہے اور ان کے گفتار سے چار چیزوں کو لیا ہے ,
۱۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو حضور قلب کا خیار رکھو ۔
۲۔ جب دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو حرام مال کھانے سے پرہیز کرو ۔
۳۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنی آنکھوں کو نامحرم سے محفوظ رکھو ۔
۴۔ اور جب انسانوں کے اندر رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو ۔(۱۰)
حضرت لقمان کی خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے بہت سارے سفر کئے اور مختلف لوگوں کے ساتھ رہے جیسا کہ علماء فقہاء وغیرہ کے ساتھ انکا رہنا سہنا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارا تجربہ کسب کیا ہے اس حد تک مولانا جلال الدین کے اس شعر کا مصداق بن گئے:
حاصل عمرم سه سخن پیش نیست
خام بدم پخته شدم سوختم
یعنی میری کل زندگی کا نتیجہ تین کلمات سے زیادہ نہیں ہے ۔ پہلئے خام تھا پھر پک گیا اور جل گیا ۔
حکمت کا معنی ا اور ان کے ابعاد :
حکمت اصل میں ( حکم ) کے مادہ سے ہے جو حرف کے وزن پر ہے جسکا معنی منع کرنا ہے کیونکہ یہ علم اور تدبیر جو کہ حکمت کے معانی میں سے ہیں انسان کو خلاف کاموں سے منع کرتی ہیں ان کو حکمت کہا جاتا ہے ۔
حکمت کے بہت سارے معانی بیان ہوئے ہیں جس کامفہموم بہت ہی وسیع ہے اور انہی میں سے ایک معرفت ہے اور اس جہان کے اسرار کی شناخت حاصل کرنا ہے اور حقائق سے آگاہی اور گفتار و عمل کے اعتبار سے حق تک پہنچنا اور خدا کو پہچاننا ہے ۔
اور اسی طرح سے نور الہی کے معنی میں ہے جو انسان کو شیطان کے وسوسوں اور گمراہی سے بچاتا ہے ۔
اور درس فلسفہ کو حکمت کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ علم حکمت کا ایک شعبہ حساب ہوتا ہے اور انسان کو حکمت کی راہ میں قرار دے سکتا ہے ۔
کلی طور پر حکمت کی دو قسمیں ہیں :
۱۔ حکمت نظری : جو تمام چیزوں کے بارے میں عمیق اور وسیع آگاہی رکھنا ہے ۔
۲۔ حکمت عملی : جو ایک معنوی حالت اور باطنی نور ہے جو انسان کو بلند مقام تک پہنچاتا ہے ۔
اس قسم کے بندے کو حکیم نام دیا ہے حکیم ایسے بندے کو کہا جاتا ہے جو عاقل اور ہوشیار اور مدبر ہو اور فکر و عمل کے اعتبار سے پاک اور خالص ہو ۔ خدا وند عالم حکیم مطلق ہے قرآن مجید میں خدا کی پاک ذات کو ۹۷ مرتبہ حکیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور لفظ حکمت قرآن مجید میں ۲۰ مرتبہ ذکر ہوا ہے اور تمام انبیاء کے نزول کا مقصد و ہدف اسی حکمت کی تعلیم دینا بیان ہوا ہے ۔(۱۱)
قرآن مجید کی نظر میں اس حکمت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خداوند متعال نے اس زمین کو اتنی وسعت کے باوجود اس کو بہت ہی کم اور ایک دہوکہ کا نام دیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔( قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ) (۱۲) یعنی زندگی کا سرمایہ بہت ہی کم ہے ۔
اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ( وَ مَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُور ) (۱۳) یعنی یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دہوکہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے ۔ لیکن اس حکمت کے بارےمیں کہہ رہے ہیں کہ( ..يُؤْتىِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتىَِ خَيرْا كَثِيرًا ) (۱۴) وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیرکثیر دیا گیا ہے۔
اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ (...الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ ;(۱۵) حکمت مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرکے فرماتے ہیں کہ(ِ أَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ ..، ونَوِّرْه بالحِكْمَة ،(۱۶) اپنے دل کو موعظہ کے ذریعے سے زندہ رکھو اور حکمت کے نور سے اسے جلا بخش دو ۔
اور حکمت کی اہمیت کے بارے میں یہی کافی ہے کہ فرمایا : (الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ (۱۷)
حکمت مؤمن کا گمشدہ مال ہے اگرچہ وہ منافق کے پاس ہی کیوں نہ ہو اس کو حاصل کرنا چاہیے ۔
اسی طرح سے کسی اور تعبیر کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ (إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ (۱۸) انسان کا دل اس کے جسم کی طرح سے سست اور تھکا ہوا ہوتا ہے اس کو خوش حال کرنے کے لئے نیک حکمتوں سے استفادہ کرنا چاہیے ۔
حکمت عملی کے آثار :
حکمت کا معنی اور اس کے آثار کے بارے میں ہم حضرت عیسی کی نصیحتوں میں پڑ ھتے ہیں کہ :بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَ النَّفْسَ نُورُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِنَّ الْحِكْمَةَ نُورُ كُلِّ قَلْبٍ وَ التَّقْوَى رَأْسُ كُلِّ حِكْمَة ; حقیقت میں آپ کو بتادوں کہ ہر چیز کی روشنی سورج کے ذریعے سے ہوتی ہے اور روح انسان کی روشنی حکمت کے ذریعے سے ہوتی ہے اور پرہیز گاری ہر حکمت کا نتیجہ ہوتا ہے ۔
اور اسی طرح سے فرماتا ہے کہ: (ُبِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَ الصَّقَالَةَ تُصْلِحُ السَّيْفَ وَ تَجْلُوهُ كَذَلِكَ الْحِكْمَةُ لِلْقَلْبِ تَصْقُلُهُ وَ تَجْلُوهُ وَ هِيَ فِي قَلْبِ الْحَكِيمِ مِثْلُ الْمَاءِ فِي الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ تُحْيِي قَلْبَهُ كَمَا يُحْيِي الْمَاءُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ وَ هِيَ فِي قَلْبِ الْحَكِيمِ مِثْلُ النُّورِ فِي الظُّلْمَةِ يَمْشِي بِهَا فِي النَّاس;
اور حق کے ساتھ آپ کو بتا دو ں کہ تلوار کو صیقل لگانا یا اس کو تیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جلا بخش دے اسی طرح سے حکمت بھی انسان کے دلوں کو جلا بخشتی ہے ۔(۱۹)
انسان کے دل میں حکمت کا ہونا بنجر زمین کو پانی دینے کی مانند ہے انسان کے دل کو زندگی دیتی ہے جس طرح سے پانی بنجر زمین کو زندہ کرنا ہے اور اسی طرح سے ایک نور کی طرح سے ہے جو رات کی تاریکی میں انسان اپنے ساتھ لیکر چلتا ہے ۔
حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس حکمت کے آثار کے بارے میں فرماتے ہیں ۔
(يَا بُنَيَّ تَعَلَّمِ الْحِكْمَةَ تُشَرَّفْ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَدُلُّ عَلَى الدِّينِ وَ تُشَرِّفُ الْعَبْدَ عَلَى الْحُرِّ وَ تَرْفَعُ الْمِسْكِينَ عَلَى الْغَنِيِ وَ تُقَدِّمُ الصَّغِيرَ عَلَى الْكَبِيرِ وَ تَجْلِسُ الْمِسْكِينَ مَجَالِسَ الْمُلُوكِ وَ تَزِيدُ الشَّرِيفَ شَرَفاً وَ السَّيِّدَ سُؤْدَداً وَ الْغَنِيَّ مَجْدا ...)
اے میرے بیٹے حکمت کی تعلیم حاصل کرو تاکہ شرافت کے بلند ترین درجہ پر پہنچ سکو چونکہ حکمت دین کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور غلام کو آزاد پر شرافت بخشتا ہے اور فقیر کو دولتمند اور امیر سے زیادہ ارجمند بناتا ہے چھوٹے کو بڑے پر مقدم کرتا ہے اور فقیروں کو بادشاہوں کی جگہ عطا کرتا ہے اور انسان کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے ۔
انسان کی زندگی اور دین دونو ں ہی اس حکمت کے علاوہ ممکن نہیں ہیں اور دنیا و آخرت کا کام صرف اسی حکمت پر موقوف ہے جس طرح سے خدا کی اطاعت کسی حکمت کے بغیر ہو تو بغیر روح والے جسم کی طرح ہوگی یا بغیر پانی والی زمین کی طرح سے ہے ۔
بس جس طرح سے جسم بغیر روح کے اور زمین پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی ہے اسی طرح سے حکمت کے بغیر خدا کی اطاعت بھی بے نشاط ہوگی ۔(۲۰)
حضرت لقمان کا حکیم ہونا اور اس کا راز :
سورہ لقمان کی آیت ۲۱ میں ہم پڑھتے ہیں کہ :( وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الحْكْمَةَ ) ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے ۔
یہ آیت اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ وہ خدا وند عالم جو حکیم مطلق ہے حضرت لقمان کے حکیم ہونے کو قبول کرتا ہے اور اس کو حکمت سے بہرہ مندکیا ہے ۔
اور یہ کہ حضرت لقمان پیغمبر تھے یا نہیں ؟ اس کے بارے میں قرآن مجید سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے اور روایات میں بھی ان کے پیغمبر ہونے کی نفی ہوئی ہے ان میں سے جو روایت پیغمبر اسلام سے نقل ہوئی ہے کہ فرمایا : (حَقّاً أَقُولُ لَمْ يَكُنْ لُقْمَانُ نَبِيّاً وَ لَكِنَّهُ كَانَ عَبْداً كَثِيرَ التَّفَكُّرِ حَسَنَ الْيَقِينِ أَحَبَّ اللَّهَ فَأَحَبَّهُ وَ مَنَّ عَلَيْهِ بِالْحِكْمَة ;(۲۱)
حقیقت میں بتادوں کہ حضرت لقمان کوئی پیغمبر نہیں تھے بلکہ وہ زیادہ فکر کرنے والے انسان تھے خدا پر اس کا ایمان اور یقین کامل تھا خدا کو دوست رکھتا تھا اور خداوند عالم بھی اس کو دوست رکھتا تھا اور خدا وندعالم نے ان کو حکمت جیسی نعمت سے نوازا ۔
اب سؤال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے کس طرح سے وہ حکمت کے اس بلند ترین درجے پر پہنچ گئے ؟
کہ خداوند متعال نے ان کی بعض حکمتوں کو نصیحت کے طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ۔
اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت لقمان ایک پاک اور مخلص انسان تھے سیر و سلوک اور عرفان کے راستے میں اس نے بہت ہی زحمت اٹھائی ہے اور اسی طرح ہوائے نفس کی مخالفت اور بہت ساری مشکلات کو تحمل کرنے کی وجہ سے خدا وند عالم نے ان کے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹ دئیے اور لقمان کی یہی قابلیت خداوندعالم کا لطف قرار پائی ۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ : (مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً إِلَّا جَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِه ;(۲۲) جو بھی خدا کی خاطر اگر چالیس دن تک اخلاص پیدا کریں تو خداوند عالم ان کے دل اور زبان حکمت جاری کرتا ہے ۔ روایت میں آیا ہے کہ کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا آپ نے یہ علم اور حکمت کہاں سے حاصل کی ہے ؟ جبکہ آپ نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا ۔(قَدَّرَ اللَّه و أداءِ الأمانَة و صدقِ الحَديثِ، و الصمت (۲۳) خدا کی چاہت اور امانت داری اور سچائی اور اپنی زبان پر کنٹرول کرنے سے یہ مقام حاصل ہوا ہے ۔
حضرت لقمان کو حکمت عطا ہونے کے راز کو امام صادق علیہ السلام اس طرح سے بیان کرتے ہیں خدا کی قسم جو حکمت لقمان کو عطا ہوئی ہے وہ نہ ہی اس کی جمال و خوبصورتی کیوجہ سےتھی اور نہ ہی ان کے حسب ونسب اور مال و دولت کی وجہ سے بلکہ وہ پاک اور پرہیز گار انسان تھے جو ہمیشہ خدا کے حکم کی اطاعت کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹرول کرتے تھے اور بہت زیادہ فکر کرنے والے تھے ۔
اور بعض موارد کے علاوہ کبھی سوتے نہیں تھے کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے کبھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے اور قضاے حاجت کے وقت ایسی جگہ نہیں بیٹھتے تھے جہاں پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے ۔ وہ بہت ہی باوقار انسان تھے ،کبھی بے جا ہنستے نہیں تھے اور کبھی بھی غصہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کبھی مذاق کرتے تھے اور دنیوی امور میں کبھی خوشحال یا غمگین نہیں ہوتے تھے۔ حضرت لقمان کی کئی بیویاں تھیں جن سے بہت زیادہ اولاد تھے ان میں سے بہت سارے مر گئے تو حضرت لقمان خدا کی خوشنودی کے خاطر ان کے موت پر کبھی روئے نہیں ۔
اور جب دو بندوں کے درمیان لڑائی ہوتی تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے تھے اور جب تک ان کے درمیان صلح نہیں ہوتی ان کو چھوڑ تے نہیں تھے ۔ جب کسی سے کوئی اچھی بات سنتے تھے تو اس کی تفسیر اور منبع و ماخذ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ علماء اور فقہاء کے ساتھ زیادہ بیٹھا کرتے تھے جو بھی اس کے معنوی فائدہ کے لئے ہوتا تھا اس پر زیادہ توجہ دیتے تھے ۔ بے ہودہ کاموں سے بیزار تھے اسی وجہ سے خداوند متعال نے ان کو حکمت جیسی خصلت سے نوازا ۔(۲۴)
نتیجہ اور جمع بندی :
انہی مطالب اور دوسرے مطالب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت لقمان اگرچہ نسل اور قوم کے اعتبار سے بہت ہی کم درجے پر تھے لیکن علم و عمل اور ریاضت اور کمال کے مراحل کو طی کرنے میں بہت بڑے مقام حکمت تک پہنچ گئے مثال کے طور پر سلمان ایک عجمی تھے لیکن خود سازی اور ریاضت کے اعتبار سے تکامل تک پہنچ چکے تھے جس کیوجہ سے امام علی علیہ السلام نے ان کو لقمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اس کی شان میں فرمایا : (قَالَ بَخْ بَخْ سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ مَنْ لَكُمْ بِمِثْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ عَلِمَ عِلْمَ الْأَوَّلِ وَ عِلْمَ الْآخِر ;(۲۵)
واہ واہ سلمان کا کیسا مقام ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں آپ کہاں سے سلمان کے درجے پر پہنچ پاوگے وہ لقمان حکیم کی طرح ہے جو گزشتہ اور آئندہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں ۔
لقمان کی زبان سے حکمت کا جاری ہونا :
پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ فرمایا ایک دن حضرت لقمان بستر پر آرام فرما رہے تھے ۔ اچانک کوئی آواز سنی جو اس کو مخاطب قرار دے کر کہہ رہی تھی اے لقمان کیا آپ چاہتے ہو کہ خداوند متعال آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے تاکہ لوگوں کے درمیان حق کی قضاوت کرو ؟
تو لقمان نے کہا اگر میرا پرودگار اس حکم پر مجھے اختیار دے دیں تو میں اس قضاوت کے امتحان کو کبھی قبول نہیں کرونگا لیکن اگر میرا خدا اس کام پر مجھے حکم دے تو میں ان کے حکم کی اطاعت کرونگا چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر ایسی ذمہ داری مجھے دی ہے تو وہ ضرور میری مدد کرے گا ۔
اور فرشتے نے جبکہ لقمان ان کو نہیں دیکھ رہے تھے ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں اس قضاوت کو قبول نہیں کرتے ہیں ؟ تو لقمان نے جواب دیا اگرچہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا بہت ہی ضروری بھی ہے اور سخت بھی ہے چونکہ ہر طرف سے ظلم و ستم اور لغزشوں کے امواج اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں ۔ اگر خدا وند عالم انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو لوگ نجات پائیں گے وگرنہ انہی لغزشوں کے امواج میں غرق ہونے کا امکان ہے ۔ بس کل قیامت کے دن انسان کے ذلیل وخوار ہونے سے بہتر ہے کہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے اور جو بھی اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو وہ کبھی بھی اس دنیا کو حاصل نہیں کرسکے گا اور اس کی آخرت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی ۔
فرشتے لقمان کی ان حکیمانہ اور منطقی باتوں سے متعجب ہوئے اس کے بعد لقمان کو نیند آگئی خداوند متعال نے لقمان کے دل میں حکمت کا نور ڈال دیا اور جب وہ نیند سے اٹھے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہونے لگی ۔
لقمان اگرچہ حضرت داؤد کے مشکلات میں مددگار تھے حضرت داؤد ان کو کہنے لگے طُوبَى لَكَ يَا لُقْمَانُ أُعْطِيتَ الْحِكْمَة.(۲۶) اے لقمان آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ خدا نے آپ کو حکمت عطا کی ہے ۔
لقمان کی دس حکمتیں قرآن میں:
حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی ہوئی بعض نصیحتیں کو خدا وند عالم نے قرآن مجید کی سورہ لقمان میں پانچ آیتوں کے ضمن میں بیان کیا ہے (سورہ لقمان آیات ۱۳۔ ۱۶۔ ۱۷ ۱ ۔۱۸۔ ۱۹۔ )
اور وہ دس نصیحتیں درجہ ذیل ہیں :
۱۔ توحید ۔ ۲۔ معاد۔ ۳۔ نماز ۔ ۴۔ امر بالمعروف ۔۵۔ نہی عن المنکر ۔ ۶۔ صبر و استقامت ۔۷۔ تواضع ۔۸۔ خود خواہی سے دور رہنا ۔ ۹۔ چلتے وقت اعتدال کا ہونا ۔ ۱۰۔ بات کرتے وقت اعتدال کا ہونا ۔
یہی نصیحتیں حکمت نظری اور عملی ، اعتقادی اور عبادی ، اجتماعی اور سیاسی ،تقویتی اور اخلاقی کا ایک مجموعہ ہیں ۔ اگر خدا نے چاہا تو ہم ان میں سے ہر موضوع کے بارے میں آئندہ مقالوں میں بحث کریں گے اس امید سے کہ لقمان کی ان نصیحتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ان کو سعادت تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیں ۔
پہلی حکمت : توحید اور خدا شناسی :
حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :( « يَابُنىََّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم ) ;(۲۷) لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: اے بیٹا! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے ۔
حضرت لقمان نے اپنی پہلے سخن کو وہی انبیاء والا سخن قرار دیا چونکہ تمام انبیاء کا مقصد و ہدف یکتا پرستی کی تبلیغ تھی اور ہر قسم کے شرک سے پرہیز کرناتھا لہذا حضرت لقمان نے بھی اپنی تمام نصیحتوں کا اساس توحید خدا وندی کو قرار دیا اس کی علت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یکتا پرستی اور خدا کی وحدانیت سے منحرف ہوکر اس کو شریک قرار دینا بہت ہی بڑا ظلم ہے ۔
لقمان کی اس نصیحت میں دو چیزیں توجہ کی طالب ہیں ۔
پہلی یہ کہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ شرک سے پرہیز کریں اور خداکو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور خدا کو بے ہمتا اور یکتا جانیں ۔
اور دوسری یہ کہ شرک قرار دینا ایک بہت بڑا ظلم ہے ۔
اور پہلے مطلب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا اور اس جہان کو خلق کرنے والا کوئی ضرور ہے تو انسان کو غیر جانبدار نہیں رہنا چاہیے چونکہ بہت سارے ایسے دلائل موجود ہے کہ اس جہان کو خلق کرنے والے خدا وند عالم کی ذات پاک ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان کی اپنی عجیب و غریب خلقت اور دوسرے موجودات کی عجیب خلقتوں کے ہوتے ہوئے خداوند عالم کی ذات پر اعتقاد نہ رکھیں ۔
اب جب خداوند عالم کو تلاش کیا تو پھر اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کو قبول کریں اور اس کو بے ہمتا جانیں اور کسی کے ساتھ شریک قرار نہ دیں چونکہ خدا کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر جہت سے بے انتہاء ہے ۔ اسی بناپراس کی کوئی بھی صفت اس کی ذات سے خارج نہیں ہے کیونکہ وہ کمال مطلق ہے اس کی صفات کا اسکی ذات سے خارج ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے ۔
توحید کے اقسام :
توحیدکے راستے میں قدم اٹھانے اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہونے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طرح سے شرک کے مختلف اقسام ہیں اسی طرح سے توحید کے بھی کئی اقسام ہیں۔عقائد کے مشہور و معروف علماء نے توحید کے چار اقسام بیان کئے ہیں۔ ۱۔ توحید ذاتی ۲۔ توحید صفاتی ۔ ۳۔ توحید عبادی یعنی عبادت و پرستش کے لائق صرف خداوند عالم کی ذات ہے ۔ ۴۔ توحید افعالی ۔ اور ان میں سے ہر ایک کئی قسموں میں تقسیم ہوتی ہے ۔ اور اسی طرح سے شرک کی بھی کئی قسمیں ہیں ۔
جیسا کہ ذاتی شرک ہے : یعنی خداکی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا ذاتی شرک کہلاتا ہے مثال کے طور پر دو خداؤں کی پرستش کرنے والوں کی طرح جو دو خداؤں - اہریمن یعنی تمام برائیوں کا خدا اور - یزدان یعنی تمام اچھائیوں اور نیکیوں کا خدا ۔ اور اسی طرح سے مسیحی جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا خدا ( اب - ابن - اور روح القدس ) ہے جو ان تین سے ملکر بنا ہے ۔
اور صفات میں شرک کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ خداکی تمام صفات اس کی ذات سے جدا ہیں ۔
اور عبادت میں شرک یعنی خداکی پرستش اور عبادت میں کسی کو شریک قرار دیناہے چنانچہ تمام انبیاء کا مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کامقصد یہی تھا کہ وہ لوگ اپنی عبادتوں میں دوسرے خداؤں کو شریک قرار دیتے تھے ۔
اوراسی طرح سے شرک افعالی جو کہ توحید افعالی کے مقابل میں ہے یعنی انسان کا اس طرح عقداہ رکھنا اس جہان کی خلقت یا اس کے نظام تدبیر میں کسی اور کو بھی شریک قرار دینا ۔ لہذا انسان کو ہر قسم کے شرک اور قیاس سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ خدا کی وحدانیت کے راستے پر چل سکے ۔ شرک اس حد تک نفرت انگیز ہے کہ انسان کو حتی ایک لحظہ کے لئے بھی اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا : «ٍإِيَّاكَ أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ إِنْ نُشِرْتَ بِالْمِنْشَارِ أَوْ قُطِعْتَ أَوْ صُلِبْتَ أَوْ أُحْرِقْتَ بِالنَّار ;(۲۸)
خداکو شریک قرار دینے سے حتی ایک لحظہ کے لئے بھی پر ہیز کیا کرو چاہیے ایسا کرنے میں تمہیں ایک آرے سے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کریں اور دروازے پر لٹکایا ہی کیوں نہ دیں یا آگ کے اندر جلایا ہی کیوں نہ دیں ۔
خداوند عالم قرآن مجید میں مشرکین کے عذاب کے بارے میں فرمارہا ہے :( وَ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيرْ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ فىِ مَكاَنٍ سَحِيق ) . جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا آسمانوں سے گر گیا پھر یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دے(۲۹)
تاریخ اسلام میں آیا ہے کہ ہجرت کی آٹھویں سال میں ثقیف نام کا ایک قبیلہ گزرا ہے جو سب کے سب مشرک تھے ایک دن مدینے میں پیغمبر اسلام کے پاس آکر کہنے لگے ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہماری دو شرطوں کو مان لیں پہلی یہ کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم تین سال تک اسی بت ( لات ) کی ہی پوجا کریں اور دوسری یہ کہ اس نماز کا جو حکم ہے وہ ہم سے اٹھالیں تو پیغمبر اسلام نے ان کی اس خواہش کو رد کردیا کیونکہ ان کی پہلی خواہش سے شرک ثابت ہوتا تھا اور دوسری خواہش توحید کی نشانی کو چھوڑنا ثابت کرتی تھی پھر نماز کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا : «لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لا صَلَاة فِيه (۳۰)
ایسا دین کہ جس میں نماز نہ ہو اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے ۔
شرک اور بت پرستی انسان کے لئے سب سے بڑی آفت اور کمالات انسان کو جلانے اور نابود کرنے کے لئے آگ شمار ہوتی ہے
پیغمبر اسلام نے سخت ترین شرائط میں بھی اس شرک کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے جب مشرکین مکہ نے یہ سازش کی کہ پیغمبر اسلام ان کی باتوں کے قبول کریں اور ہم ایک سال تک آپ کے آئین کی پیروی کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے آئین کی پیروی کریں تو اس وقت ہم آپ کو بہترین امتیازات دینگے لیکن پیغمبر اسلام نے ان کے جواب میں فرمایا : «معاذ الله ان اشرك به غیره;
میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ خدا کا شریک قرار دوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بعض خداؤں پر ہاتھ رکھیں اور ان سے تبرک حاصل کریں تو ہم آپ کی سچائی کا اعلان کریں گے اور آپ کے خدا کی پرستش کریں گے لیکن پیغبر اسلام نے ان کو اس طرح سے جواب دیا میں خداوند متعال کے حکم کا انتظار کررہا ہوں اسی وقت سورہ کافرون نازل ہوا اور پیغمبر اسلام نے اس کے مطابق کہا میں کبھی بھی آپ کے آئین کو قبول نہیں کرونگا ۔(۳۱)
پیغمبر اسلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ فرمایا : جو بھی سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا تو گویا اس نے قرآن مجید کے ایک چوتھائی حصہ کو پڑھ لیا اور اس سے شیاطین درو ہو جاتے ہیں ۔(۳۲)
اس تعبیر سے اس بات کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ قرآن مجید کے ایک چوتھائی حصہ بت پرستی اور شرک کے ساتھ مقابلہ کرنے کو بیان کرتا ہے کہ جس کا خلاصہ قرآن کی اس سورہ میں بیان ہوا ہے اور شرک سے پرہیز کرنے کی تاکید ہوئی ہے اور اس سرکش شیطان کے مقابلہ میں اپنا دفاع کریں تاکہ شیطان انسان پر مسلط نہ ہو سکے
اور جالب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں تقریبا دو سو سے زیادہ مرتبہ شرک ا ور غیر توحیدی چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور جہاں پر صرف شر ک سے منع کیا گیا ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مشرکین کے لئے سخت غذاب ہے جیسا کہ فرمایا :
«( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) ; اے ایمان والو! مشرکین تو بلاشبہ ناپاک ہیں لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں(۳۳)
کسی اور جگہ پر فرمایا : «( وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظيما ) ; اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔(۳۴)
توحید ناب پیغمبراسلام اور امیر المؤمنین کے کلام میں :
اس بحث کو مکمل کرنے کے لئے ہم یہاں پر پیغمبر اسلام اور امام علی علیہ السلام کی دو باتوں کو ذکر کریں گے ۔
۱۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا کہ علم کا بلند ترین مرحلہ کونسا ہے ؟ تو پیغمبر اسلام نے اس کے جواب میں فرمایا خداوند متعال کی شناخت جس طرح سے وہ لائق ہے اس طرح سے پہچاننا۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ یہ جان لیں کہ خداکا نہ کوئی مثل ہے اور وہ نہ ہی کسی سے شباہت رکھتا ہے بلکہ اس کو واحد اور خالق و قادر مطلق جانے ۔ نہ ہی اس کاکوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس جیسا ہے اور یہی خدا کی حقیقی معرفت ہے ۔(۳۵)
۲۔ جنگ جمل میں اسی جنگ کی حالت میں ایک شخص امیر المؤمنین کے پاس آکر کہنے لگا کیا آپ یہی کہتے ہیں کہ خداوند عالم واحد ہے؟ تو اسی وقت امیر المؤمنین کے اصحاب نے اعتراض کیا کہ یہ سؤال کرنے کا کونسا وقت ہے؟ لیکن امام علی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو اپنے حال پرہی چھوڑ دو یہ مر د عرب جو ہم سے چاہتا ہے وہی ہم اپنے دشمنوں سے چاہتے ہیں اور اسی کی خاطر لڑتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا اے اعرابی میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ خدا واحد ہے اس کے چار معانی ہیں ان میں سے دو صحیح اور دو غلط ہیں۔
۱ ۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ خدا واحد ہے یعنی عدد مراد ہو یعنی عدد کے اعتبار سے ایک ہے جو دو کے مقابل میں ہے تو اسی صورت میں خدا ایک ایسا واحد اور یکتا ہوگا کہ جس کے لئے دوسرے کے نہ ہونے کا تصور ہی نہیں اس بناپر یہ اعداد میں داخل نہیں ہوتاہے۔
۲۔ اور کوئی کہہ دے کہ خدا واحد ہے اور اس کا مقصد جنس کا ایک ہو تو یہ بھی صحیح نہیں ہیں کیونکہ اس کا مفہوم خداکو تشبیہ دینے کے معنی میں ہوتا ہے ۔ لیکن وہ جو دومعانی صحیح و ثابت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایسا یکتاہے کہ جو کسی سے شباہت نہیں رکھتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ خدا (احدی المعنی ) ہے یعنی وہ وجود کے اعتبار سے نہ ہی عقل و وہم میں اور نہ ہی خارج میں قابل تجزیہ و تقسیم نہیں ہے ۔(۳۶)
شرک کا سب سے بڑا ظلم ہونا :
شرک کے باطل ہونے پر بہت سارے دلائل موجود ہیں حضرت لقمان کی اس شرک کے بطلان پر موجود دلیلوں میں سے ایک جامع دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے چونکہ شرک کرنا خدا پر ظلم ہے کیونکہ ایسے موجودات مثال کے طور پر بت وغیرہ خدا وند عالم کے ہمتا قرار پائے ہیں مثلا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کالی چیونٹی حضرت سلیمان کی ہمتا قرار پائی ہے تو کیا اس طرح کا مقایسہ کرنا حضرت سلیمان پر ظلم نہیں ہے ؟ اور دوسری طرف سے خدا کی اس خلقت پر ظلم ہے چونکہ اس کو حقیر اور ناتواں جاننے سے اس کی فکر کو ٹھیس پہنچتا ہے جس کی وجہ سے وہ فکری انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے پست تر ایک چیز کو خدا کا ہمتا قرار دیا ہے ۔
اور تیسرا یہ کہ شرک انسان کو خدا کے بلند ترین درجہ عبودیت سے گرا کر ذلت اور غیر خدا کی عبادت کرنے کا باعث بنتاہے ۔
حضرت لقمان کی باتیں اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ تمام چیزوں میں عدالت اور انصاف ہونا چاہیے اور عدالت ہر چیز کو اپنے محل اور صحیح جگہ پر قرار دینا ہے اور ظلم اس کا مخالف ہے ۔
یہاں پر اس نکتے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ شرک کے لئے بہت سارے معانی اور اقسام بیان ہوئے ہیں ۔ اور حضرت لقمان کی نصیحت تمام پیغمبروں کی اطاعت اور ہر قسم کے شرک کرنے سے پرہیز کرنے کے بارے میں ہے ۔اس بنا پر شرک آشکار(بت پرستی ) اور شرک خفی ( یعنی ریا اور خود نمائی ) کرنا بیا اس شرک میں شامل ہے ۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے شرک رات کی تاریکی میں کالے کپڑوں پر چیونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ مخفی ہے ۔
اور اس کا ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنی حاجت کو خداسے طلب کرنے کے لئے اپنی انگوٹھی کو انگلی میں گماتا رہتا ہے ۔(۳۷)
توحید کے اقسام میں سے ایک خداوند عالم کے سامنے تسلیم ہونا ہے اور اس کا عکس خدا کے احکام میں شک و تردید میں پڑنا ہے جو ایک قسم کا شرک شمار ہوتا ہے ۔ اسی لئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مؤمن خداوسول کی بتائی ہوئی چیز کے مخالف عمل کریں یا اس کے اندر ایسی حالت پیدا ہو جائے حتی وہ زبان پر نہ بھی لائے پھر بھی یہ شرک شمار ہوتا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے سورہ نساء کی آیت ۶۴ کو مثال کے طور پر تلاوت فرمایا ۔(۳۸)
دوسری حکمت : حساب وکتاب :
جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت توحید اور خداشناسی کے بارے میں تھی اور ابھی حضرت لقمان کی دوسری نصیحت کے بارے میں تشریح کریں گے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح نصیحت کرتے ہیں : «( يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطيفٌ خَبيرٌ ) ;(۳۹ )
اے بیٹے! اگررائی کے دانے کے برابر بھی کوئی (اچھی یا بری) چیز کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تواللہ اسے یقینا نکال لائے گا یقینا اللہ بڑا باریک بین، خوب باخبر ہے۔
اس آیت میں دو اہم مطلب بیان ہوئے ہیں ۔
۱۔ خداوند متعال کی قدرت کی وسعت اور اس کا تمام جہان پر احاطہ جوکہ خداشناسی میں سے ہے اورخدا کے نظام اور حساب رسی کو بیان کرتی ہے ۔
۲۔ اور خود انسان کے حساب وکتاب کا مسئلہ : یعنی انسان کو خود اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے اعمال کا خود حساب و کتاب کریں اور اپنی کردار و رفتار کو خدا کے احکام کے ساتھ ہماہنگ کریں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ دنیا اور آخر ت دونوں میں انسان سے سخت حساب ہونا ہے ۔ ایک دن اس کو حساب وکتاب کے میزان پر کھڑ ا ہونا پڑے گا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں یا آخرت میں ملنا ہے ۔
اس آیت میں خردل کی مثال دی گئی ہے اس سے مراد کسی جڑی بوٹی کانام ہے کہ جس کے کالے کالے اور چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اس آیت میں اس کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال اگرچہ اس خردل کے مانند چھوٹی ہی کیوں نہ ہوں اس کا بھی حساب ہو جائے گا ۔
خداوند عالم کے حساب کا میزان اس طرح سے ہے کہ اگر انسان کے اعمال میں سے ذرہ بھی کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو خدا اس کو بھی اپنے میزان حساب میں حاضر کردے گا ۔
اور آسمانوں کی عظمت اور اس کے حیرت انگیز وسعت کی طرف توجہ کرنے سے ہم خدا کے اس میزان حساب و کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ۔ آج کے دور میں علم سائنس نے یہ ثابت کردیا ہے کہ بعض ستاروں کا زمین سے فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ لاکھوں سال تک ایک نور کی ضرورت ہے جو زمین تک پہنچ جائے اور اس بات کی توجہ دیتے ہوئے کہ اس نور کی جو حرکت ہے اس کی سپیڈ ایک سکنڈ میں تین لاکھ کلو میٹر تک ہے ۔ جب انسان کے اعمال میں سے ایک چھوٹا ساعمل بھی انہی ستاروں میں سے کسی ایک ستارے کے کونے میں بھی ہو تو وہ بھی خدا اپنے میزان حساب میں حاضر کرے گا ۔ لہذا حضرت لقمان کی یہ نصیحت انسان کو متوجہ کرتی ہے انسان اس خطرے کی گنٹی کی طرح ہمیشہ ہوشیا ر رہے ۔
آسمانوں کی وسعت اور اس کی عظمت ایک مثال سے بہتر سمجھ میں آئے گی مثال کے طور پر سورج کی روشنی تقریبا آٹھ منٹ تک زمین پر پہنچ جاتی ہے اور زمین سے سورج کا فاصلہ تقریبا ۲۴ ملیون فرسخ ہے ۔ اب زمین سے ان ستاروں کا فاصلہ کتنی وسعت کے ساتھ ہونا چاہیے یہاں سے ہمیں آسمانوں کی وسعت اور عظمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔
حضرت لقمان خدوند عالم کے اس احاطہ علمی اور اس کی قدرت اور حساب کتاب کو یاد کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ہوشیار کرتاہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو اور اپنے اعمال کا حساب کرکے خود کو کنٹرول میں رکھو تاکہ کل حساب و کتاب کردیتے وقت سرخرو ہو جاؤ اور خدا کے لطف اور انعام کےمستحق ہوجائے ۔
حساب و کتاب قرآن کی دوسری آیتوں میں :
علم خداکی وسعت اور حساب و کتاب کے بارے میں قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی بیان ہوا ہے انہی میں سے ایک سورہ سبا آیت ۳ میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ :لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرُ إِلاَّ في كِتابٍ مُبين : آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی (کوئی چیز) اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ اس سے بڑی مگر یہ کہ سب کچھ کتاب مبین میں ثبت ہے.۔
جب ہم کلمہ حساب کو قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہ کلمہ قرآن مجید میں مختلف شکلوں میں تقریبا ۴۷ مرتبہ ذکر ہوا ہے انہی میں سے اٹھ آیتوں میں سریع الحساب کا لفظ ذکر ہوا ہے یعنی خداوند عالم کی حساب رسی بہت ہی سرعت کے ساتھ بغیر کسی سستی اور کاہلی کے انجام پائے گی ۔ اور اسی طرح سے پانچ آیتوں میں قیامت کے دن کیلئے یوم الحساب آیا ہے ۔(۴۰) جو قیامت کے مشہور ترین ناموں میں سے ہے ۔
اور اصل میں قیامت اس لئے ہے کہ سورہ انبیاء آیت ۴۷ میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرمایا: «( وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفى بِنا حاسِبين ) ; اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہو گا اور اگر رائی کے دانے برابر بھی (کسی کا عمل) ہوا تو ہم اسے اس کے لیے حاضر کر دیں گے اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ نامہ اعمال کا میزان اور ان اعمال کو ( رقیب و عتید ) دو فرشتوں کے ذریعے سے ثبت کرنا جیسا کہ قرآن مجید سورہ ق آیت ۱۸ میں تکرار کے ساتھ آیا ہے یہ سب کل قیامت کے دن خداوند عالم کے حساب و کتاب کو بیان کرتا ہے لہذا انسان کو حساب و کتاب کے مسئلہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے ۔
حساب و کتاب روایات کی نظر میں :
پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی روایات میں حساب و کتاب کے بارے میں بہت ساری روایات تقل ہوئی ہیں انہی میں سے کچھ روایتوں کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے ۔
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے «حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا ;(۴۱)
اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے اپنا حساب وکتاب کرو ۔
امام علی علیہ السلام نے فرمایا : «قَيِّدُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْمُحَاسَبَة ;(۴۲)
حساب و کتاب کے ذریعے سے اپنے اوپر کنٹرول کرو ۔
اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے «أَكْيَسُ الْكَيِّسِينَ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ ،;(۴۳)
چالاک ترین انسان وہ ہے جو اپنا حساب و کتاب خود کرتاہے ۔
اور امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے «حَقٌ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ يَعْرِفُنَا أَنْ يَعْرِضَ عَمَلَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونَ مُحَاسِبَ نَفْسِهِ فَإِنْ رَأَى حَسَنَةً اسْتَزَادَ مِنْهَا وَ إِنْ رَأَى سَيِّئَةً اسْتَغْفَرَ مِنْهَا لِئَلَّا يَخْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ :(۴۴)
ہر وہ مسلمان جو ہمیں جانتا ہے اور ہماری امامت کو قبول کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ہر صبح و شام اپنا حساب و کتاب کرے اگر اپنے اعمال میں نیکی پائے تو اس میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کرے اور اگر اپنے اعمال میں گناہ پائے تو استغفار اور توبہ کیا کرے تاکہ کل قیامت کے دن رسوا نہ ہو جائے ۔
روایات میں جو مختلف مسائل ذکر ہوئے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ انسان کے اعمال کا پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کے سامنے پیش ہونے کا ہے اور یہ موضوع بھی اسی حساب و کتاب کو بیان کرتا ہے اس طرح سے کہ پورے ہفتے میں ہمارے اعمال کئی مرتبہ پیغمبر اور ائمہ معصومین کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اسی موضوع کے بارےمیں اصول کافی میں تقریبا چھ روایتیں آئی ہیں انہی میں سے پہلی روایت امام صادق سے نقل ہوئی ہے «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَعْمَالُ الْعِبَادِ كُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارُهَا وَ فُجَّارُهَا فَاحْذَرُوهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُه; (۴۵)
نیکو کار اور فاسق لوگوں کے اعمال ہر صبح اور شام کو پیغمبر اسلام کے سامنے پیش ہوتے ہیں لہذا اپنے برے کردار سے بچو اور قرآن مجید میں خداوند عالم کا کلام سورہ توبہ کی آیت ۱۰۵ میں اسی معنی پر دلالت کرتا ہے ۔
اور کہدیجیے: لوگو! عمل کرو کہ تمہارے عمل کو عنقریب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے اور پھر جلد ہی تمہیں غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹا دیا جائے گا پھر وہ تمہیں بتا د ے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو ۔
اور اسی طرح اعمال کے ائمہ معصومین کے سامنے پیش ہونے کے بارےمیں بھی کئی روایات ذکر ہوئیں ہیں ۔(۴۶)
مکہ میں ہارون رشید اور امام کاظم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا اس میں ہارون نے امام سے کئی سؤالات پوچھے کہ دین کیا ہے ؟ اور اس دین کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کے بارے میں بیان کریں تو امام علیہ السلام نے کچھ اعداد گن کر کہا کہ دین سے مراد یہی اعداد ہیں ؟ تو ہارون ہنستے ہوئے کہنے لگے میں آپ سے دین کے بارے میں پوچھتاہوں اور آپ مجھے ریاضی کے اعداد گن کر بتا رہے ہیں تو امام کاظم نے فرمایا : «َ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَ الدِّينِ كُلَّهُ حِسَاب; کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس دین میں سارا حساب ہی ہے ؟
پھر اسی کی تائید میں سورہ انبیاء کی آیت ۴۸ کی تلاوت کرنے لگے ۔
حساب و کتاب کے بارے میں تجزیہ و تحلیل :
محاسبہ اورحساب و کتاب یہ ہیں کہ انسان اپنے کردار کی حفاظت کریں اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اس کو اسلامی احکام کے ساتھ ہماہنگ کریں تاکہ صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو جائیں ۔
روایات میں آیا ہے کہ کسی نے امیر المؤمنین سے پوچھا محاسبہ سے مراد کیا ہے ؟ اور انسان کس طرح سے اپنا محاسبہ کریں ؟ تو امام نے فرمایا : جب صبح ہو جائے تو انسان اپنے روز مرہ کاموں میں مشغول ہو جائیں اور جب رات ہو جائے تو اپنے وجدان کی طرف رجوع کریں اور اس کو مخاطب قرار دے کر کہیں ! اے وجدان ! آپ کی عمر کا ایک اور دن گزر گیا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور خداوند عالم اس دن کے بارے میں تم سے سؤال کرے گا کہ تم نے اس دن کو کیسے گزارا ؟ کونسا عمل انجام دیا ؟ اور کیا خدا کا شکر ادا کیا یا نہیں ؟ اور کسی بندے کے غم کو برطرف کیا یا نہیں ؟ اور اس کی غیبت پر اس کی آبرو کو محفوظ رکھا یانہیں ؟ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے خاندان میں ان خدمات کو محفوظ رکھا یانہیں ؟ اور کسی مسلمان کی مدد کی یانہیں ؟
اگر انسان کا وجدان اس کے جواب میں کہے کہ میں نے نیک کاموں کو انجام دیا ہے تو اس کو خداوند عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر اس کے جواب میں گناہ آجائے تو اس وقت انسان کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے ۔(۴۷)
پیغمبر اکر م کا فرمان ہے کہ انسان اسوقت تک پرہیز گار نہیں بن سکتا ہے جب تک اپنا حساب و کتاب نہ کرے جس طرح سے وہ اپنا شریک سے حساب کرتا ہے اسی طرح سے اپنا محاسبہ کرے اور اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں اور اس کے کپٹرے کہاں سے آئے ؟ کیا وہ حرام مال سے ہاتھ آئیں ہیں یا حلال مال سے ؟ ( ۴۸)
اسی بنا پر علماء اخلاق نے محاسبہ کرنے کا طریقہ اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جب مؤمن صبح کو نیند سے اٹھتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان پانچ مراحل کو طے کریں ۔ ۱ ۔ مشارطہ ۔۲۔ مراقبہ ۔ ۳۔ محاسبہ ۔ ۴۔ معاقبہ ۔ ۵۔ مکافئہ ۔
یعنی سب سے پہلے انسان اپنے ساتھ شرط باندھے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کرونگا پھر اسی کی مراقبت کرے تاکہ کوئی گناہ انجام نہ دے اور اس کا وعدہ نہ ٹوٹ جائے اس کے بعد جب رات ہوتو اپنا محاسبہ کرے کہ کیا دن میں کوئی گناہ اس سے سرزد ہوا یانہیں؟ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اپنی سرزنش کرے اور توبہ کرنے کی کوشش کرے ۔
اور پانچواں مرحلہ میں اپنے انجام دئیے ہوئے ان گناہوں کی تلافی میں نیک اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرے ۔
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ : «ثَمَرَةُ الْمُحَاسَبَةِ إِصْلَاحُ النَّفْسِ .(۴۹) محاسبہ کرنے کا نتیجہ انسان کی روح اور نفس کی اصلاح ہے۔
شیخ عباس قمی نے شیخ بہائی سے نقل کیا ہے کہ ( ثوبہ بن صمۃ ) نام کا ایک شخص ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا تھا وہ ایک دن اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ساٹھ سال کی عمر گزر گئی جو اکیس ہزار پانچسو دن بن جاتے ہیں اگر میں ہر دن ایک گناہ انجام دیتا تو میرے اکیس ہزار پانچسو گناہ بن جاتے اور اس وقت میں خدا کو کیا جواب دیتا لہذا وہ اپنے اس حساب کتاب سے غمگین ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں اور اسی حالت میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ۔(۵۰ )
اور اسی طرح سے نقل کرتے ہیں کہ ( احمد بن ابی الجواری ) جو کہ پرہیز گاری میں بہت ہی مشہور و معروف تھے ۔اس کا ایک استاد ( ابو سلیمان دارانی ) تھا اس کے مرنے کے ایک سال بعد اسکو خواب میں دیکھا اور احوال پرسی کرنے کے بعد اس سے کہنے لگا اے استاد آپ کے مرنے کے بعد خداوند عالم نے آپ سے کیسا سلوک کیا ؟ تو ابو سلیمان نے اس کے جواب میں کہا اے احمد ! میں ایک دن دمشق میں باب الصغیر کے کنارے سے گزر رہا تھا ایک بوڑ ھے کو دیکھا جو اونٹ پر لکڑیاں لادھے ہوا تھا میں نے اس کے اونٹ سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا لیکن ابھی مجھے معلوم نہیں کہ میں نے اس کو خلال کے طور پر استعمال کیا تھا یا اسے پھینک دیا تھا ؟ جب سے میں مرا ہوں ابھی تک اسی عذاب میں گرفتار ہوں کہ میں نے اجازت کے بغیر وہ لکڑی کیوں اٹھائی ؟ اور میں ابھی اسی کا حساب دے رہا ہوں ۔
اس عجیب واقعہ کونقل کرنے کے بعد محدث قمی فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیات اس واقعہ کی تصدیق کرتی ہیں جیسا کہ خداوند متعال نے حضرت لقمان کے قول کونقل کرتے ہوئے فرمایا : «( إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صَخْرَة ) ...»(۵۱)
اگررائی کے دانے کے برابر بھی کوئی (اچھی یا بری) چیز کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تواللہ اسے یقینا نکال لائے گا
اور اسی طرح سے امام صادق کا یہ قول بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ فرمایا: «اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّهَا لَا تُغْفَر; چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرو اور ان کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھو کیونکہ ان کے انجام دینے والے جب تک توبہ نہیں کریں گے بخشے نہیں جائیں گے ۔
امام علیہ السلام کے ایک شاگرد ( زید بن شحام ) کا کہنا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا چھوٹے گناہ سے مراد کیا ہے ؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا : «الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَقُولُ طُوبَى لِي لَوْ لَمْ يَكُنْ لِي غَيْرُ ذَلِكَ ; ایک شخص گناہ انجام دیتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے کہ میرا صرف اسی کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں ہے ۔(۵۲)
اور اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے شاگردوں اور مسلمانوں کو حساب و کتاب سمجھانے کے لئے ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ کسی سفرپر گئے اور جب ایک صحرا میں ٹہرنے لگے تو پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا جاکر کوئی لکڑیاں جمع کرو تاکہ کھانے کا بندوبست کریں تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس بیابان میں کہاں سے لکڑی آئے گی ؟ تو پیغمبر نے کہا جو ملے وہ لیکر آو تو اصحاب چلے گئے اور لکڑیاں لیکر آئے ان سب کو جمع کیا تو لکڑیوں کا ایک ڈھیر بن گیا تو پبغمبر نے اصحاب کو کہا «هَكَذَا تَجْتَمِعُ الذُّنُوب ; انسان کے گناہ بھی اسی طرح سے جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسی چھوٹے چھوٹے گناہ جو آپ کی نظر میں بہت ہی حقیر اور چھوٹے ہیں ان سے بچو ! چونکہ ان چھوٹے گناہوں کا بھی حساب ہے اور جب یہ جمع ہونگے تو گناہوں کا ایک ڈھیر بن جائے گا ۔(۵۳)
کسی اور روایت میں صفوان کہتا ہے کہ عبد اللہ بن حسن ( یعنی امام حسن مجتبی کا پوتا اور امام صادق کے درمیان کسی سیاسی بحث پر اختلاف پیدا ہوا اور بہت سارے لوگ جمع ہوگئے ۔ لوگوں کے مجمع میں ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں اسی طرح سے رات ہوگی تو ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن صبح کو میں جلدی گھر سے نکلا راستے میں امام صادق کو عبد اللہ کے گھر کے دروازے پر دیکھا جو عبداللہ کی کنیز سے کہہ رہا تھا کہ جاکر عبداللہ کو بتاؤ کہ میں دروازے پر انتظار کررہا ہوں۔ جب عبداللہ گھر سے نکلا تو امام کو غمگین حالت میں دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں ؟ تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کل کی اس بحث میں جب اختلاف ہوا تو رات کو گھر جاکر جب قرآن کی یہ آیت( وَ الَّذينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِساب ) ) (۵۴) پڑ ھ کر میں بہت ہی متاثر ہوا گویا کہ یہ آیت میں نے نہیں پڑھی تھی لذا میں ابھی صلح کرنے آیا ہوں دونو ں ایک دوسرے کو آغوش میں لیکر بہت رونے لگے ۔(۵۵)
تیسری حکمت : نماز قائم کرنا :
حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت کرتے ہوئے فرمارہے ہیں( يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ ) ؛اے بیٹے نماز کو قائم کرو(۵۶)
پہلی والی دونوں نصیحتیں خدا شناسی اور معاد و حساب و کتاب کے بارے میں تھیں ۔ حضرت لقمان نے دین کے بنیادی اصول یعنی خدا شناسی و معاد اور قیامت کے دن حساب و کتا ب ہونے کے بارے میں بیان کیا پھر اس کے بعد اب اس دین کی فرع یعنی نماز کو قائم کرنے کے بارے میں نصیحت کرتا ہے فقط نماز کو انجام دینے کے لئے ہی نہیں بلکہ اس کو ہمیشہ کے لئے قائم و دائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے کیونکہ یہ دن رات کی جو نماز ہے وہ خالق حقیقی سے ملنے کے لئے ایک بہترین وسیلہ ہے ۔
خدا شناسی انسان کو قیامت اور روز جزاء (مالک یوم الدین )کی یاد دلاتی ہے اور روزانہ کی یہ تمرین انسان کو صراط مستقیم اور حساب و کتاب کی یاد دلاتی ہے ۔
نماز کے بارے میں مختلف مسائل بیان ہوئے ہیں جو بحث کرنے کے قابل ہیں لیکن ان میں اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ جو حضرت لقمان نے بیان کیا ہے وہ اس نماز کو قائم کرنا ہے ۔
اقامہ اصل میں قیام کے مادہ سے لیا گیا ہے جو اس مطلب کو بیان کرتا ہے کہ نماز کو طوطی کی طرح نہیں رٹے بلکہ اس کو بطور عبادت انجام دے اور ان الفاظ کےمفہوم کو روح وروان کے ساتھ ہماہنگ کرے اور نماز کے اس پرچم کو ہمیشہ سربلند رکھے ۔
مناسب یہی ہے کہ ہم یہاں پر نماز کے بارے میں تین اہم مطالب کو بیان کریں ۔
۱۔ نماز کی اہمیت :
نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ دین اسلام میں مختلف تعبیروں کے ساتھ اس کا معنی بیان ہوا ہے ۔
کبھی نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے (الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّي ننماز دین کا ستون ہے(۵۷) اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے (الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّين نماز دین کی پناہ گاہ ہے(۵۸)
حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ«يا بُنَيَ أَقِمِ الصَّلاةَ فَإِنَّمَا مَثَلُهَا فِي دِينِ اللَّهِ كَمَثَلِ عُمُدِ فُسْطَاط ؛ اے بیٹے نماز کو قائم کرو چونکہ دین اسلام میں نماز خیمے کےستون کی مانند ہے اس خیمے کا ستون جب تک استوار اور مضبوط رہے گا تب تک خیمہ سالم رہے گا لیکن اگر اس خیمے کا ستون ٹوٹ جائے تو پھر خیمہ گر جائے گا اور اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی(۵۹)
اسی طرح سے کبھی اس نماز کو بہترین عمل قرار دیا ہے جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ : «مَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هذِهِ الصَّلَاةِ ؛ میں نے خدا کی شناخت اور اس کی معرفت کے بعد نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا ہے(۶۰)
اس نماز کا ایک مخصوص وقت ہے جو خدا وند عالم کی طرف سے معین ہے اسی کو ایک بہترین موضوع قرار دیا ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے ابو ذر نے پیغمبر اسلام سے پوچھا نماز کیا چیز ہے ؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا نماز بہترین موضوع ہے( ۶۱)
اسی طرح سے کبھی اس نماز کو اسلام کا چہرہ قرار دیا ہے جیسا کہ پیغمبر کا فرمان ہے (لْيَكُنْ أَكْثَرُ هَمِّكَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا رَأْسُ الْإِسْلَامِ .
آپ کی تمام ہمت اور اہتمام اس نماز کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ نماز دین اسلام کا سر ہے(۶۲)
امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے ہر چیز کے لئے ایک چہرہ ہوتا ہے اور دین اسلام کا چہرہ نماز ہے ۔(۶۳)
اور روایات اسلامی میں معصومین کی زبان سے دوسری تعبیر ات بھی بیان ہوئیں ہیں جیسا کہ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے نماز خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ ہے نماز خدا کی خوشنودی کا باعث ہے اور نماز خیر العمل یعنی ایک بہترین عمل ہے۔ نماز پیغمبر اسلام کے آنکھوں کا نور ہے ۔ نماز انسان کی تمام آلودگیوں کو پاک کرنے کی ایک نہر ہے۔ نماز گناہوں کا کفارہ ہے اور انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اسی نماز پر موقوف ہے اور نماز وہ سب سے پہلا کام ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن پہلا سوال ہو گا
اور اس نماز کی اہمیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک عبادی امر ہے جو انسان کی خلقت کی ابتداء سے ہی تھا اور ابھی تک باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پہلے سے ہی موجود تھی لیکن ہر زمانہ کے اعتبار سے مختلف تھی ۔ حضرت ابراہیم جوکہ توحید کا فاتح شمار ہوتا ہے جب اسماعیل اور ہاجر کو اس غیر آباد صحراء میں چھوڑ آیا تو اپنی دعاؤں میں اس طرح سے فرمایا اے خدا میں اپنی اولاد کو اس غیر آباد صحراء میں کہ جہاں پر آپ کا حرم ہے چھوڑ رہاہو ں (لِيُقِيمُوا الصَّلاة؛ تاکہ قائم کریں(۶۴) ۔
کسی اور مورد میں جب خدا وند عالم نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے کی حالت میں اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا تو بارگاہ الہی میں شکر گزاری کرتے ہوئے اس طرح سے دعا کی «رَبِ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي ؛خدایا مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے دیں ۔(۶۵)
جیسا کہ آپ نے ملاحہر کیا کہ حضرت ابراہیم اپنی تمام چاہتوں سے پہلے نماز کو قائم کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں ۔ اور خدا وند عالم نے حضرت اسماعیل کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا : «( وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاة ) ؛ حضرت اسماعیل اپنے خانوادے کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتا تھا ۔(۶۶ )
اور حضرت عیسی علیہ السلام جب گہوارہ میں باتیں کرنے لگے تو اپنی نبوت اور عبودیت کا اعلان کرنے کے بعد اس نماز کو قائم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا : « «( وَ أَوْصانِي بِالصَّلاة ) ؛ خداوند عالم نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے ۔(۶۷)
خلاصہ کلام یہ کہ نماز بااہمیت ترین حکم ہے جو خدا وند عالم نے انسان کو عطا کیا ہے اور یہ بلدک ترین اطاعت الہی ہے جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا«ُإِنَ طَاعَةَ اللَّهِ خِدْمَتُهُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ خِدْمَتِهِ تَعْدِلُ الصَّلَاة ؛ اطاعت الہی میں یعنی زمین پر خدا کی خدمت کرنا اور کوئی بھی خدمت نماز کے برابر نہیں ہوسکتی ۔(۶۸)
اور جالب بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی اس نورانی زندگی اور اس کی سیرت میں ملتا ہے کہ ہجرت کے نویں سال طائفہ (طی ) قبیلہ طائف کی نمائندگی میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مذاکرہ کے بعد وہ اس شرط پر تسلیم ہونے کو قبول کیا کہ ان سے نماز کا حکم ہٹادیا جائے لیکن پیغمبر اسلام نے بہت ہی سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ «ُ لَا خَيْرَ فِي دِين لَا صَلَاة معه؛ ایسا دین کہ جس میں نماز نہ ہو اس میں خیر و برکت نہیں ہے(۶۹) اور یہی بات نماز کی عظمت اور پیغمبر اسلام کی نگاہ میں نماز کی اہمیت کو بیان کرتی ہے ۔
۲۔ نماز کے آثار اور اسکا فلسفہ :
جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اہم چیز نماز کو قائم کرنا ہے اور یہ تعبیر اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ نماز ہمیشہ قائم ہونی چاہیے اور انسان کااجتماعی اور فردی طور پر یہی انگیزہ ہونا چاہیے ایسی نماز کہ جس کو خداوند متعال مقبول اورحقیقی نماز جانتا ہے ۔ ایسی نماز کی اہمیت اسوقت ہے کہ جب یہی نماز دین کا حقیقی ستون بن جائے اور ملکوت اعلی میں مومن کی معراج بن جائے تو ایسی نماز اپنے تمام شرائط کے ساتھ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے ۔ اسی بنا پر ایک نماز کامل کو اس کے آثار میں ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے آداب اور اسرار کے بارے میں جان لینا چاہیے اور اسے اپیک زندگی میں ان کا اظہار کرنا چاہیے ۔
نماز کا مقصد اور ہدف صرف اس کا خاکہ اور ڈھانچہ ہی نہیں بلکہ اس کا روح اور باطن ہونا چاہیے نماز میں ظاہری رکوع اور سجود پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے جو اس نماز کا ظاہری جلد شمار ہوتا ہے حقیقت میں اس کا مغز اور باطن حقیقی نماز شمار ہوتا ہے ۔
جب ہم قرآن مجید اور روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس نماز سے مربوط آیات اور روایات کو دیکھتے ہیں کہ جن میں اس نماز کے اسرار اور اس کے فلسفہ کی طرف اشارہ ہوا ہے اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز اسی فلسفہ اور انہی رازوں کیوجہ سے کامل ہوئی ہے جیسا کہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ فرمایا : (( أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ) ..؛ اور نماز قائم کریں، یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے ۔(۷۰)
کسی اور آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ (( و أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ لذكري ) ؛اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔(۷۱)
بنا بر این نماز کا اصل راز انسان کا اپنے روح و روان سے خدا وند عالم کو یاد کرنا ہے اور یہی خدا کی یاد انسان کا خدا سے رابطہ کرنے کا باعث بنتی ہے اور انسان کی اصلاح اور کمال تک پہنچنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسی نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور تمام پریشانیوں کو دور کرکے انسان کو آرامش اور سکون کا سبب بنتی ہے اور حقیقت میں خدا کی یاد انسان کی خود سازی کا باعث بنتی ہے ۔
قرآن کی نظر میں غافل انسان خسارے میں ہیں اور ایسے شخص کی عاقبت یہ ہے کہ اس کی زندگی بہت ہی سخت اور ناگوار گزرے گی اور آخرت میں بھی وہ نابینا ہو گاجیسا کہ قرآن فرمارہا ہے ۔ اے ایمان والو! تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔(۷۲)
نماز جو کہ خدا کی یاد کرنے کا باعث ہے وہ انسان کی زندگی میں برے آثار کو پاک کرتی ہے اور اس کے خسارے میں ہونے کے بدلے میں خوشبخت اور بینا بنادیتی ہے ۔
انسان کے اندر موجود غرائز میں میں سے ایک غریزہ حرص اور لالچ ہے جو تمام گناہوں اور فسادوں کی جڑ ہیں لیکن نماز میں ایسی خاصیت ہے کہ انسان کے اندر موجود وہ بری صفت حرص اور بے تابی اور لالچ کو نابود کرتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان ھلوع اور حریص خلق ہوا ہے انسان یقینا کم حوصلہ خلق ہوا ہے۔جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے ، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے ، سوائے نمازگزاروں کے ، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں،
اور جن کے اموال میں معین حق ہے ۔(۷۳)
محمد بن سنان کہہ رہا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے نماز کے فلسفہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نماز کے فلسفہ اور اس کے آثار کے بارے میں فرمایا : نماز پڑھنے کی علت یہ ہے کہ آپ ۔
۱۔ خدا کی ربوبیت کا اقرار کرے ۔
۲۔ خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دے ۔
۳۔ خدا کی بارگاہ میں اس کے سامنے تواضع اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا ۔
۴۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور بخشش کا تقاضا کرے ۔
۵۔ اور ہر دن خدا کی تعظیم کے لئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے ۔
۶۔ ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اس طریقے سے کہ تمہارے اندر سے غرور مستی اور غفلت وغیرہ ختم ہو جائے ۔
۷۔ ہمیشہ خدا کو یاد کرنا چونکہ نماز خدا کو نہ بھولنے کا باعث بنتی ہے یہی یاد خدا ہے کہ جو انسان کو غرور اور تکبر سے روک دیتی ہے اور تمام گناہوں اور ہر قسم کے فساد سے روک دیتی ہے ۔(۷۴)
انہی آثار کی طرف توجہ دیتے ہوئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں « الصَّلَاةُ حِصْنٌ مِنْ سَطَوَاتِ الشَّيْطَان؛نماز شیطان کے حملوں کے مقابل میں ایک مضبوط قلعہ ہے ۔(۷۵)
عالم ربانی شیخ عبد اللہ شوشتری ( متوفی ۱۰۲۱) جو علامہ مجلسی کے زمانے کے مشہور ترین عالم شمار ہوتے تھے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب نماز جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہوئے اس کا بیٹا کسی سخت بیماری میں مبتلا تھا اسی لئے وہ بہت ہی پریشان تھے نماز جمعہ پڑھانے میں مشغول ہوئے جب وہ نماز کی دوسری رکعت میں سورہ منافقوں کی اس آیت ۹ «( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّه ) ؛ کو پڑھنے لگا تو اس کو بار بار تکرار کرنے لگا ( اگر چہ وقت کے ہوتے ہوئے نماز میں آیات کو تکرار کرنا جائز ہے ) پھر بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بعض لوگوں نے اس تکرار کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے میرا بیٹا کسی بیماری کی وجہ سے بسترے میں ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اپنے بیٹے کی یاد آگئی تو میں نے اس آیت کو باربار تکرار کیا تاکہ اپنے نفس پر کنٹرول کرسکوں جس طرح سے یہ آیت خدا کو یاد کرنے کا کہہ رہی ہے میں نے دوسروں کو اپنے دل سے نکال دیا اور یہ فرض کرنے لگا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے اور اس کا جنازہ میرے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور میں خدا سے غافل نہیں ہوا ایسا وقت تھا کہ پھر میں نے آیت کو تکرار نہیں کیا( ۷۶)
۳۔ نماز کے قبول ہونے اور اس کے اسرار میں تامل :
تمام عبادات میں سے اہم ترین مسائل کہ جن کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہیں جیسا کہ نماز ہے جس میں اہم ترین مسئلہ اس کا قبول ہونا ہے اور نماز کا قبول ہونا اس کی کامل ترین شرائط میں سے شمار ہوتا ہے اور نماز کا قبول ہونا بھی اس کے اثر پر موقوف ہے جو انسان کی پاکسازی میں دخالت رکھتی ہے جیسا کہ قرآن مجید کا فرمان ہے «( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقين ) ؛ اللہ تو صرف تقویٰ رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے۔(۷۷) یعنی گناہ آلود اعمال کبھی بھی قبول نہیں ہوتے ہیں ۔
امام صادق علیہ السلام اپنے کسی کلام میں فرماتے ہیں انسان کی زندگی کبھی پچاس سال سے بھی گزر جاتی ہے لیکن خدا وند عالم اس کی ایک نماز کو بھی قبول نہیں کرتا ہے پس اس سے بڑھ کر اور سخت چیز کیا ہو گی ؟ پھر اس کے بعد فرمایا «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْحَسَنَ فَكَيْفَ يَقْبَلُ مَا يُسْتَخَفُّ بِه ؛ اعمال نیک اور شائستہ کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں پس حقیر اور ہلکا سمجھ کر انجام دیا جانے والا عمل کیسے قبول ہوگا(۷۸) ممکن ہے یہاں پر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ ہم کہاں سے جان لیں کہ ہماری نماز یں قبول ہوئیں ہیں یا نہیں ؟
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنی پاکسازی میں اس نماز کی تاثیر کیطرف متوجہ رہے جس انداز اور مقدار کے مطابق اس پر اثر ہوا ہے اسی اندازے کے مطابق اس کی نماز قبول ہوئی ہے ۔ اسی لئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کی نما ز قبول ہوئی ہے یانہیں ؟ تو اس کے لئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اس کی نمازیں ان برے کام انجام دینے سے اور گناہوں سے روک رہی ہیں یا نہیں ؟ اگر اس کو روکا ہے تو پھر اس کی نماریں قبول ہوئیں ہیں ۔(۷۹)
نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اعمال اور نمازوں کے قبول ہونے کے بارے میں فکر کریں اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہماری ساری کوششیں نابود ہو جائیں گی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت زیادہ پیسہ خرچ کرکے ایک بہت بڑا خربوزہ خرید ے تو اس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خربوزہ سرخ اور میٹھا ہونا چاہیے اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کا سارا خرچ کیا ہوا پیسہ بے مقصد اور فضول ہوا ۔
نماز کے قبول ہونے میں حضور قلب اور خشوع کا کردار :
پوچھا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہماری نمازیں خدا کی درگاہ میں قبول ہو جائیں ؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے صحیح ہونے والی شرائط کی اس نماز میں رعایت کرنی چاہیے اور اسی طرح سے اس نماز کو کمال تک پہنچانے والی شرائط کو بھی لحاظ رکھیں جو درجہ ذیل ہیں ۔
۱ ۔ ولایت ۔ ۲۔ خشوع اور حضور قلب ۔ ۳۔ نماز کے بارے میں تفکر ۔ ۴۔ کسی مقدس جگہ پر نماز پڑھنا ۔ ۵۔ نماز کی سجدہ گاہ اگر تربت امام حسین علیہ السلام کی ہو تو بہت ہی اثر رکیتج ہے ۔ ۶۔ اول وقت میں پڑھنا ۔ ۷۔نماز میں خوف الہی سے گریہ کرنا ۔ ۸۔ آداب نماز کی رعایت کرنا ۔ ۹۔ ذکر خدا کی مٹھاس کو حاصل کرنا ۔ ۱۰۔ کسی بھی قسم کے گناہ کو انجام نہ دینے کا ارادہ رکھنا ۔۱۱ ۔ اپنے دل کو ہر قسم کی ریا کاری اور ناخالص چیز سے پاک کرنا ۔۱۲۔ دنیا سے تعلق ختم کرکے خدا سے لو لگانا ۔
ان تمام شرائط میں سے خشوع اور حضور قلب کا ہونا بہت ہی زیادہ اہمیت کا متحمل ہے اگرچہ دوسری شرائط حضور قلب اور خشوع کو تقویت دیتی ہیں لیکن اہم چیز کونسی ہے کہ جس سے ہم خشوع اور حضور قلب پیدا کریں ؟
فیض کاشانی یہاں پر ایک اچھی مثال دیتے ہیں اگر مرد یا عورت میں سے کوئی میٹھی چیز کھالیں اور اس کے منہ میں مٹھاس باقی رہ جائے تو وہ منہ دھوئے بغیر نماز پڑھنا شروع کریں تو اسی حالت میں ایک مکھی اس کے منہ کی اس مٹھاس کی طرف باربار آرہی ہے لیکن وہ اپنے ہاتھ سے یا سر ہلاتے ہوئے اس کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے ۔
عربی لغت میں مکھی کو ذباب کہا جاتا ہے جو دو کلمہ (ذب اور آب ) سے مل کر بنا ہے یعنی اس کو رد کیا لیکن وہ واپس آگئی ۔ اور یہ مکھی کی خاصیت ہے کہ اس کو جتنا بگانے کی کوش کرو اتنا ہی حریص ہو جاتی ہے اور اپنے ساتھ اور مکھیوں کو بھی لیکر آتی ہے تو پھر یہ بندہ اپنی پوری نماز میں مکھیاں مارنے میں مشغول رہا پھر فرماتے ہیں کہ یہ کونسی اور کیسی نماز ہوگئی کہ نماز کا پورا وقت مکھیاں مارتے ہوئے نکل جائے ۔ اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ مکھیاں اس دنیا میں آپ کے تعلقات ہیں اور آپ کے منہ کی وہ مٹھاس اس دنیا سے آپکی محبت اور طمع ہے ۔ آپ نے نماز سے پہلے کیوں اپنی منہ کو نہیں دھویا تاکہ وہ دنیا کے تعلقات آپ کا پیچھا کرنا ہی چھوڑ دیتے اور جس کے نتیجے میں آپ حضور قلب اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھ سکیں ۔
اسی بنا پر اگر نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو اس دنیا کی مادیات سے خالی کرے تو نماز میں خشوع وخضوع پیدا کرنے کے لئے ایک بہترین راستہ فرماہم ہوگا اگرچہ حضور قلب کی حفاظت کرنا اس صفت کی بقا کے لئے بہت ہی اہم اور مؤثر ہے ابتداء میں آپ کچھ نمازوں کو حضور قلب کے ساتھ پڑھےق اور آہستہ آہستہ اسی کی مراقبت کرتے جائے اور اسی کو جاری رکھیں تو انشااللہ کامیاب ہوں گے ۔
حضور قلب کے بغیر پڑھی جانے والی نماز جماعت سے امام زمانہ کی بے اعتنائی :
حضور قلب کے بارے میں آپ کی نظروں کو اس قصے کی طرف مبذول کرائیں گے جو امام زمانہ عجل اللہ سے منسوب ہے
آیت اللہ شیخ جعفر نجفی جوکہ بہت بڑے عالم دین تھے اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی معروف و مشہور تھے جیسا کہ سید مرتضی نجفی کا کہنا ہے کہ میں کئی سالوں سے شیخ جعفر کے ساتھ رہتا ہوں اور ہر وقت چاہے سفر ہو غیر سفر ہو میں اس کے ساتھ زندگی کزار رہا ہوں لیکن دین کے معاملے میں کبھی بھی اس کو کسی لغزش کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور یہ عالم شیخ جعفرنجفی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ہم کوفہ کی مسجد میں نماز جماعت میں تھے۔ حوزہ نجف کا ایک بہت بڑا عالم جوکہ لوگوں کے درمیان بہت احترام سے مشہور تھے وہا ں پر موجود تھے جب نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز پڑھانے کے لئے محراب میں گیا اور نماز جماعت پڑھانے کی تیاری کرنے لگا ۔ مؤذن آذان دے رہے تھے ۔بعض لوگ نماز کی وضو کرنے میں مشغول تھے اور بعض لوگ وضو کرکے نماز کے لائن میں کھڑے تھے تاکہ نماز شروع ہوجائے مسجد کوفہ کے صحن میں ہانی بن عروہ کے مرقد کے کنارے میں ایک چھوٹا سا نہر تھا جس میں تھوڑا سا پانی جاری تھا ۔ اسی نہر کی ایک جگہ پر تھوڑا سا گڑا تھا جس میں پانی جمع ہوا تھا جو صرف ایک بندے کے وضو کرنے کی جگہ تھی۔ جب میں وضو کرنے وہاں پر گیا تو دیکھا کہ ایک نورانی شخص وہاں پر بہت ہی اطمئنان کے ساتھ وضو کررہیں ہے میں جماعت میں حاضرہونے کے خاطر جلدی میں تھا تاکہ وہ جلدی وضو کرکے ہٹ جائیں اور مجھے وضو کرنے کا موقع ملے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے ہلتے ہی نہیں ! گویا وہ نماز جماعت میں حاضر ہونے کا قصد نہیں رکھتے ہیں ؟ بالاآخرہ میں نے اس کو کہا کیا آپ نماز جماعت میں شرکت نہیں کرنا چاہتے ؟ تو اس نے فرمایا نہیں ! تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں شرکت نہیں کرتے ؟ تو انہوں نے کہا «لانه الشيخ الدخينى؛ اس لئے کہ وہ شیخ جو امام جماعت بنا ہے وہ شیخ ارذنی ہے (یعنی ارزن کی کاشت کرتا ہے ۔ ارزن ایک چھوٹی قسم کا اناج ہے جس کے دانے ساگو دانے سے مشابہ ہے جو اکثر پالتو پرندوں کو کھلایا جاتا ہے ) میں نے تعجب کیا اور ان کی باتوں کو نہیں سمجھا اس کا مقصد کیا ہے ؟ جب وہ وضو سے فارغ ہو کر چلے گئے پھر اس کے بعد میں نے اس کو نہیں دیکھا میں جلدی سے وضو کرکے نماز جماعت میں شرکت کی اور نماز کے ختم ہونے کے بعد جب سارے لوگ چلے گئے تو میں امام جماعت کے پاس جاکر وہ سارا قصہ بیان کیا تو میری وہ باتیں سن کر اس کا رنگ تغیر ہوا اور غمگین ہونے لگا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ نے امام زمانہ کو دیکھا ہے لیکن اس کو نہیں پہچانا ہے ؟چونکہ اس نے ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر دی ہے کہ جو صرف خدا کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ جان لو کہ میں نے اس سال کوفہ کے اطراف کسی زمین میں ارذن کے دانے کاشت کئے ہیں لیکن وہاں پر لوگوں کی رفت وآمد کی وجہ سے وہ کھیت خطرے میں ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ زراعت اور کاشت نابود ہوجائے جب میں ابھی نماز میں مشغول ہوا تو اسی ارذن کی کاشت کے بارے میں یاد آیا کہ اس کا کیا بنے گا ؟
میں ظاہرا نماز پڑھ رہا تھا اور باطن میں میری تمام سوچ اور فکر اس مزرعہ کی طرف تھی اسی وجہ سے امام نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں اس بندے کے پیچھے جو حضور قلب نہیں رکھتا نماز نہیں پڑھتا ہوں ۔(۸۰)
چوتھی اور پانچویں حکمت :
امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر :
حضرت لقمان کی چوتھی اور پانچویں حکمت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہے جیسا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں (( وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَر ) . اے بیٹے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرو ۔(۸۱)
یہ حکمت بہت ہی اہم اور ضروری ہے اس کی وضاحت کرنے کے لئے درجہ ذیل مطالب کو بیان کریں گے ۔
معروف اور منکر کا معنی اور ان کے اقسام و مراحل:
معروف ہر نیک کام کو کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے انجام دینے والے کو ہمیشہ اسی صفت کے ساتھ ہی پہچان لیں ۔ اور بعض نے معروف کا معنی پہچانا ہوا لیا ہے چونکہ انسان کی پاک فطرت اسی سے آشنا ہے اور اس کا مخالف منکر ہے جو نہیں پہچاننے کے معنی میں ہے معروف اور نیکی کو پہچاننے کا بہترین طریقہ دین مقدس اسلام کی طرف رجوع کرناہے جو عقل خارجی شمار ہوتا ہے اور انسان کے اندر عقل اس کا باطنی شرع شمار ہوتا ہے ۔
بنابر این ہر وہ چیز کہ جس کا شارع مقدس اسلام نے حکم دیا ہے اور مسلمانوں کو اس حکم کے انجام دینے کی ترغیب دی ہے وہی معروف ہے۔ اس حساب سے ہم معروف کو پہچاننے کے لئے دین اسلام کے دستور واجب اور مستحب ہونے کی رجوع کریں گے اور اس نیکی کو دین کی نظر سے حاصل کریں گے ۔
قرآن مجید اور روایات میں اس کے لئے ہزاروں مصداق ذکر ہو ئے ہیں جیسا ایمان ۔تلاوت قرآن۔تفکر ۔ توکل ۔ اور خدا پر اعتماد۔ صبر و تحمل ۔ پرہیز گاری ۔ خدا اور اس کے رسول کی پیروی ۔ نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا ۔ انفاق اور عفو و درگزر ۔ احسان و نیکی ۔ توبہ ۔ جہاد ۔ شہادت ۔ عدالت ۔ شکر خدا ۔ دعا ۔ استقامت ۔ برد باری ۔ خوش اخلاقی ۔ قرآن مجید کی تعلیم ۔ حق بات کرنا اور مشکلات کو تحمل کرنا ۔ نماز ۔ روزہ ۔ حج ۔ صدقہ ۔ سچائی ۔ امانت داری ۔ وعدہ کی وفا کرنا ۔عفت ۔ شجاعت ۔ سخاوت اور عمل صالح ۔ دین کی مدد کرنا ۔ دعا و مناجات اور خدا کی رضا پر خوشنود ہونا اور حق کو آشکار کرنا اور قرآن مجید میں تدبر و تفکر کرنا اور قیامت کو یاد کرنا وغیرہ ۔۔۔
اور منکر کااصل معنی برا کام ہے جو وہی حرام اور مکروہ ہے جو فطرت کے اعتبار سے ناشناختہ اور عجیب و غریب ہے ۔
بنا بر این نہی عن المنکر دو قسم کا ہیں
امر بالمعروف واجب : جو واجبات کے مقابل میں ہے ۔
اور امر بالمعروف مستحب : جو مستحبات کے مقابل میں ہے ۔
اس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عقلی اور شرعی اعتبار سے جو چیز واجب ہے اس کی طرف امر کرناہے اور جو چیز عقل کے اعتبار سے بری ہے اور شرع مقدس میں حرام ہے اس سے نہی کرنا واجب ہے اور جو چیز مستحب ہے اس کے بارے میں امر کرنا مستحب ہے اور جو چیز مکروہ ہے اس کے بارے میں نہی کرنا مستحب ہے ۔(۸۲)
منکر کے مصادیق بہت ہی زیادہ ہیں جیسا کہ کفر ۔قتل نفس ۔ جہالت اور نادانی ۔ نااہل لوگوں سے دوستی کرنا ۔ ارادہ کا ضعیف ہونا گناہوں کو تکرار کرنا ۔ ظلم وستم ۔ اور کافروں کی اطاعت کرنا ۔ مؤمنین کے ساتھ لڑائی جھکڑا کرنا ۔ ظلم پر راضی ہونا اور حق بات کو چھپانا ۔ جھوٹ ۔ خیانت ۔ غیبت ۔ تہمت ۔ باطل راستے پر انقاق کرنا ۔ فتنہ ۔ بدعت ۔ حسد ۔ تکبر ۔ لالچ اور طمع ۔ قطع رحم اور والدین کے ساتھ بے احترامی کرنا ۔ قرآن میں تدبر نہ کرنا اور پیغمبر اسلام کے ساتھ مخالفت کرنا وغیرہ ۔۔۔۔
شرعی دلائل قرآن سنت اجماع اور عقل کے اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کے چہار شرائط ہیں۔
۱۔ معروف اور منکر کو جاننا کہ کیا یہ شرع کی نظر میں نیک اور پسندیدہ ہے یا نہیں ؟
۲۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تاثرم کا احتمال ہو ۔
۳۔ طرف مقابل معروف کو ترک کرنے اور گناہ کو انجام دینے میں مصر ہو ۔
۴۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے کوئی جانی نقصان اور ضرر نہ ہو ، چاہیے امر کرنے والا ہو یا کوئی مؤمن ہو ان کو نقصان اور کوئی ضرر نہ پہنچنے لیکن ایسے موارد میں کہ جہاں اسلام کو کوئی خطرہ پیش آجائے تو وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہو جاتاہے اگر چہ ایسا کرنے میں جان کے لئے ہی خطرہ کیوں نہ ہو ! جیسا کہ امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے اور اپنی جان قربان کردی اور ان کے اہل بیت اسیر ہوگئے ۔
اور دوسرا اہم مسئلہ جو کہ فقہی کتابوں میں بیان ہوا ہے وہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراحل کے بارے میں ہے کہ جنکو جاننے کی بہت ہی ضرورت ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دل سے ہونا چاہیے پھر زبان پر اور پھر عمل کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ ان میں سے ہر کسی کے لئے مختلف درجے ہیں اور ہدف و مقصد جب پہلے درجے سے حاصل ہو جائے تو دوسر ے درجے کی باری ہی نہیں آتی ہے ۔ اسی لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے جیسے نرمی ۔ خشونت ۔ استدلال ۔ اور مجادلہ اور دوسروں کے ساتھ برخورد کیسا ہونا چاہیے ۔۔
لہذا انہی چیزوں کو جاننا چاہیے کہ اثر کرنے والی چیزیں کونسی ہیں اور اس کا طریقہ کیسا ہے اور انہی طریقوں کو پہچان کر پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے تاکہ اچھا نتیجہ حاصل ہو ۔
قرآن کی آیات اور روایات کی طرف ایک نگاہ :
اس بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسان اور معاشرے کی پاک سازی میں ایک خاص اہمیت کے متحمل ہیں قرآن مجید جو کہ انسان سازی کی ایک کامل کتاب ہے وہ اس چیز کو بہت ہی اہمیت دی ہے اور اپنی پیروی کرنے والوں کو ان دو فریضوں کی طرف دعوت دیتی ہے۔ قرآن مجیدکبھی اس امر کی طرف تشویق دلاتی ہے اور اس امر کے ترک کرنے کے برے عواقب کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کبھی شرائط کے موجود ہوتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازمی قرار دیتی ہے اور اس کو مؤمن کی خصوصیات میں سے شمار کرتی ہے ۔
قرآن مجید میں تقریبا دس سے زیادہ ایسے مقامات ہیں کہ جن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ذکر ہوا ہے(۸۳)
اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ اہم فریضے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نماز کی طرح ہر انسان پر واجب ہیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو ان میں کوئی فرق نہیں بلکہ سب پر واجب ہیں ۔(۸۴)
اور روایات اسلامی میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاص اہمیت بیان ہوئی ہے اور اس کو خداوند عالم کی طرف سے اہم ترین حکم اور دستور فرض کیا گیا ہے ان روایتوں کو ہم پانچ گروہ میں تقسیم کرسکتے ہیں ۔
وہ روایات جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کو بیان کرتی ہیں ۔
وہ روایات جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے والے کو خبر دار کرتی ہیں ۔
وہ روایات جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں ۔
وہ روایات جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مراحل کو بیان کرتی ہیں ۔
وہ روایات جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آثار کو بیان کرتی ہیں ۔
یہاں پر ان پانچ گروہوں میں سے ہر کسی کے لئے کئی روایات ذکر ہوئی ہیں لیکن ہم ان میں سے ایک روایت کو ذکر کریں گے ۔
امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے :« وَيْلٌ لِقَوْمٍ لَا يَدِينُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ;
افسوس ہے ایسی قوم پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی دین کا روش اور شعار قرار نہیں دیتے اور اس پر اعتقاد رکھنے میں خدا کو قبول نہیں کرتے ہیں( ۸۵)
امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے «فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْمَاضِيَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَّا لِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكر; خداوند متعال نے گزشتہ لوگوں کو اپنی رحمت سے دور نہیں کیا مگر یہ کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کیا۔( ۸۶) کسی اور مقام پر امام نے فرمایا : «وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَخُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ ..; امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خدا وند متعال کی صفات میں سے ہیں یہ نہ ہی انسان کی موت کو نزدیک کرتیں ہیں اور نہ ہی ان سے رزق میں کمی آتی ہے ۔( ۸۷)
کسی اور عبارت میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کا ایک گروہ اپنے ہاتھ ( عمل ) زبان اور دل سے منکرات کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اندر تمام خصلتوں کو جمع کیا ہوا ہے ۔
اور ایک گروہ ایسا ہیں جو صرف اپنی زبان اور دل سے نہی عن المنکر کرتے ہیں انہوں نے دو نیک خصلتوں کو اپنایا ہے اور ایک کو چھوڑ دیا ہے ۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو صرف اپنے دل سے مقابلہ کرتے ہیں اور عمل اور زبان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور صرف ایک ہی خصلت کو اپنایا ہے ۔ اور ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جنہوں نے ان تین خصلتوں میں سے کسی سے بھی تمسک نہیں کیا ہے اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے «فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء ، یہ لوگ حقیقت میں زندہ لوگوں کے درمیان مردہ شمار ہوتے ہیں پھر فرمایا :
«وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّي ; خدا کی راہ میں میں انجام پانے والی تمام نیکیاں اور اچھائیاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایک قطرہ کی مانند ہیں جو سمندر کے مقابل میں ہوتا ہے ۔(۸۸)
ان دو فریضہ الہی کے آثارکے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں :بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ ; امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے تمام فرائض اور واجبات انجام پاتے ہیں اور راستوں میں امن و امان بر قرار رہتا ہے اور لوگوں کی تجارت حلال ہو جاتی ہے اور ہر قسم کا ظلم و ستم ختم ہو جاتا ہے زمین آباد ہو جاتی ہے دشمنوں سے انتقام لیا جاتا ہے اور تمام امور اسی سے انجام پاتے ہیں ۔(۸۹)
نظارت عمومی اور آزادی کا مسئلہ :
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم معاشرے کی اصلاح اور عدالت کو برقرار رکھنے کے لئے ایک عظیم پروگرام شمار ہوتا ہے ۔
یہ حکم کسی خاص گروہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اپنی توان اور قدرت کے مطابق ہر کسی پر واجب اور ضروری ہیں ۔
بنا بر این یہ دو فریضے عمومی ہیں جو معاشرے کو غرق ہونے سے بچاتے ہیں اور معاشرے کی اس کشتی کو سلامتی کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہچاتے ہے اور عقل کے اعتبار سے ایسا کرنا ایک نیک اور اچھا کام ہے جس سے کہ ڈ اکٹر مریضوں پر نظارت عمومی رکھتا ہے اور انسان کے مریض نہ ہونے کے لئے مختلف چیزوں کو تجویز کرتا ہے اسی طرح سے معاشرے کو بیماری اور خطرے سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ دونوں فریضے بہت ہی اہم ہیں ۔
بعض آزادی کے دعویدار اس لفظ آزادی کو غلط معنی میں لیتے ہوئے آزادی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے درمیان تضاد ہونے کے قائل ہوئیں ہیں کیا واقعا ایسا ہی ہے ؟
تمام تمدنوں اور فرہنگوں میں آزادی کے لئے کوئی خاص حد اور حدود معین ہیں لذا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آزادی مطلق کو اجرا کرے آزادی اسوقت تک محترم اور اچھی ہے کہ معاشرہ کے انحراف اور سقوط یا حرج و مرج کا باعث نہ بنیں ۔
عقلی طور پر آزادی یعنی انسان کے تکامل اور رشدمیں جو رکاوٹیں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنا ہے اور اس کے لئے بہترین طریقہ وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نظارت عمومی ہیں جو کمال تک پہنچنے کی راہ ہموار کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صحیح آزادی کو تقویت دیتے ہیں ۔
پیغمبر اسلام کے زمانے کا ایک ایسا ہی شبھہ بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس کی ایک مثال دیتے ہوئے جواب دیا ہے کہ ہمارے معاشرے کی مثال اس کشتی کے مانند ہے کہ جس میں سوار افراد اسوقت تک آزاد ہیں جب تک دوسروں کے ہلاک ہونے کا باعث نہ بنیں اور جب کوئی مسافر اس آزادی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کشتی میں سراخ کرنا چاہے تو دوسرے مسافر اس کو اس کام سے نہی کریں گے اور روک دیں گے تاکہ دوسر ے مسافر غرق نہ ہو جائیں تو ایسا کرنا عقل اور فطرت کے اعتبار سے بہت ہی ضروری اور لازمی ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف عمل کرے تو یہ دیوانگی اور خود کشی ہے کیا آزادی انسان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ خود کشی کرے اور دیوانگی اختیار کرے ؟
اور دوسری مثال یہ ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے اعضاء شمار ہوتے ہیں اگر کسی شخص کے جسم پر کوئی بدبودار پھوڑا نکلے اور ڈاکٹڑ اس پھوڑے کو آپریشن کرکے نکال دے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آزادی کے خلاف کام کیا ہے ؟
جبکہ اس نے دوسرے افراد کو اس پھوڑے کے خطرے سے محفوظ رکھا ہے ۔(۹۰)
قرآن کے دو سؤالوں کے جواب :
قرآن مجید میں کبھی ایسی آیات کی طرف بھی نظر پڑتی ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں ۔
۱۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ آیت ۱۰۵ میں ہم پڑھتے ہیں کہ «( يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُم ) ; اے ایمان والو !اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا،
اگرچہ یہ آیت ظاہری طور پر اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ ہر کوئی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو اس صورت میں گمراہوں کی طرف سے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اسی لئے دوسروں کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے اور بعد والی آیات کے طرف توجہ دیتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مورد کافر اور منافقین سے مربوط ہے جبکہ یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علم نہ ہونے کی بناپر اثر نہ کرنے والی صورت کو بیان کرتی ہے ۔ اس صورت میں یہ دونوں فریضے واجب اور ضروری نہیں ہیں ۔ اور دوسرا یہ کہ آیت یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے بعد اگر کافر اور منافقین قبول نہ کریں تو آپ اپنے کو پاک رکھو تو ان کی گمراہی آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گی ۔
۲۔ اور دوسری آیت یہ کہ بعض شبہہ کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرمارہا ہے( وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ..; اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔(۹۱)
اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کرے اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے لیکن بعض مراحل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں خطرہ اور ضرر پائے جاتے ہیں لذا ایسی چیزوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنے چاہییں ؟
اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کی طرف توجہ دینے سے روشن ہوتا ہے کہ یہ آیت راہ خدا میں انقاق کرنے سے مربوط ہے اور اس سے پہلی والی آیات دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں بیان ہوئیں ہیں اور اس آیت سے مراد اس جہاد کے مقدمات کو فراہم کرنے کےلئے انفاق کرنے کا حکم ہوا ہے اور انفاق نہ کرنے یا انفاق میں اسراف کرنے کرکے خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا ہے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد ہر چیز میں افراط اور تفریط کرنے سے روکنا ہے ۔
اما ایسی آیات اور روایات جو یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں عن المنکر کرنے کے راستے میں خود کو زحمت اور مشقت میں ڈالیں اور تمام سختیوں کو تحمل کرکے اس فریضہ الہی کو انجام دے دیں اور اسے ترک نہ کریں اور ایسا کرنے میں کوئی ہلاکت نہیں بلکہ اس میں انعام اور پاداش الہی سعادت اور شہادت ہیں کیا شہادت ہلاکت ہے ؟
دوسری عبارت میں مہم اور اہم کا قانون یہ ہیں کہ مہم کو اہم کی خاطر قربان کردے لہذا ایک بڑی منفعت کو حاصل کرنے کی خاطر ایک جزئی ضرر کو تحمل کرنا کبھی بھی ہلاکت شمار نہیں ہوتا ہے ۔ اس بحث کو مکمل کرنے کے لئے اس واقعہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے ۔
روایت میں آیا ہے کہ اسلم بن ابی عمران کہہ رہا ہے کہ ہم قسطنطنیہ( جو آج کا استانبول ترکیہ )میں موجود تھے عقبہ بن عامر جو کہ مصر کے لوگوں کے ساتھ موجود تھے اور فضالہ بن عبید جو شام کے لوگوں کے ہمراہ موجود تھے روم سے ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے آئے ہم دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے جلدی سے اپنی لائن میں کھڑے ہوئے اسی دوران مسلمانوں میں سے کوئی اچانک دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہوا تو بعض مسلمانوں نے چیخنا شروع کیا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے جبکہ قرآن مجید نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے تو پیغمبر اسلام کا مشہور اور معروف صحابی ابو ایوب انصاری کھڑ ے ہو کر کہنے لگے اے لوگوں کیا آپ نے اس آیت( وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ...)کی اپنی رائی سے تاویل اور تفسیر کی ہے ۔ جبکہ یہ آیت ہم انصاری گروہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب خدا وند عالم نے اپنے دین کو فتح اور کامیاب کیا تو دین کے حامی بہت ہی زیادہ ہونے لگے تو ہم میں سے بعض لوگ مخفیانہ طور پر ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے اموال کو ضایع کیا جبکہ خدا وند عالم نے اپنے دین اسلام کو کامیابی عطا کی جس کی وجہ سے دین اسلام کے چاہنے والے بہت زیادہ ہوگئے اگر ہم اپنے اموال کو اپنے پاس رکھ دیتے تو ابھی اسی سے استفادہ کرتے ۔۔۔ تو اسی وقت میں ہماری ان باتوں کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی « وَ أَنْفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ; اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کیا کرو،
اس بناپر ہلاکت سے مراد اموال کو اپنے پاس رکھ کر جنگ میں دشمن کے مقابل میں انفاق نہ کرنا ہے ۔(۹۲)
حضرت لقمان اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مسئلہ :
حضرت لقمان کی زندگی کی اہم ترین خصوصیات میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا تھا ۔ اس کو لقمان بہت ہی اہمیت دیتا تھا وہ اپنی حکیمانہ باتوں سے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دیتا تھا اور منحرف ہونے سے ہمیشہ انکو ہوشیار کرتا تھا اسی لئے ان کی وہ حکیمانہ باتیں قرآن مجید اور اولیاء خدا کے زبان پر ہر نسل میں منتقل ہوتی آئی ہیں اور لوگ ان کی حکیمانہ باتوں سے ہر زمانہ میں آگاہ ہیں ۔ حضرت لقمان بہت ہی زیادہ نصیحتیں کرتے تھے اور بہت ہی نرمی سے باتیں کیا کرتے تھے معنی کو سمجھانے کی خاطر مثالوں کو ذکر کیا کرتے تھے ۔
ہدایت کے مسئلے کو اپنے زوز مرہ کے کاموں میں شامل کیا ہوا تھا اور ہر عصر و زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس فریضہ الہی کو اہمیت دینے کی تاکید کیا کرتے تھے اسی لئے اپنے بیٹے کو اس امر کی سفارش کرتے ہیں ۔
چھٹی حکمت : صبر و استقامت :
اس چھٹی حکمت میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس طرح سے نصیحت کرتے ہیں ۔( وَ اصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ) )(۹۳) اے بیٹا! ۔۔جو مصیبت تجھے پیش آئے اس پر صبرکرو، یہ امور یقینا ہمت طلب ہیں۔
تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام پیغمبر وں اور ائمہ معصومین کے کلام میں صبرو استقامت کی بہت ہی تاکید ہوئی ہے اس طرح سے صبر و استقامت کو اکسیر اعظم یعنی تمام مشکلات کا حل قرار دیا ہے اور اس کے برعکس عمل کرنے کو سستی اور ضعف اور بدبختی کا باعث قرار دیا ہے ۔ بقول مولانا :
صد هزاران كیمیا حق آفرید
كیمیایی همچو صبر آدم ندید
یعنی خداوند متعال نے ہزار ہا کیمیا پیدا کئے ہیں لیکن صبر آدم کی طرح کوئی کیمیا نہیں ہے ۔
صبرو استقامت ان کلمات میں سے ہیں جو قرآن کریم میں مختلف تعبیروں کے ساتھ تقریبا دوسو مرتبہ ذکر ہوئے ہیں جو کہ اہم ترین مفاہیم میں سے ہیں اور انسان کے تقدیر بدلنے میں اساس اور بنیاد قرار پائے ہیں ۔ خدا وند متعال صابرین پر ہمیشہ دورد و سلام بھیجتا ہے اور انکو ہدایت پانے والوں میں سے قرار دیا ہے۔
اور خداوند متعال صابرین کی جزاء اور انعام کے بارے میں پیغمبر اسلام کو اس طرح سے فرمایا کہ ان کو خوش خبری دو پھر فرمایا :( أُوْلَئكَ عَلَيهْمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْمُهْتَدُون ) ;(۹۴) یہ وہ لوگ ہیں جن پران کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ۔
حضرت لقمان نے اپنی بیشتر نصیحتوں میں اس صبر و استقامت کو بیان کیا ہے اور وہ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ اس محکم اور مضبوط قدرت سے استفادہ کریں اور اسی کی روشنی میں کمالات تک پہنچنے کی کوشش کریں ۔
انہی نصیحتوں میں سے ایک جو ہماری مورد بحث آیت ہے کہ جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو زندگی کے تلخ ترین حوادث اور سخت ترین مشکلات میں صبرو استقامت کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کو ہوشیار رہنے کی سفارش کرتا ہے ۔
صبر استقامت کا مسئلہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے انسان اس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے ۔
ممکن ہے یہاں پر (من عزم الامور)کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہو کہ صبرو استقامت ایک محکم اور مضبوط ارادہ کا محتاج ہے کہ جس کے بغیر انسان کبھی بھی صبرو استقامت جیسے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے ۔ جیسا کہ لغت والوں نے صبر کا عزم اور ارادہ یا کسی کام کو انجام دینے کے لئے مصمم ارادہ کرنے کا معنی کیا ہے ۔(۹۵)
تجزیہ وتحلیل :
جس طرح سے تجربہ اور تاریخ سے ثابت ہوا ہے اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ مشکلات اور سختیاں بہت ہی زیادہ ہیں کبھی خاندانی اختلافات اور کبھی ہمسایوں کے درمیان اختلافات ہونے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں وجود میں آتی ہیں اور اسی طرح سے کبھي گلی سڑکوں میں اور کبھی ٹریفک حادثات اور ایک دوسرے کو بدزبانی کی وجہ اور کبھی بیماریوں اور کبھي سیاسی حالات اور فقر و تنگدستی کی وجہ سے اور کبھي شادی کے مسائل اور جنگوں کے مسائل کی وجہ سے بہت سارے اختلافات پیش آتے ہیں اور ہر جگہ پر یہی مشکلات اور مصائب پائی جاتی ہیں اور ہم ان مشکلات کو دیکھتے ہی ہیں ۔
اسی طرح سے کبھی کسی آسمانی آفت جیسے ( زلزلہ اور طوفان) وغیرہ جیسی مشکلات سے انسان دچار رہتا ہے کہ جس کا خلاصہ امام علی علیہ السلام کے اس کلام میں ملتا ہے کہ فرمایا : (الدُّنْيَا دَارٌ بِالْبَلَاءِ محفوفة ; دنیا ایک ایسا گھر ہے جو رنج اور بلاؤں میں لپٹا ہے ۔(۹۶)
ایسی شرائط میں انسان اپنی حفاظت اور آرامش کے لئے صبر اور استقامت جیسی خصلت سے مدد لے اور اس کی پناہ میں آکر انسان اپنے کو آرامش بخش دے لیکن اگر وہ بے صبری کا اظہار کرے تو اس کی مشکلات اور بلاؤں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور اس کی سالم زندگی بے سکونی اور ناراحتی میں تبدیل ہو جائے گی ۔
اور ظاہر ہے کہ انسان اس نفسانی حالت کے ساتھ ہو تو اس کے بہت برے آثار ظاہر ہونگے ۔ اسی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت لقمان کی یہ نصیحت بہت ہی قیمتی اور با ارزش ہے انسا ن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان جیسی نصیحتوں کو اپنے لئے نمونہ عمل قرار دے دیں وگرنہ انسان کے پاس جب صبر حوصلہ نہ ہو تو ان کی زندگی کو ہمیشہ لڑائی جھگڑے کا سامنا کرنا پڑے گا ۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ اس قانون کے کچھ استثناءات بھی ہیں جیسا کہ ایسے موارد میں کہ جہاں انسان اپنے صبراور سکوت کو توڑکر اپنے حق کا دفاع کرسکتا ہے۔
صبر کے اقسام :
صبر اور استقامت کے مختلف انواع اور اقسام ہیں :
جیسا کہ گناہ کے مقابل میں صبر اختیار کرنا ۔ اطاعت کے راستے میں صبر کرنا ۔ اورمصائب و مصیبتوں کے وقت صبر کرنا ۔ لیکن حضرت لقمان نے ا پنی اس نصیحت میں مصیبتوں کے مقابل میں صبر کرنے کو بیان کیا ہے جو کہ صبر اور استقامت کے اہم ترین اقسام میں سے شمار ہوتا ہے ۔ اور ایسا صبر توان اور قوت قلبی کا منشا ہے اور یہی آثار انسان کو دوسرے موارد میں صبر کرنے میں مدد دیتے ہیں اور دوسری عظیم برکات کا سرچشمہ قرار پاتے ہیں۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت لقمان کی مراد صبر کی تمام اقسام ہوں چونکہ اطاعت کے مقابل میں ایسے عوامل جو سستی اور گناہ کا سبب بنتے ہیں وہ بھی مصیبت ہی شمار ہوتے ہیں ۔
بہر حال اس دنیا کی مشکلات اور مصائب بہت ہی زیادہ طاقت فرسا ہیں اگر ان کے مقابل میں صبر و استقامت نہ ہو تو انسان کا وجود بے ہودہ اور بے مقصد ہوگا ۔ اور ہر کا م کسی چیز کے سامنے گٹھنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اور اپنی روح و بدن کو ہلاکت میں ڈالے گا ۔
انہی سختیوں میں سے ایک جنگ کا میدان ہے کہ جس میں مرنے یا زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ۔ جب انسان ان سختیوں کے مقابل میں صبر نہ کرےتو گویا اس نے فرار ہونے کو ترجیح دے دی لیکن اگر انسان صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کرے تو اس کی توان اور اس کی قدرت دوگنا ہو جائیں گے اور ایک دشمن کے بجائے دس دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ جیسا کہ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتاہے ۔ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن; اگر تم میں بیس صابر (جنگجو) ہوں تو وہ دو سو (کافروں) پر غالب آجائیں گے ۔
اسی طرح سے قرآن مجید میں آیا ہے کہ شموئیل پیغمبر کا نائب طالوت جب ایک چھوٹا سا گروہ لیکر جن میں بہت کم افراد شامل تھے لیکن صبر و استقامت کے ساتھ جب جالوت کے اس بڑے عظیم لشکر کے مقابلے میں گیا جبکہ وہ اس دعا کو پڑھتے تھے ۔
( « قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرين ) ; اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پرنکلے توکہنے لگے: پروردگارا ! ہمیں صبر سے لبریز فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہمیں فتح یاب کر ۔(۹۷)
ان لوگوں نے اس جذبہ کے ساتھ جالوت کے اس عظیم لشکر کے ساتھ جنگ کی اور کامیاب ہوئے چونکہ وہ خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے تھے جس کا نتیجہ انکی استقامت تھی اور مضبوط اعتقاد کے ساتھ کہہ رہے تھے ۔
«( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرينَ ) ; بسا اوقات ایک قلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔(۹۸)
حضرت ایوب صبر کا قرآنی نمونہ :
قرآن مجید ان تلخ اور دشوار حوادث کے مقابل میں صبرو استقامت جیسی خصوصیت کی تعلیم دینے میں کبھی گزشتہ انبیاء کی تاریخ کو بیان کرتا ہے اور ان کی زندگی کے ایک حصے کو بطور نمونہ ذکر کرتا ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو ان کے ساتھ مقایسہ کریں اور ان سے صبر و استقامت کا درس حاصل کریں ۔ انہی میں سے ایک نمونہ حضرت ایوب ہے جو زراعت اور چوپانی کرنے کی وجہ سے بہت ہی عظیم ثروت کے مالک تھے ۔
حضرت ایوب کی زندگی تمام نعمات الہی سے سرشار تھی وہ ہمیشہ خدا کا شکر انجام دیتے تھے اس حد تک وہ شکر خدا بجا لاتے تھے کہ ابلیس اس سے حسد کرنے لگا اور خدا کی درگاہ میں عرض کرنے لگا ایوب کا اتنا شکر بجالانا آپ کی نعمات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے لہذا آپ مجھے اس پر مسلط کردیں تاکہ معلوم ہوجائے کہ وہ کیسے آپ کا شکر بجا لاتا ہے ؟ تو خداوند عالم نے ان کو اجازت دی تاکہ بعد میں آنے والوں کے لئے یہ حقیقت ثابت ہو جائے لہذا ابلیس نے حضرت ایوب کے تمام مویشیوں کو اور سارے باغوں کو اور یہاں تک کہ انکے گھر اور بیٹوں کو بھی نابود کردیا لیکن حضرت ایوب نے ان سب مصیبتوں اور مشکلات میں صبر و استقامت کے ساتھ انکا مقابلہ کیا اور ہمیشہ شکر خدا بجا لاتا رہا بلکہ ان سب مشکلات اور سختیوں کے بعد اس کے شکر بجا لانے میں اور اضافہ ہو گیا ۔(۹۹)
حضرت ایوب اسی حالت میں بھی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر خدا وندمتعال سے اس طرح سے راز و نیاز کرتا ہے ۔(اے دن اور رات کو خلق کرنے والے خدا میں جس حالت میں اس دنیا میں آیا ہوں اسی حالت میں تیرے پاس آؤنگا خدایا آپ نے مجھے نعمت دی ہے اسی کو مجھ سے دوبارہ لے لیا ہے میں آپ کی اس رضا پر راضی ہوں )
اتنی ساری مشکلات کے ساتھ اس دفعہ حضرت ایوب اپنے پاؤں کے بہت ہی سخت درد میں مبتلا ہوئے اس کا پاؤں زخمی ہوا جس کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کرسکتے تھے ۔ حضرت ایوب تقریبا سات یا سترہ سال تک اسی حالت میں رہے لیکن پہاڑ کی طرح محکم اور مضبوط رہے اور ان سب مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرے اور ہمیشہ خدا کا شکر بجا لاتے رہے ۔
حضرت ایوب نے نہ ہی اپنے دل میں اور نہ ہی زبان سے اور نہ ہی عملی طور پر ایک ذرہ بھي خدا کی نارضایتی کا اظہار نہیں کیا اور یہی اس کی صبر و استقامت کا بہترین نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مقام شکر اور رضا حاصل ہوا ۔ خدا کی درگاہ میں وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا :
تو را خواهم نخواهم نعمتت گر امتحان خواهی
در رحمت به رویم بند و درهای بلا بگشا
یعنی میں تجھے چاہتا ہوں تیری نعمتوں کو نہیں اگر امتحان لینا چاہتاہے تو رحمت کے دروازے بند کرکے بلاؤں کے دروازے کھول دے !
حضرت ایوب کی کئی بیویاں تھیں لیکن ان کی اس بیماری کو تحمل نہیں کرسکیں وہ ایک ایک ہوتی ہوئیں حضرت ایوب کو تنہا چھوڑ کر چلی گئیں ۔ حضرت ایوب کی صرف ایک ہی بیوی جو رحیمہ نام کی تھی اس کے ساتھ رہ گئی لیکن کچھ ہی مدت کے بعد وہ بھی بے صبری کا اظہار کرتی ہوئی ایوب کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی ۔
حضرت ایوب اتنی ساری مشکلات اور سختیوں کے ساتھ اس صحراء میں تنہا رہ گئے لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ ان ساری مشکلات کا مقابلہ کرتے رہے اور خدا کا شکر بجا لاتے رہے ۔
اب حضرت ایوب کے پاس کھانے کے لئے بھي کچھ نہ رہا بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور خدا کو مخاطب قرار دیتے ہوئے عرض کرنے لگے ۔ (رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ; جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا: مجھے (بیماری سے) تکلیف ہو رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔
ایسے وقت میں حضرت ایوب کی دعا قبول ہوگئی اور ان کی ساری مشکلات اور سختیاں ختم ہوئیں اور خدا وند متعال نے ان کو تمام بلاؤں کے بدلے میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور ان کے صبر اور استقامت اور شکر کے بدلے میں ان کے مال و دولت میں اور بھي اضافہ ہوا جیسا کہ فرمایا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف ان سے دور کر دی اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے اور اپنی رحمت سے ان کے ساتھ اتنے مزید بھی جو عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ( ۱۰۰)
قرآن مجید کی یہ تعبیر «...وَ ذِكْرَى لِلْعَالَمِين » حضرت ایوب کے صبر کرنے کا جو واقعہ ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد یہ اعلان کررہا ہے کہ حضرت ایوب کی شخصیت تمام عالم اسلام کے لئے نمونہ عمل بن گئی ہے بالکل یہی بات ہے کہ خداوند عالم نے حضرت ایوب کو تمام دنیا والوں کے لئے مایہ افتخار بنایا ہے کہ فرمایا : «( إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب ) ; ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ (اپنے رب کی طرف) رجوع کرنے والے تھے۔(۱۰۱)
پیغمبر اکرم ص اور ائمہ معصومین ع کا صبر :
۱ ۔ رسالت کے ابلاغ کے راستے میں پیغمبر اسلام کی طرح کسی اور پیغمبر کو اذیت اور تکلیف نہیں ہوئی ہے جیسا کہ خود پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ۔ «مَا أُوذِيَ نَبِيٌ مِثْلَ مَا أُوذِيت ; کسی بھی پیغمبر کو میری طرح اذیت و آزا ر نہیں پہنچا ہے ۔(۱۰۲)
اس کے باوجود پیغمبر اکرم کی تمام زندگی میں کوئی ایسا مورد نہیں ملتا ہے کہ پیغمبر نے عاجزی یا ضعف و سستی کا اظہار کیا ہوا ہو بلکہ انہوں نے ایک پہاڑ کی مانند صبر و استقامت کے ساتھ اپنے راستے کو جاری رکھا ۔
جیسا کہ جنگ احد میں پیغمبر اسلام کو بہت ہی سخت ترین مصیبت ( حضرت حمزہ کی شہادت ) کا سامنا کرنا پڑا اور حضرت علی جیسی محبوب ترین شخصیت زخمی ہوئی اور اآپ کے مبارک دانتوں پر چوڑ لگی لیکن ان سب مشکلات کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ پیغمبر کے اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دشمن کے لئے بدعا اور نفرین کریں لیکن انہوں نے فرمایا : (اللَّهُمَ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .خدا یا میری قوم کی ہدایت فرما کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں ۔(۱۰۳)
پیغمبر اسلام کے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ جو کہ حضرت خدیجہ سے تھے جب مدینہ میں وفات پائے تو اس کے بعد پیغمبر اسلام کو کوئی اور بیٹا نہیں ہوا یہاں تک کہ ہجرت کی آٹھویں سال پیغمبر اسلام کی ایک بیوی ماریہ قبطیہ سے ایک بچہ ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا اور وہ بھی ایک سال دس مہینہ اور آٹھ دن کے بعد وفات پاگئے تو پیغمبر اسلام نے انکو بقیع میں دفن کیا ۔(۱۰۴)
پیغمبر اسلام کے لئے یہ بہت بڑی مصیبت تھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا : میری آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے لیکن صبر اور شکر کے خلاف کوئی ایسا کلام نہیں کرونگاجو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے ۔
امام علی علیہ السلام کو کہنے لگے آپ قبر میں داخل ہو جائیں اور ابراہیم کو دفن کریں امام علی علیہ السلام پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے قبر میں داخل ہوئے تو بعض اصحاب نے کہا کہ پیغمبر اسلام خود قبر میں داخل نہ ہونے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کے قبر میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے تو پیغمبر اسلام نے انکو کہا یہ کوئی حرام کام نہیں ہے لیکن مجھے اس بات سے خوف ہے کہ کسی شخص کا بیٹا مرجائے اور اسکا باپ اس کو دفن کرے اور اس وقت اس کے بیٹے کے چہرے پر نظر پڑ جائے اور باپ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر بے صبری کا اظہار کرے اور بے تابی کرنے لگے تو اس کے نتیجہ میں جو خداکی درگاہ میں جو مقام اور اجر و ثواب ہے وہ نابود ہوجائے ۔(۱۰۵)
۲۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ان کے خاندان پر بہت بڑی مصیبتں آئیں امام علی علیہ السلام بہت ہی سخت ترین مشکلات میں گرفتار ہوئے ایک طرف سے پیغمبر اسلام کی وفات کا غم اور ایک طرف سے حضرت زہرا کی شہادت کا غم اور انکی خلافت کو غصب کرنا لیکن ان ساری مشکلات میں امام علیہ السلام نے صبر وتحمل کا مظاہر ہ کیا اور فرمایا : «فَرَأَيْتُ أَنَ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذًى، وَ فِي الْحَلْقِ شَجًى، » میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے تو میں نے اس عالم میں صبر کرلیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اورگلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔(۱۰۶)
شاید پیغمبر اسلام کے بعد حضرت علی کی طرح کوئی بھی رنج اور بلاء میں مبتلا نہیں ہوا ہے لیکن کبھی بھی عاجزی اور ضعف کا اظہار نہیں کیا ۔ امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق امام علی علیہ السلام سخت ترین مشکلات اور مصائب میں گرفتار ہوتے تو نماز پڑھتے تھے اور اسی نماز کے ذریعے سے اپنی روح کو آرامش بخشتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے : «( وَ اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ ) ;صبر اور نماز سے مدد لینا ۔(۱۰۷)
۳۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام سخت ترین شرائط میں قرار پائے تو اپنے اصحاب کو مخاطب قرار دے کر فرمایا : (صَبْراً يَا بَنِي عُمُومَتِي صَبْراً يَا أَهْلَ بَيْتِي ،اے میرے چچا زاد بھائیوں کے بیٹے اور اے میرے اہل بیت صبر کرو آج کے بعد پھر کبھی بھی ناراحتی نہیں دیکھو گے ۔(۱۰۸)
اور خود امام حسین علیہ السلام اتنے صابر تھے کہ کربلا کی تاریخ بیان کرنے والے حمید بن مسلم کہہ رہے ہیں : (فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَكْثُوراً قَطُّ قَدْ قُتِلَ وُلْدُهُ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ أَصْحَابُهُ أَرْبَطَ جَأْشاً وَ لَا أَمْضَى جَنَاناً مِنْهُ ; خدا کی قسم میں نے ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا جو اتنی مشکلات میں گرفتا رہو اور جس کے سارے خاندان اور انکے بیٹے اور اصحاب شہید ہوئے ہوں اس کے باوجود وہ صابر اور استوار ہو ۔
امام علیہ السلام اپنی شہادت کے وقت خدا سے مناجات کر رہے تھے «صبرا علی قضائك یا رب; خدایا آپ کی چاہت اور رضا پر میں صبر اور استقامت اختیار کرتا ہوں ۔(۱۰۹)
۴۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد مفضل بن عمر کا اسماعیل نامی ایک بیٹا تھا جب وہ وفات پا گئے تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے موسی بن جعفر کو مفضل کے گھر تسلیت کے لئے بھیجا اور انکو کہا کہ مفضل کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ جب میرے بیٹے اسماعیل کے مرنے کی خبر مجھے دی تو میں نے صبر کیا اور آپ بھی ہماری طرح سے صبر کرنا چونکہ جو کام خدا کے ارادے سے ہوتا ہے ہم اسی کو پسند کرتے ہیں اور خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں ۔
جب امام صادق علیہ السلام بیماری کی حالت میں بسترے میں پڑے ہوئے تھے تو امام کا ایک صحابی ان کی عیادت کو آیا اور امام کی وہ حالت دیکھ کر رونے لگا تو امام نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہے ؟ تو وہ کہنے لگے یا امام میں آپ کو اس کمزوری کی حالت میں دیکھوں اور نہیں روؤں ؟ تو امام علیہ السلام نے کہا ! آپ روئے نہیں چونکہ تمام نیکیاں مؤمن کو دی جاتی ہیں اگر کوئی حقیقی مؤمن ہو اور اس کے جسم کے تمام اعضاء قطعہ قطعہ ہو جائیں تو یہ اس کے لئے بہتر ہے او ر اسی طرح وہ مشرق اور مغر ب کا مالک بن جائے تو بھی اس کے لئے بہتر ہے ۔(۱۱۰)
۵۔ صبر اور استقامت کا ایک اور نمونہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے اگر حضرت زینب کربلا میں روتی تھی تو یہ احساسات کی بنا پر تھا اور جب وہ بولتی تھی تووہ عدالت اور نہی عن المنکر اور دشمن کو رسوا کرنے کی خاطر تھا ۔
حضرت زینب اس حد تک صابر اور شاکر تھی کہ ابن زیاد کی مجلس میں فخر کے ساتھ کہہ رہی تھی «مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلا ; میں نے صرف اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ! اے مرجانہ کے بیٹے قیامت کے دن دیکھنا کہ ہم میں سے کون جیتا اور کون ہارا؟(۱۱۱) ابن زیاد کی مجلس میں حضرت زینب کا خطبہ اتنا پر جوش تھا کہ ابن زیاد اپنی سلطنت کو بچانے کی خاطر حضرت زینب اور ان کے تمام ساتھیوں کو قید کر دیا ۔(۱۱۲)
۶۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے علی ابن بابویہ قمی ( متوفی ۳۲۹ ) کو خط لکھا کہ جس میں ان کو اور اپنے شیعوں کو صبر اور استقامت کی تاکید کی ہے انہی میں سے ایک جملہ میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ (میں تمہیں صبر اور انتظار فرج کی نصیحت کرتا ہوں ) اسی طرح سے کسی اور جملہ میں فرماتے ہے اے شیخ آپ میرے اعتمادوالے شخص ہیں آپ صبراور استقامت کریں اور ہمارے شیعوں کو بھی صبر و استقامت کی تلقین کریں ۔
محدث قمی اس خط کو نقل کرنے کے بعد لکھ رہے ہیں کہ اس خط میں صبر اور استقامت کی بہت ہی تاکید ہوئی ہے کیونکہ صبر اور استقامت کے بہت ہی اچھے نتائج موجود ہیں جس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہشت تمام رنج اور استقامت میں لپٹی ہوئی ہے ( یعنی تمام بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر اور استقامت اخیتار کرکے بہشت کے بلند ترین درجات تک پہنچ سکتے ہیں ۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کے یہ اشعار ذکر کرتے ہیں :
انی وجدت وفی الایام تجربة =للصبرعاقبة محمودة الاثر
وقل من جد فی امر یطالبه = فاستصحب الصبر الا فاز بالظفر
پھر کہتے ہیں ان اشعار کی فارسی میں معنی یہ ہے ۔
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند - بر اثر صبر، نوبت ظفر آید
بگذرد این روزگار تلختر از زهر -بار دگر روزگار چون شكر آید
یعنی صبر اور کامیابی دونوں پرانے دو دوست ہیں ۔صبر کرنے کا نتیجہ فتح اور کامیابی ہے ۔
زہر سے بھی کڑوا یہ دن گزر جائے تو پھر شکر کرنے کا وہ دن آجائے گا ۔
پھر اپنی اس بات کو مکمل کرنے کے لئے بوذر جمہر ی کاوہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن ایران کا نوشیروان بادشاہ ( بوذر جمھر جوکہ اس زمانے کا سب سےبڑا حکیم شمار ہوتا تھا اس کو بادشاہ نے قید کیا اور حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قید خانے میں بند کردو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا ۔وہ پھر کچھ عرصے تک وہا ں رہا ایک دن نوشیروان نے ان کی حالت پوچھنے کے لئے کچھ بندوں کو بھیجا جب وہ ان کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ بہت ہی خوش ہے اور انکا چہر ہ بالکل ہی حشاش بشاش ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے زندان کی اتنی سختی میں ہوتے ہوئے بھي اتنا خوش حال ہونے کی وجہ کیا ہے ؟
تو بوذر جمہر نے اس کے جواب میں کہا ! میں نے چھ چیزوں کا ایک معجون تیار کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں خوشحال ہوں ۔
اور وہ معجون میں نے ان چھ چیزوں سے ملکر بنایا ہے ۔
۱۔ خدا پر اطمئنان ۔۲۔ تقدیر الہی پر راضی رہنا ۔۳۔ صبر اور استقامت ۔۴۔ اگر میں صبر نہ کروں تو بے تابی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا ۔ ۵۔ میں نے سوچا کہ میری اس حالت سے بھی بہت سخت حالات پائے جاتے ہیں ۔
۶۔ اس ستون سے دوسرے ستون تک فرج اور گشادگی ہے ۔(۱۱۳)
ایک سؤال کا جواب :
سؤال ہوتا ہے کہ صبر اور تحمل کا حکم ایک بے ہودہ چیز ہے کیونکہ کوئی ظالم اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو ہم صبر کرتے ہوئے اس ظالم کے خلاف خاموش رہے تو یہ اس ظالم کے ظلم میں مزید اضافہ کرنے کاباعث بنتا ہے اور وہ گستاخ بن جاتا ہے ۔اور یہی کمیونسٹ والوں کا نظریہ ہے اوردین اسلام پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ دین اسلام ظالموں اور ستمگروں کے ظلم و ستم کے مقابل میں صبر و تحمل کا درس دیتا ہے پس دین آفیون کی طرح سے ایک نشہ ہے ۔
اس سؤال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اصل حقیقت کو عام دوسرے موارد کی طرح تحریف کیا گیا ہے چونکہ کلمہ صبر جو کہ تمام سختیوں اور ظلم و ستم کے مقابل مضبوط عزم اور ارادہ رکھنا اور استقامت کرنے کا نام ہے ۔ اس کو عجز اور تسلیم میں تحریف کیا گیا ہے اسی طرح سے اسکا بالکل ہی برعکس معنی کیا ہوا ہے ۔ اگر ہم لغت اور قرآن کریم کی آیات اور معصومین علیہم السلام کی روایات کی طرف رجوع کریں تو دیکھتے ہیں کہ صبر و استقامت اختیار کرنا ظلم اور ستم اور طاغوتیت کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے نہ کہ ظلم کرنے یا طاغوت کو ثابت کرنے کا ۔
اسی بنا پر اس قسم کا اشکال کرنا ایک قسم کی غلط فہمی ہے چونکہ اسلام نے صراحت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ :
«...( فَقَتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِى ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) »; زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، ۔۔۔۔(۱۱۴)
اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا :« لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ . ایسی امت ہرگز پاک و پاکیزہ نہیں ہوسکتاہے جو ضعیف اور کمزوروں کے حق کو ستمگروں سے چھین نہ لے ۔(۱۱۵)
ساتویں حکمت تواضع اور فروتنی :
حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی ہوئی نصیحتوں میں ساتویں نصیحت تواضع اور فروتنی ہے کہ جس کو تمام کمالات کی کنجی جانا جاتا ہے اس نصیحت میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرمارہے ہیں «( وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْض مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُور. ) ..)۔اور لوگوں سے (غرور و تکبرسے) رخ نہ پھیرا کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو یقینا دوست نہیں رکھتا۔(۱۱۶)
تواضع کا معنی اور اس کے اقسام :
تواضع اصل میں لفظ وضع سے لیا گیا ہے جس کا معنی تسلیم اور حقیر جاننا ہے اور اخلاق کے اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر کرجانے اور اس کے برعکس تکبر اور غرور ہے یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا ! جوکہ ایک بری صفت ہے اور فکری انحراف کا باعث بنتی ہے ۔
البتہ اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ تواضع سے مراد اپنے کو خوار و ذلیل کر نا نہیں ہے ۔ جیسا کہ بیان ہوتا ہے کہ یہ تواضع کی علامات میں سے ہے کہ انسان دوسرے لوگوں سے ملاقات کرتے وقت ان کے ساتھ خوش روی اور اچھی رفتار کے ساتھ ملا کرے اور اسی طرح سے ان سے جدا ہوتے وقت بھی بہت ہی خوش مزاجی کے ساتھ ان سے خدا حافظی کرے ان کی وہ جدائی محبت آمیز ہونی چاہیے نہ کہ کینہ اور دشمنی کے ساتھ ہو ۔
اسی طرح سے بری صفات میں سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہت بڑا سمجھے ۔
اور (وَ لا تُصَعِّرْ) کی یہ تعبیر اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہے کہ تواضع نہ کرنا انسان کے اند ر ایک قسم کی بیماری شمار ہوتی ہے چونکہ لفظ تصعر کا معنی جس طر ح سے لغت ( مصباح المنیر ) میں بیان ہوا ہے کہ یہ لفظ اصل میں( صعر )سے لیا گیا ہے جو کہ ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کو لگ جاتی ہے یعنی جب یہ بیماری اونٹ کو لگتی ہے تو اس کا گردن جھکا دیتی ہے ۔
اسی بنا پر تواضع سے خارج ہونا ایک قسم کی بیماری ہے جو انسان کی باطنی حالت کو آشکار کرتی ہے ۔
تواضع کے مختلف درجات اور نشانیاں ہیں ضروری ہے کہ ہم ان کوپہچان لیں اور خاص طور پر ان کی رعایت کریں جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ :« وَ قَالَ ع التَّوَاضُعُ الرِّضَا بِالْمَجْلِسِ دُونَ شَرَفِهِ وَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ لَقِيتَ وَ أَنْ تَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّا ; اصل تواضع یہ ہے کہ انسان کسی مجلس میں اپنی شان اور منزلت سے کمتر پر راضی ہو جائے اور جب دوسروں سے ملاقات کرے تو سلام کرنے میں پہل کرے اور فضول گفتگو سے پرہیز کرے اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو ۔(۱۱۷)
کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تواضع کی حد کیا ہے ؟ اگر کوئی اس کی رعایت کرے تو وہ متواضع کہلائے گا ؟ تو امام علیہ السلام نے انکے جواب میں فرمایا تواضع کے کئی درجات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی قدر اور منزلت کو جان لیں اور اسی کو اپنے محل میں قرار دیدے اور دوسروں کیلئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور جب کسی سے برائی دیکھے تو اس کے بدلےمیں اسے نیکی کرے اپنا غصے پر کنٹرول کرے اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرے کہ خدا وند عالم نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے(۱۱۸)
تواضع انسان کے خضوع اور خشوع کی ایک اندرونی حالت ہے جو انسان کے کردار اور رفتار اور اس کی گفتا رسے ظاہر ہوتی ہے ۔
اور کبھي ممکن ہے کہ انسان معنوی اعتبار سے اس حالت تک نہ پہنچے لیکن عملی اعتبار سے اپنے آپ کو اس تواضع کی میزان میں ڈال دیں تو ایسا شخص عملی طور پر متواضع کہلائے گا ۔
تواضع کے اقسام :
تواضع دو قسم کا ہے ۔
۱۔ خدا کے مقابل میں تواضع : اس میں حق اور قانون خدا کے مقابل میں تواضع کرنا بھی شامل ہے اور اسی طرح سے پیغمبروں اور اماموں اور اولیاء : کے سامنے تواضع کرنا بھی شامل ہے ۔
۲۔ معاشرے میں لوگوں کے مقابل میں تواضع : جیساکہ دوست ہمسایہ والدین اور استاد و شاگرد وغیرہ۔۔۔ کو شامل ہے۔
اور یہ بات واضح اور روشن ہے کہ خداوند عالم کے سامنے جو تواضع ہے وہ سب سے بلند ترین درجے پر ہے کہ جس کا مخالف تکبر اور غرور ہے جو سب سے بڑا گناہ اور شرک شمار ہوتا ہے ۔
خدا کے مقابل میں جو تواضع ہوتی ہے وہ ایمان کا جزء اور معرفت خدا کو حاصل کرنے کے لئے راہ ہموار کرتی ہے ۔
جسکا نتیجہ احکام الہی کے مقابل میں تسلیم اور انکی اطاعت کرناہے اور خدا کی عظمت کے سامنے خضوع اور خشوع حاصل کرناہے ۔
اس طریقے سے انسان اپنے کو خدا کے مقابل میں حقیر جانے اور اس کے حق پر کوئی اعتراض نہ کرے اور اپنی زندگی کے تمام امور کو خدا کی رضایت کے خاطر انجام دے اور اسی کو راضی کرنے میں قدم اٹھائے اور اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور خدا کے ساتھ اس حد تک متصل رہنا چاہیے کہ جیسا شاعر فرمارہا ہے ۔
اسیر عشق تو از هشت خلد مستغنی است
غلام كوی تو از هر دو جهان آزاد است
یعنی تیرے عشق کا اسیر آٹھوں بہشتوں سے مستغنی ہے -- اور تیری گلی کا غلام دونوں جہانوں سے آزاد ہے ۔
پیغمبر اسلام جو کہ ایک بہت عظیم اور بے نظیر انسان تھے خداوند عالم کی عظمت کے سامنے اس حد تک متواضع تھے کہ خداوند عالم کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں آپ کو بادشاہت و رسالت یا بندگی اور رسالت کے درمیان اختیار دیتاہوں کہ آپ ان میں سے کس کو انتخاب کرتے ہیں ؟ تو پیغمبر اسلام نے بندگی اور رسالت کو انتخاب کیا ۔(۱۱۹)
امام صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام کی خصوصیات اور صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔«قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مُتَوَاضِعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَل; جب پیغمبر اسلام خداوند عالم کی طرف سے رسالت پر مبعوث ہوئے تو خدا کے سامنے اتنے متواضع ہوئے کہ اپنی رحلت تک کبھی بھی کسی چیز پر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا اس حد تک تواضع کی رعایت کیا کرتے تھے ۔
پیغمبر اسلام ایک دن اپنے غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے ایک عورت وہاں سے گزری اور پیغمبر اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگی اے محمد آپ کیوں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں غلاموں کے ساتھ ہمنشین ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ؟ جبکہ آپ پیغمبر ہیں آپ بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کریں ؟ تو پیغمبر اسلام نے اس کے جواب میں کہا ۔ «وَيْحَكِ أَيُ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي ; افسوس ہو تم پر مجھ سے بڑھ کر کوئی بندہ ہے ؟(۱۲۰)
پیغمبر اکرم ص اور ائمہ معصومین کی وہ خاشعانہ اور مخلصانہ نمازیں اور انکی خضوع اور خشوع کے وہ طولانی سجدے اور دعائیں سب کے سب یا ان میں سے ہر کوئی ہمارے لئے درس عبرت ہے ہمیں خدا کے مقابل میں بہترین تواضع حاصل کرنے کادرس دیتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے بس یہی کافی ہے کہ ہم صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں اور اس میں موجود دعاؤں کا مطالعہ کریں تاکہ تواضع کی حقیقت کو حاصل کر سکیں ۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی کسی دعا میں فرمارہی ہیں «اللَّهُمَ ذَلِّلْ نَفْسِي فِي نَفْسِي وَ عَظِّمْ شَأْنَكَ فِي نَفْسِي ;
خدایا مجھے میرے نزدیک چھوٹا کردے اور اپنا مقام میرے نزدیک عظیم بنا دے ۔(۱۲۱)
اور دوسروں کے مقابل میں تواضع کرنا اس کی دوسری قسم ہے جو اخلاقی اعتبار سے بہت ہی اہم اور ضروری ہے اور انسان کی زندگی میں اس کے بہت ہی اہم آثار موجود ہیں ۔
تواضع کی تعریف میں علامہ نراقی بیان کرتے ہیں کہ تواضع سے مراد انسان کا اپنے نفس کو توڈ دینا ہے یعنی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر نہ سمجھے کہ جس کا لازمہ انسان کی گفتار اور کردار ہے جو دوسروں کے مقابل میں تعظیم اور اکرام کرنے پر دلالت کرتی ہے ۔(۱۲۲)
یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو انسان کی شرافت اور اس کی وقار و زینت کا باعث بنتی ہے اور شیطان کے مقابل میں ایک ہتھیار اور اسلحہ شمار ہوتی ہے اور انسان کے عقل میں اضافہ ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اور پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی بہت ساری روایات میں بھی اسی مطلب کو بیان کیا گیا ہے ۔(۱۲۳)
اور اوپر والی آیت میں حضرت لقمان کا مقصد بھی یہی ہے یعنی دوسروں کے مقابل میں تواضع اختیار کرنا جو خصوصی طور پر اسی کی نصیحت کی ہے ۔اسی طرح سے حضرت لقمان اپنی کسی اورگفتار میں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمارہے ہیں :( تَوَاضَعْ لِلْحَقِ تَكُنْ أَعْقَلَ النَّاس;حق کے مقابل میں تواضع اختیار کرو تاکہ عاقل ترین انسانوں میں سے شمار ہو جاو ۔(۱۲۴)
مختصر یہ کہ تواضع تمام نیکیوں کا خزانہ ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ تمام امور کی کنجی ہے اور تمام فضیلتوں کی ماں شمار ہوتی ہے جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے : (بِخَفْضِ الْجَنَاحِ تَنْتَظِمُ الْأُمُور ; تواضع اور فروتنی سے زندگی کے تمام امور منظم ہوتے ہیں ۔(۱۲۵)
امیر المؤمین اپنے کسی کلام میں پیغمبروں کی اس طرح سے تعریف کرتے ہیں:«.. وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَابُرَ وَ رَضِيَ لَهُمُ التَّوَاضُعَ فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ وَ عَفَّرُوا فِي التُّرَابِ وُجُوهَهُمْ وَ خَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ;
خداوند عالم نے تمام پیغمبروں کو تکبر سے نفرت دلائی ہے اور تواضع و فرتنی کو انکے لئے پسندکیا ہے وہ اپنے رخسار کو زمین پر رکھتے تھے اور اپنے چہرے کو خاک میں ملا دیتے تھے اور اپنی پروں کو مؤمنین کے لئے پھیلادیتے تھے ۔(۱۲۶)
کسی اور مقام پر عبادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا :«... وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِتَاقِ الْوُجُوهِ بِالتُّرَابِ تَوَاضُعاً وَ الْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْأَرْضِ تَصَاغُراً وَ لُحُوقِ الْبُطُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ الصِّيَامِ تَذَلُّلًا ;نماز میں اپنے چہرے کی بہترین جگہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کر سجدہ کرنا تواضع کا باعث بنتا ہے اور اسی طرح سے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو زمین پر رکھنا اپنے کو حقیر جاننے کی نشانی ہے اور روزہ کی حالت میں اپنے پیٹ کو کمر کے ساتھ لگا نا فرتنی کا باعث بنتا ہے ۔(۱۲۷)
اور کلی طور پر خدا کی عبادت ایسی خصوصیات میں سے ہےکہ جو کبھی بھی خدا کی معرفت رکھنے والوں سے جدا نہیں ہوسکتی ہے اور عبادت اس وقت کامل ہوسکتی ہے کہ جس میں مٹھاس ہو کہ جس سے اس عبادت کے انجام دینے والے کو لذت حاصل ہوجائے نہ کہ وہ اس عبادت کے انجام دینے سے تھک جائے ۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا میں آپ کی اس عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو کیوں نہیں دیکھتا ہوں ؟ تو اصحاب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ حلاوت اور مٹھاس کس چیز میں ہے ؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا : التواضع ۔یعنی تواضع اور فروتنی اختیار کرنے سے عبادت میں حلاوت اور لذت حاصل ہوتی ہے ۔(۱۲۸)
تواضع اور ذلت پذیری کے درمیان فرق :
تمام موضوعات میں جو چیز سب سے زیادہ توجہ کی طالب ہے وہ اس کے صحیح معنی کو بیان کرنا ہے اور افراط و تفریط سے پرہیز کرنا ہے لہذا اس جیسے اہم مسئلہ کے طرف توجہ نہ کرنا انحراف کا باعث بنتا ہے جس طرح سے صبر کا معنی کیا ہے کہ ( عاجزی اور ظلم )کے مقابل میں صبرکرنا ! حالانکہ یہ صبر کے حقیقی معنی کے برعکس ہے ۔
اسی بنا پر بعض فضائل اور رذائل کے درمیان جو حد بندی بتائی گئی ہے وہ بہت ہی نازک اور باریک ہے جیسا کہ عزت اور تکبر کے درمیان جو حد ہے سیاست اور دنیا پرستی کے درمیان اور زہد و ترک دنیا کے درمیان اور اسی طرح سے ذلت اور تواضع وغیرہ۔۔۔۔کے درمیان جو حد ہے ۔
لہذا پہلے ان کے درمیان جو رابطہ اور معیار ہے اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان کے درمیان موجود حدود کو جان سکیں اور کوئی بھي عزت کے جگہ پر تکبر کو اختیار نہ کرے اور قناعت کے نام سے بخیل نہ بنے یا تواضع کے بجائے ذلت اور خواری کو اختیار نہ کرے ۔
اور اسی طرح سے ضروری ہے کہ استثنا ءات کی طرف بھی توجہ دی جائے کیونکہ بہت ساری اخلاقی صفات ایسی بھی ہیں جو اس سے باکل ہی جدا ہیں مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن بعض ایسے موارد ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنا واجب بھی ہوجاتا ہے جیسا کہ کسی ظالم کے ہاتھوں سےمظلوم کو نجات دینا ۔
ہماری اس بحث میں اگرچہ تواضع ایک نیک اور اچھی صفت ہے لیکن یہی تواضع بعض موارد میں اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر تکبر کرنا اچھا ہے جیسا کہ کسی جنگ کا میدان ہے اور اپنے دشمن کے مقابل میں مغرورانہ انداز میں چلنا اچھا ہے تاکہ دشمن ان کی اس رعب اور دبدبہ سے خوف کھائے ۔ اس کی مثال تاریخ میں بھی ملتی ہے کہ جیسا کہ پیغمبر اسلام اور ابو دجانہ انصاری کے درمیان جنگ احد میں واقع ہوا ۔(۱۲۹)
اب ہم اپنے اس مطلب کی طرف آئینگے اور وہ یہ ہے کہ اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ تواضع ذلت اور خواری یا چاپلوسی جیسی صفات کا باعث نہ بنے جیسا کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ تواضع یہ ہے کہ انسان اپنے کو دوسروں کے مقابل میں ذلیل و خوار کرے اور ایسے اعمال انجام دے تاکہ لوگوں کے نظروں سے گر جائے اور اس کو سوء ظن کی نسبت دے دیں جیسا کہ بعض صوفیوں کے حالات میں نقل ہوا ہے ۔
لیکن اسلام کبھی بھی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تواضع کے نام پر اپنے کو حقیر کرے اور انسان کی جو کرامت ہے وہ پائمال ہو جائے ۔
اس کے بارے میں فیض کاشانی لکھتا ہے کہ دوسری عام اخلاقی صفات کی طرح تواضع بھی دو اطراف یعنی (افراط اور تفریط ) پر مشتمل ہے افراط یعنی ( تکبر ) اور تفریط یعنی(ذلت اور پستی کو قبول کرنا ) اور ان کے درمیانی حد وہی تواضع ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ تواضع وہی ہے جو انسان اپنے کو چھوٹا سمجھے یعنی بغیر کسی ذلت اور خواری کے ! مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور انکو پیچھے چھوڑدے تو وہ متکبر کہلائے گا لیکن جو آپنے آپ کو سب سے پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ شخص متواضع کہلائے گا لیکن اگر کوئی معمولی شخص مثلا کسی دانشمند یا کسی بڑے عالم کے پاس حاضر ہو جائے اور وہ عالم اس کا احترام کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور اس کو اپنی جگہ پر بٹھادے اور اس کے جوتے اٹھانے لگے تو یہ اس کی تواضع نہیں کہلائےگا بلکہ یہ ایک قسم کی ذلت ہے جو قابل مذمت ہے ۔(۱۳۰)
پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ ہواہے جیسا کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ۔
«وَ مَنْ أَتَى ذَا مَيْسَرَةٍ فَيَخْشَعُ لَهُ طَلَبَ مَا فِي يَدِهِ- ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِه ; اگر کوئی شخص کسی امیر اور مالدار شخص کے پاس آئے اور وہ اس کی دولت کی خاطر یا اس سے کچھ حاصل کرنے کی امید سے اس کے سامنے تواضع اور فروتنی اختیار کرے تو اس کے دین کا تیسرا حصہ ضایع ہو جائے گا ۔(۱۳۱)
اسی طرح کی ایک اور روایت امام علی علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے ۔(۱۳۲)
امام صادق کا فرمان ہے «مَا أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ تَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُ »; مؤمن شخص کے لئے برا ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ علاقہ اور رغبت پیدا کرے جو اس کو ذلت اور خواری میں مبتلا کرے ۔(۱۳۳)
چاپلوسی ایک قسم کی ذلت اور پستی کو قبول کرنے کا نام ہے جو عام طور پر حرص اور طمع سے وجود میں آتی ہے اور بعض لوگ کبھی تواضع کا غلط معنی کرتے ہوئے اسے با ارزش سمجھتے ہیں جبکہ یہ چاپلوسی صرف بعض موارد کے علاوہ بری سمجھی جاتی ہے جو انسان کی کرامت پر بہت ہی بھاری چوٹ لگا دیتی ہے ۔
امام علی علیہ السلام اپنےکسی کلام میں فرماتے ہیں ):الثَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ ; حد سے بڑھ کر کسی کی تعریف کرنا چاپلوسی ہے ۔(۱۳۴)
اور بسا اوقات بعض افراد تواضع کے عنوان سے حد سے بڑھ کر تعریف کرتے ہیں یا حد سے بڑھ کر اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں تو یہی وہ چاپلوسی ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں : «لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ التَّمَلُّقُ وَ لَا الْحَسَدُ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعِلْم ; چاپلوسی اور حسد مؤمن کے اخلاق میں سے نہیں ہے مگر علم حاصل کرنے کے راستے میں ۔(۱۳۵)
اسی بنا پر اسلام نے پاؤں پر بوسہ دینا منع کیا ہے اور بعض روایات کے مطابق ہاتھوں پر بوسہ دینا بھی مناسب نہیں مگر والدین کے ہاتھوں کے یا معلم اور استاد کے یا کسی دینی راہنما کےجو اس کے احترام کےخاطر ہو اور اسی طرح سے والدین اپنے چھوٹے بیٹے کو محبت کی وجہ سے چومنا ۔
روایت میں ہے کہ یونس بن یعقوب نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاتھ آگے کریں میں ان کا بوسہ لونگا تو امام نے ہاتھوں کو آگے کیا اور پھر میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤ آپ کے سر کا بوسہ دونگا تو امام نے اپنے سر کو آگے کیا تو میں نے بوسہ دیا پھر میں نے امام سے عرض کیا پاؤں کا بوسہ لونگا تو امام نے قبول نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کے بوسہ دینے کے بعد جسم کے کسی اور عضو کا بوسہ لینا مناسب نہیں ہے ۔(۱۳۶)
تواضع کی علامت اور اس کے درجات :
تواضع اور اس کی علامات کے بارے میں پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کے اقوال میں تواضع کے بعض صحیح طریقوں کی طرف اشارہ ہوا ہے ہم یہاں پر آپ کی توجہ کو انکی طرف مبذول کرائنگے جیسا کہ مجلس میں سب سے آخر میں بیٹھنا سلام میں پہل کرنا اونچی آواز میں سلام کرنا اور خود نمائی سے پرہیز کرنا اپنی تعریف کرنے سے پرہیز کرنا اور دوسرے لوگوں کی تعریف کرنے کو پسند نہ کرے امیر اور فقیر لوگوں کے درمیان فرق کا قائل نہ ہو جائے راستے میں دوسروں سے آگے نہ بڑھے ۔
امیر المؤمنین کا فرمان ہے «مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِمَا عِنْدَ اللَّه; جزاء الہی کو حاصل کرنے کی غرض سے فقیروں کے مقابل میں امیروں کی تواضع اور فروتنی کتنی ہی اچھی ہے ۔(۱۳۷)
آٹھویں اور نویں حکمت :
بد رفتاری اور غرور:
آٹھویں اور نویں حکمت میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس طرح سے نصیحت کررہے ہیں : «( وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُور ) ;(۱۳۸) اور لوگوں سے (غرور و تکبرسے) رخ نہ پھیرا کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو یقینا دوست نہیں رکھتا۔
آداب معاشرت اور آداب اسلامی کے اہم ترین موارد میں سے ایک یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ نیک رفتاری سے پیش آئیں اور ہر قسم کی تکبر اور غرور سے پرہیز کریں چونکہ غرور اور خود پسندی برے اعمال کے انجام دینے کا باعث بنتے ہیں جس کا نتیجہ دوستوں کے درمیان اختلاف اور جدائی اور کینہ کا سبب بنتا ہے ۔
تکبر انسان کی ایک باطنی اور انحرافی حالت ہے جو کہ انسان کی زندگی میں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے ۔
حضرت لقمان کی اس نصیحت میں تکبر اور خود پسندی کی دو اہم نشانیوں کے طرف اشارہ ہوا ہے کہ جن سے پرہیز کرنا بہت ہی ضروری ہے ۔
۱۔غرور اور تکبر کی وجہ سے دوسروں سے رخ نہیں پھیرانا :
۲۔ غرور اور تکبر کی وجہ سے زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلنا :
یہ دو ایسی بری صفات ہیں جو تکبر کی وجہ سے انسان کے اندر وجود میں آتی ہیں جو انسان کی زندگی اور معاشرے پر بہت ہی برا اثر رکھتی ہیں اور حتی بعض اوقات انسان کی دوستیوں کو دشمنی میں تبدیل کرتی ہیں اور ان کے درمیان موجود محبت اور صمیمیت کو کینہ اور عداوت میں تبدیل کرتی ہیں جس سے انسان کی زندگی میں اختلاف وجود میں آتا ہے خصوصا میاں اور بیوی کے درمیان اور ہمسایوں اور دوستوں کے درمیان اختلاف وجودمیں آتا ہے ۔
ممکن ہے یہاں پر یہ سؤال پیدا ہوجائے حضرت لقمان کی اس نصیحت میں انہوں نے جزئیات کو بیان کیاہے ؟
تو اس سؤال کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتےہیں کہ چونکہ انسان کے اندر بری صفات انہی جزئیات کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں مثال کے طور پر ماہ رمضان کے مہینے میں کوئی شخص سب کے سامنے سگریٹ پیتا ہے اور اس کے دھواں کو آسمان کی طرف پھونکتا ہے تو اس کی یہ حالت ظاہری طور پر ایک جزئی چیز ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ خداوند متعال کے مقابل میں اس کے غرور کی علامت اور نشانی ہے اور معاشرے کے لوگوں کے سامنے ایک توہین اور گستاخی جو اس بندے کی اندرونی حالت یعنی ان کی روح کے فاسد ہونے کو بیان کرتی ہے ۔
اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ انسان کے جسم کے بعض حصوں پر جو چھوٹے چھوٹے دانے موجود ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے نظریے کے مطابق جسم کی گندگی کی وجہ سے ہے جو خون اور گوشت کے درمیان جمع ہونے کیوجہ سے وجود میں آتے ہیں ۔
جبکہ یہی دانے اور نشانیاں انسان کے نفس (سانس ) کا علاج اور انکو پاک اور صاف کرنے کے لئے ہوتے ہیں ۔
حقیقت میں حضرت لقمان اپنی اس نصیحت میں تمام انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنے اندرونی حالت کو پہچان لیں کیونکہ انسان کی اندرونی حالت کسی نہ کسی طریقے سے ان کے چہرے پر یا ان کے کردار و رفتار سے ظاہر ہو جاتی ہے ۔ جیسا کہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے ۔ «مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِه ; جو بھی اپنے دل میں کوئی بات چھپا دیتا ہے وہ اس کی زبان سے نکلے گا یا اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے گا ۔(۱۳۹)
البتہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت لقمان کی اس نصیحت سے مراد ہر قسم کی تکبر اور غرور سے پرہیز کرنا ہے ۔
اب مناسب ہے کہ ہم ان دونوں نشانیوں کا تجزیہ و تحلیل کریں ۔
۱۔غرور اور تکبر سے دوسروں سے رخ پھیرنا :
آداب اسلامی میں ہے ایک یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ملتے وقت یا ان سے جدا ہوتے وقت ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئیں سلام کریں اور خوش رفتاری سے ملیں یعنی آداب اسلامی کی رعایت کریں ۔ غصے کی حالت بناکر دوسروں سے منہ نہ موڑ یں چونکہ ایسا کرنے سے انسان کےاندر خود پسندی اور غرور پیدا ہوتا ہے جس کےنتیجہ میں انسان کی ایک دوسرے سے دوستیاں اور رابطے ختم ہو جاتے ہیں ۔
حضرت لقمان کی تعبیر میں جو بیان ہوا کہ :(( وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ) ) کلمہ تصعر اصل میں لفظ( صعر ) کے مادہ سے لیا گیا ہے ۔ یہ اصل میں ایک بیماری کا نام ہے جو غالبا اونٹ کو لگ جاتی ہے یعنی یہ بیماری اونٹ کی گردن کو ٹیڑھا کرتی ہے ۔ یہ تعبیر اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ کوئی انسان جب دوسروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی اخلاقی بیماری کی نشانی ہے اور اس کے فکری انحراف کا ایک قسم ہے جبکہ سالم انسان کبھی بھی دوسروں کے ساتھ اس طرح کی رفتار اور اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کرتے ۔
کیونکہ دوسرے سے منہ موڑنا انکی توہین شمار ہوتا ہے اور اس کے بہت ہی برے آثار جیسے ( کینہ اور دشمنی ) وغیرہ وجود میں آتے ہیں اور انسان کے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کا باعث بنتے ہیں ۔ اور حتی کہ خداوند متعال نے پیغبر اسلام کو کافروں سے دوری اختیار کرنے کے بارے میں اس طرح سے حکم دیا ہے کہ «... وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا»; اور شائستہ انداز میں ان سے دوری اختیار کیجیے۔(۱۴۰) یعنی ان سے آپکی یہ دوری محبت آمیز اور دلسوزی کے ساتھ ہو ۔
خداوند عالم کے اس حکم میں ان کے ساتھ نیک اور اچھی رفتار سے پیش آنے میں ایک حکمت ہے یعنی انکو اپنی طرف جلب کرنے کا ایک طریقہ ہے ۔
علامہ طبرسی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ «و في هذا دلالة على وجوب الصبر على الأذى لمن يدعو إلى الدين و المعاشرة بأحسن الأخلاق و استعمال الرفق ليكونوا أقرب إلى الإجابة; یہ آیت لوگوں کے ساتھ نیک اخلاق اور اچھی رفتار سے پیش آنے کو ثابت کرتی ہے تاکہ ان کو جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ جلدی قبول کریں ۔(۱۴۱)
اور پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی روایات میں بھی اس کی تاکید ہوئی ہے جیساکہ روایت میں ملتا ہے ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انکو نصیحت کرنے کو کہا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا : «الْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ .; اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خوش رفتاری سے پیش آنا ۔(۱۴۲)
اور اسی طرح سے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا :« زِينَةُ الشَّرِيفِ التَّوَاضُع ; لوگوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی کے ساتھ ملنا انسان کی شرافت اور زینت شمار ہوتی ہے ۔(۱۴۳)
نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوسروں سے ملتے وقت ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور ہر قسم کی بداخلاقی اور غرور دور رہے تاکہ اس کے لئے آرامش اور محبت کا باعث بنے ۔
۲۔ غرور اور تکبر کے ساتھ چلنا :
خود خواہی اور تکبر سے ظاہر ہونے والی ایک صفت کہ جس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس سے بچنے کی سفارش کی ہے وہ مستی اور مغرورانہ انداز میں چلناہے جو انسان میں موجود بری صفات میں سے ہے اس طریقے سے چلنے والے کو ( مشی مرح یا مستی اور غفلت ) سے تعبیر کیا گیا ہے ۔
یہ ایک قسم کی بزرگنمائی ہے یعنی اپنے کو بہت بڑا کرکے دکھانا جو انسان کو سرکش بناتا ہے اسی لئے خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے : «( وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنا ) ۔۔; اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین میں (فروتنی سے) دبے پاؤں چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو سلام کہتے ہیں(۱۴۴)
اسی طرح سے فرماتے ہیں : «( وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً ) ۔۔۔۔ ۔۔۔۔;
اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلاشبہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ ہی بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔(۱۴۵)
خداوند عالم کا اس طرح سے حکم دینا انسان کے غرور کو ختم کردیتا ہے کہ انسان جتنا بھی تکبر کرے نہ ہی وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے ۔
اسی بناپر خدا وند عالم کی مخلوق کو دیکھتے ہی اپنے کو ایک ناچیز جانے اور ہر قسم کے غرور کو اپنے اندر سے نکال دے نہ کہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے زمین پر اکڑ اکڑ کر چلے ؟ ۔
پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین اپنی زندگی کے تمام امور میں حتی کہ چلتے وقت بھی تواضع کی انتہائی رعایت کیا کرتے تھے جیساکہ پیغمبر اسلام کا قول ہے کہ «مَنْ مَشَى عَلَى الْأَرْضِ اخْتِيَالًا لَعَنَتْهُ الْأَرْضُ وَ مَنْ تَحْتَهَا وَ مَنْ فَوْقَهَا ;جو شخص زمین پر غرور اور تکبر سے چلتاہے تو جو چیز اس زمین پر ہے اور جو اس زمین کے اندر ہے سب کے سب اس پر لعنت کرتے ہیں ۔(۱۴۶)
ایک دن پیغمبر اسلام کسی گلی سے کزر رہے تھے تو ایک گروہ کودیکھا جو جمع ہوئے تھے پیغمبر اسلام ان کے پاس جاکر پوچھنے لگے کیا ہوا ہے ؟ تو انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ ایک دیوانہ ہے اپنی حرکتیں اور ہنسا دینے والی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف جلب کرتا ہے اور لوگ اس کےتماشا دیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں تو پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو کہا یہ شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے لیکن کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حقیقی دیوانہ کون ہے ؟ تو انہوں نے کہا ! ہاں بتائیے ؟ تو پیغبر اسلام نے فرمایا:
«الْمُتَبَخْتِرُ فِي مِشْيَتِهِ النَّاظِرُ فِي عِطْفَيْهِ الْمُحَرِّكُ جَنْبَيْهِ بِمَنْكِبَيْهِ فَذَاكَ الْمَجْنُون ; اصل دیوانہ وہ ہے جو مغرور ہو کر چلتا ہے اور ہمیشہ اپنے کاندھوں کو ادھر ادھر ہلاتا رہتا ہے اور اپنے کو باربار دیکھتا ہے تو ایسا شخص اصلی اور حقیقی دیوانہ ہے ۔(۱۴۷)
امام علی علیہ السلام سے بھی نقل ہواہے کہ اسلام کے ان ابتدائی دنوں میں کسی جنگ کے موقع پر ابودجانہ انصاری اپنے سر پر ایک عمامہ باندھ کر مغرورانہ انداز میں چلنے لگے تو پیغمبر اسلام نے انکو کہا اس طرح کے چلنے کو خداوند عالم پسند نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ جنگ کا میدان ہو جو دشمن کے مقابل میں ہو ۔(۱۴۸)
اس مطلب کو زیادہ واضح اور روشن ہونے کےلئے آپ کی توجہ کو ان احادیث کی طرف مبذول کرتے ہیں ۔
۱۔ بشیر نبال کا کہنا ہے کہ مدینہ کی مسجد میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں کالے رنگ کا ایک غلام جو اپنے پاؤں کو زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے داخل ہوئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا : یہ شخص جبار ہے ۔ تو میں نے امام کو کہا یہ شخص بے چارہ ایک سائل ہے تو فرمایا بلکہ وہ جبار ہے ۔(۱۴۹) یعنی اگرچہ وہ فقیر ہے لیکن جب وہ اس انداز سے مستی اور مغرورانہ انداز میں چلتا ہے تو جبار اور ستمکاروں میں سے شمار ہوتا ہے ۔
۲۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا : خداوند متعال نے انسان کے تمام اعضاء و جوارح پر ایمان کو واجب قرار دیا ہے اور ان کے درمیان تقسیم کیاہواہے ان میں انسان کے پاؤں پر واجب ہے کہ وہ گناہ کی طرف نہ بڑھیں بلکہ خدا کی راہ میں اٹھے اسی لئے خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم زمین پر تکبر اور غرور کے انداز میں نہ چلو یعنی (زمین پر اکڑ کر نہ چلو،)(۱۵۰)
اور اسی طرح سے فرماتے ہیں : چلتے وقت اعتدال کی رعایت کرو ۔(۱۵۱)
۳۔ پیغمبر اسلام کی سیرت میں ملتا ہے جب وہ مرکب پر سوار ہوتے اور چلتے وقت راستے میں جب کوئی پیدل ان کے مقابل میں آتا تو وہ اس کو اپنے مرکب پر سوار کرتے اور جب وہ سوار ہونے کو قبول نہ کرتا تو پیغمبر اسلام کہتے کہ آپ مجھ سے آگے آگے چلو اور فلان جگہ پر میرے ساتھ ملاقات کرو ۔(۱۵۲)
دسویں حکمت : آواز میں اعتدال :
حضرت لقمان کی آخری نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی ہے وہ قرآن مجید میں اس طرح سے بیان ہوا ہے ۔
( وَ اقْصِدْ في مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ ) :
اور اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھ، یقینا آوازوں میں سب سے بری گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔(۱۵۳)
اسلام اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے یعنی انسان اپنے زندگی کے تمام امور میں افراط اور تفریط سے پرہیز کرے تو یہ اسلام کا اصل رکن شمار ہوتاہے ۔ اسی لئے قرآن مجید میں امت اسلام کو امت وسط سے یاد کیا گیاہے جو تمام عالمین کے لئے نمونہ عمل قرار دیا ہے جیسا کہ فرمایا :
( وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطا ) ً :
اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔(۱۵۴)
معصومین کی بہت سارے روایات میں نقل ہوا ہے فرمایا :
نحن الامة الوسطی، و نحن شهداء الله علی خلقه و حججه فی ارضه... نحن الشهداء علی الناس... الینا یرجع الغالی و بنا یرجع المقصر ;
ہم امت وسط ہیں اور مخلوق خدا پر ہم گواہ ہیں اور زمین پر ان کے حجت ہیں اور لوگوں پر ہم ہی گواہ ہیں غالی اور مقصر ہمارے طرف لوٹ آئیں گے اور ہمیں اپنا الگو قرار دینگے ۔(۱۵۵)
اعتدال کے اقسام میں سے ایک چلتے وقت اعتدال کی رعایت کرنا ہے اس طریقے سے کہ اس کا چلنا مغرورانہ انداز میں یا بے ادبی سے نہ ہو اور سستی اور کاہلی کے حال میں نہ ہو ۔ چلنے کا صحیح طریقہ اور اور انکے آداب کو گزشتہ بحث میں بیان کیا گیا ہے ہم یہاں اسی پر اکتفا کرتے ہیں ۔
اعتدال کی ایک اور قسم آواز میں اعتدال کی رعایت کرنا ہے اور یہ آداب اسلام میں سے ہے کہ انسان اپنی آواز میں اعتدال پیدا کرے۔ یہاں پر اسی بحث کو حضرت لقمان کی آخری نصیحت کے طور پر اس کی وضاحت کریں گے ۔
آواز میں اعتدال کا معنی :
آواز میں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی آواز میں آداب اسلامی کی اس طریقے سے رعایت کرے کہ اس کا آواز اتنا اونچا نہ ہو کہ جس سے دوسروں کو اذیت ہو تی ہو ۔
اگرچہ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ آواز کئی قسم کی ہے جیسا کہ گاڑیوں کی ہارن کی آواز یں اور مسجدوں اور امام بارگاہوں میں لگے ہوئے لوڈاسپیکرز کے آوازیں اور خود انسان کی مختلف آوازیں جو دوسروں سے باتیں کرتے وقت یاٹیلیفون پر بات کرتے وقت اور اسی طرح سے غیر طبیعی آوازیں کہ جو انسان کو چھینک آنے سے یا کھانسی کرتے ہوئے نکلتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ان سب آوازوں کے رعایت کرنی چاہیے ۔
اسی طرح سے دوسری آوازیں جیسا کہ ٹیلی ویژن اور ریڈو اور مختلف کارخانوں کے آوازیں جو عصر حاضر کے ٹیکنالوجی میں شمار ہوتے ہیں ان سب کی آوازیں جو انسان سے سکون اور آرامش کو چھین اس کو اذیت اور آزار کا باعث بنتا ہے بلکہ انسان کے سننے کا جو حس ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے ۔ اور سائنسدانوں کے مطابق اس قسم کی آواز یں انسان کے اعصاب اور دل پر بہت ہی برا اثر رکھتی ہے ۔
ایسی آوازیں جو کبھی شادی بیاہ کے عنوان سے کبھی کسی مجلس اور جشن کے عنوان سے یا کبھی کھیل کود کے میدان سے نکلی ہیں بہت ہی خطرناک قسم کی آوازیں شمار ہوتی ہیں ۔
اور کبھی لڑھائی جھگڑے کی صورت میں اور زار و قطار رونے کی آوازیں جو کہ فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں ان سب کی رعایت کرنی چاہیے اور اگر اس کی رعایت نہ کریں تو انسان میں ضد اور عداوتوں کو اجاگر کرتی ہے کہ جس سے لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی آوازیں جو دوسروں کو تکلیف اور اذیت کا باعث بنتے ہیں وہ گناہان کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں جو کہ حق الناس شمار ہوتا ہے یعنی اس گناہ کے لئے اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے تو اس کی قبولیت کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ اس بندے کو راضی کرے کہ جن کی آوازوں کے انکو اذیت پہنچی ہو ۔
اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتے ہے جب تک وہ ان کو راضی نہ کریں ۔ لہذا اپنی آوازوں میں آداب کی رعایت کرنے چاہیے
اور خصوصا ڈرائیور حضرات جو کہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ گاڑیوں کی رش کی وجہ سے وہ زیادہ جوش میں آتے ہیں اور صبر و تحمل کرنے کے بجائے ہارن لگاتے رہتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے ۔
اسی بنا پر بعض ملکوں میں اس طرح کی آوازوں کے آلودگی سے بچنے کے لئے مختلف قوانین بنایا ہے تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو اور معاشرے کے اندر اعتدال اور آرامش برقرار رہے ۔ چونکہ معاشرے میں بہت سارے بیمار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان خطرناک آوازوں کے وجہ سے اپنی جان کو ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ دل کی بیماری میں مبتلا ہے جب وہ کسی جگہ سے گزر رہا ہے تو اچانک ایک لڑکا اس کے سامنے سے پٹاخہ پھینک دیتا ہے جس کے پھٹنے سے خطرناک قسم کی آواز نکلتی ہے جس کی وجہ سے وہ دل کا مریض اسی جگہ پر مرجاتا ہے یا اسکو بہت شدید قسم کا چوٹ لگتا ہے ۔ تو ہر انسان اس قسم کے حرکات کو انجام دینے کو پسند نہیں کرتا ہے اور جو یہ کام انجام دیتا ہے ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں ۔
اور اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ٹیلیفون پر کسی کو اذیت کرنا یا دروازے کی گھنٹی مار کر بھاگ جانا اور چیزیں بھیجنے کے خاطر اپنے گاڑی میں لوڈ اسپیکر لگا کر گلی گلی میں اعلان کرنا یہ سب آواز کی آلودگیوں میں سے شمار کرسکتے ہیں جو کہ حق الناس شمار ہوتا ہے ۔
اور اسی طرح سے شاگردوں کے اپنے استاد کے سامنے شور کرنا بھی اسی میں شامل ہوتا ہے ۔
اسی بنا پر ہر قسم کی آواز میں اعتدال کی رعایت کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کے لئے اذیت نہ ہو ۔ کیونکہ سکون اور آرامش لوگوں کا حق بنتا ہے اور ان کی رعایت نہ کرنا انکے حق میں تجاوز شمار ہوگا جو بہت بڑا گناہ جرم ہے ۔
آواز پر کنٹرول کرنا قرآن کی نظر میں :
قرآن مجید میں تین جگہوں پر اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے ۔(۱۵۶) کہ ان میں سے دو ایسے موارد ہیں کہ جن میں پیغمبر اسلام سے بات کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے ۔اور ان میں سے ایک مورد ایسا ہے جس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہوئی نصیحتوں میں سے جانا گیا ہے ۔حضرت لقمان کی اس نصیحت میں جیساکہ ابتدا کلام میں بیان ہوا اس طرح سے بیان ہو رہا ہے ۔
( وَ اقْصِدْ فىِ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحْمِير ) )
اور اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھ، یقینا آوازوں میں سب سے بری گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔(۱۵۷)
اس آیت میں دو اہم مطلب کو بیان کیا ہے ۔
پہلا یہ کہ : جب آپ کسی سے بات کرتے ہو یا اس کو آواز دیتے ہو تو اپنی آواز کو دھیمی رکھو یعنی اپنی آواز کو اونچی نہ کرو ۔
لفظ ( غض ) اصل میں آواز کو دھیمی رکھنے کے معنی میں ہے یعنی بلندی سے نیچے کی طرف آنے کے معنی میں ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اپنی آواز کو بالکل ہی نرم اور ہلکا آواز میں بات کرو اور چیخنے اور پکارنے سے بچو !
اور دوسرا یہ کہ : حضرت لقمان کی اس نصیحت میں اونچی آوازوں کو گدھوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے ۔ اگرچہ اس سے بڑھ کر خوفناک آوازیں ہیں لیکن اسی کے ساتھ تشبیہ دینا اس کی عمومیت کے وجہ ہے جو کہ اس قسم کی مثالیں ہر زمان اور ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں جو عمومیت کی بنا پر ہے اور بہت ہی واضح اور روشن ہے ۔
اور اس کے علاوہ کہ یہ آواز دوسرے آوازوں سے بہت ہی خوفناک اور بری ہے کبھی بغیر کسی مقصد اور ہدف کے بے اختیار نکلتی ہے جس طرح سے انسان کے منہ سے نکلنے والی وہ آوازیں اور نعرے جو بغیر کسی مقصد کے ہوتے ہیں ۔
امام صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:
(هی العطیسة المرتفعة القبیحة ...;)
یعنی بلند آواز میں چھینگنا بہت ہی برا ہے ۔(۱۵۸)
اور بعض مفسرین سے بھی نقل ہواہے کہ
(أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ )
سے مراد بری آواز ہے اور کدھے کی آواز دوسرے حیوانوں کے نسبت سے بہت ہے برا ہے چونکہ اس کی آواز کی ابتداء میں برے سانسوں سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد بری آواز نکلتی ہے ۔(۱۶۱)
اور انسانوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو جو گہری سانسوں کے ساتھ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں ۔
قرآن مجید میں دو ایسے موارد کو بیان کیا گیا ہے کہ جن میں آواز میں اعتدال اور اس کی رعایت کرنے کے بارے میں ذکر ہوا ہے جیساکہ سورہ حجرات میں ارشاد ہوتاہے ۔
( يَأَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبىِِّ وَ لَا تجَهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تحَبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنتُمْ لَا تَشْعُرُون ) :
اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔(۱۶۲)
اور اس کے بعد والی دو آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے ۔
جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں بلاشبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے ۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں بلاشبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔
ان آیتوں میں بیان ہورہا ہے کہ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کے سامنے بات کرتے وقت آداب کی رعایت کرے اور کبھی بھی ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرے اور ان سے برے الفاظ میں بات نہ کرے انکی حرمت کی حفاظت کرے اور نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرے ۔ جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام استاد اور شاگرد کے درمیان حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔
شاگر د کا اپنے استاد پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرے ۔(۱۶۳)
نتیجہ یہ ہے کہ : ان آیات میں آداب اسلامی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے سامنے بات کرتے وقت اپنی آواز میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کو بیان کرتے ہے اور خصوصا پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کے سامنے ان آداب کی رعایت کرنے کی زیادہ تاکید ہوئی ہے ۔۔
آواز میں اعتدال بزرگوں کے کلام میں :
پیغمبر اسلام کا فرمان ہے :
ان الله یحب الصوت الخفیض، و یبغض الصوت الرفیع;
خداوند عالم نرم اور دھیمی آواز کو پسند کرتا ہے اور اوچی آواز کو پسند نہیں کرتا ہے ۔(۱۶۴)
اور امام علی علیہ السلام جہاد کے بارے میں فرماتے ہیں :
«و امیتوا الاصوات فانه اطرد للفشل;
جنگ کے میدان میں ایک دوسرے سے بحث کرنے پرہیز کریں یہ سستی اور کاہلی کو دور کرتی ہے ۔(۱۶۵)
امام کسی اور کلام میں فرماتے ہیں اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھنا اور بولتے وقت اپنی آواز میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا چونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے اور اچھی دینداری شمار ہوتی ہے ۔(۱۶۶)
استثناءات :
البته اس بات کی طرف متوجه رهنا چاہیے کہ بعض موارد ایسے ہیں کہ جن میں آواز کو بلند کرنا اچھا اور پسندیدہ ہے ۔ مثال کے طور پر ظالم کے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا اور اپنے حق کا دفاع کرتے ہوئے آواز کو بلند کرنا اور اس کے علاوہ وہ موارد کہ جہاں پر قرآن مجید کی محفلیں ہوتی ہے یا علمی مباحثے اور مناظرے ہوتے ہیں تو ان موارد میں آواز کو بلند کرنا پسندیدہ اور قابل ستایش ہے ۔
اسی لئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ۔
( «لَّا يحُبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَ كاَنَ اللَّهُ سمَيعًا عَلِيمًا ) ۔
اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی (کسی کی) برملا برائی کرے، مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو اور اللہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔
یہاں پر ( جہر ) سے مراد آشکار اور کھل کر بات کرنا ہے جو انسان کی باتوں کے ساتھ مربوط ہے تو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا والوں کی مظلومیت اور ان کی فریادیں اسی آیت کے مصداق ہیں ۔
روایت میں آئی ہے پیغمبر اسلام کا صحابی ( ثابت بن قیس )جو کہ خطیب تھے جب سورہ حجرات کی آیت ۲ کے نزول کے بارے میں سن لیا کہ (۔۔اونچی آواز میں بات کرنے سے انسان کے اعمال ضایع ہونے کا باعث بنتا ہے ۔)تو اس کو بہت دکھ ہوا لیکن پیغمبر اسلام نے ان کو کہا آپ ڈرے نہیں آپ کی وہ بلند آواز خطابت اور تقریر کے خاطر ہے آپ کے حساب دوسروں سے جدا ہے۔(۱۶۷)
انہی استثناءات میں سے ایک نماز کی حالت میں بلند آواز سے آذان دینا ہے اور حج انجام دیتے وقت بلند آواز میں لبیک کہنا ہے ۔ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے
«یغفر للمؤذن مد صوته و بصره;
مؤذن کی آواز جس حد تک دور جاتی ہیں اتنا ہی اس کو بخش دیا جاتا ہے۔(۱۶۸)
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اتنا ہی بلند آواز میں آذان دینی چاہیے تاکہ کہ آواز دور دور تک جائے اور اتنا ہی زیادہ ثواب ملے ۔
اور اسی طرح سے استکبار اور طاغوت کے خلاف جو آوازیں اور شعار بلند ہوتے ہیں جو اپنے حق کے دفاع کي خاطر هوتے ہیں وہ بھی انہی استثناءات میں سے شمار ہوتے ہیں یہ آوازیں جتنا ہی بلند ہوگا اتنا ہی دشمن کی پستی اور انکے ذلیل ہونے کا باعث بنے گا۔
لیکن صرف ان کچھ موارد کے علاوہ کسی اور مورد میں انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آپنی آواز کوبلند کرے چونکہ اس سے مؤمنین کی حقارت کا باعث ہوتا ہے ۔
امام خمینی کی ایک نصیحت :
لوڈ اسپیکر پر آواز کو بلند نہ کرنے کی طرف امام خمینی کی سفارش :
امام خمینی ان بے جا آوازوں کے بارے میں جو دوسروں کے لئے مزاحمت کا باعث بنتے ہیں اگرچہ وہ عبادت کے عنوان سے ہی کیوں نہ ہو ان سے پرہیز کرنے کی نصیحت کرتےہیں ۔
ہم یہاں پر بطور نمونہ امام خمینی کی دو نصحیتوں کو ذکر کریں گے ۔
۱۔ امام کی یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے مجالس میں یا امام بارگاہوں میں اوڈ اسپیکر لگاتے ہیں وہ دوسرے ضعیف اور کمزور لوگوں کی رعایت کریں کیونکہ ان میں بہت سارے بیمار اور بوڑھے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کی آوازوں سے تکلیف اور اذیت ہوتی ہے لہذا لوڈ اسپیکر کو باہر نہ لگایا جائے بلکہ ان کو مسجدوں کے اندر ہی لگائے اور اسی حد تک ہی محدود رکھے ایسا نہ ہو کہ خدا کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی معصیت کا باعث بنے ۔
اور رمضان کے مہینے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسروں کو آرامش دے ۔۔۔۔۔۔(۱۶۹)
۲۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے کام ہیں جو ظاہری طور پر اسلامی ہوتے ہیں لیکن بےتوجہی کی وجہ سے وہ غیر اسلامی شمار ہوتےہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا کہ دین کی خدمت کریں لیکن وہ عمل کرتے وقت اس طرح سے انجام دیتے ہیں کہ وہ معصیت اور گناہ شمار ہوتا ہے یعنی اسلام کے نام پر بعض ایسے کام انجام دیتے ہیں جو اصلا اسلام کے ساتھ ہماہنگ نہیں ہوتے ۔ جیسا کہ آدھی رات کو تکبیر کی آوازیں لگاتے اور نعرے لگانا شروع کرتے ہیں کہ جس سے ان کے ہمسایوں کو اذیت کا باعث بنتے ہیں تو ان کی یہ خدمت کرنا گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے ۔
اگر آپ اپنے گھر میں مجلس پڑھاتے ہیں تو لوڈ اسپیکر کو اسی گھر کے اندر ہی محدود رکھے تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے ۔ اگر آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس لوڈ اسپیکر کی آواز باہر نہ جانے دیں اور محلہ کے لوگوں کو اذیت نہ ہو ۔ اور اگر ان کو تکلیف پہنچی یا انکو اذیت ہوئی تو آپ کی یہ خدمت عبادت کے بجائے گناہ کبیرہ ہو جائےگا چونکہ کسی مسلمان یا مؤمن کو اذیت دینا سب سے بڑا گناہ شمار ہوتا ہے ۔(۱۷۰)
گیا رویں حکمت : قرآن مجید سے بہرہ مند ہونا:
قرآن مجید میں انسان کی اچھی خصوصیات کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے
( وَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يخَرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَانًا ) ۔
اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔(۱۷۱)
یہ اہم ترین خصوصیات میں سے ہیں جو خداوند عالم کے خاص بندوں کو حاصل ہوتاہے جو اپنے رابطے کو قرآن کے ساتھ محکم کرتےہیں اور روح قرآن کو اپنے زندگی میں آشکار کرتے ہوں جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت اور دوسری آیتوں کی ذیل میں فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے تین قسم کے ہیں ۔
۱۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے تمام امور اور اخراجات کے لئے قرآن مجید کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اور اسی کے وسیلے سے اپنے خودنمائی کرتے ہیں ۔
۲۔ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے کا مقصد اور ہدف قرآن کی حروف اور تجوید کو حفظ کرتے ہیں لیکن اس کی حدود اور قوانین کو تباہ و برباد کرتے ہیں خداوندعالم اس قسم کی گروہ کو زیاد نہ کریں ۔
۳۔ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اسی کو اپنے دل کی بیماریوں کے لئے شفا قرار دیتے ہیں ( قرآن کو اپنے معنوی بیماریوں کے لئے وسیلہ قرار دیتے ہیں ) اور اسی کے وسیلہ سے راتوں کو عبادت اور دنوں کو زوزہ رکھتے ہیں ۔
(فوالله لهولإ فى قرإ القرآن اعز من الكبريت الاحمر۔
خدا کی قسم اس طرح کی قرآن پڑھنے والوں کی یہ گروہ کبیرت احمر سے بھی زیادہ کمیاب ہے ۔(۱۷۲)
جب ہم قرآن مجید کی آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر قرآن مجید کی دو اہم ذمہ داریاں عاید ہوتی ہیں ۔
۱۔ قرآن مجید کی محتوی کو صحیح طریقے سے پہچاننا ۔
۲۔ اور مفاہیم قرآن پر عمل کرنا :
اس کی وضاحت : قرآن مجید میں خود لفظ قرآن تقریبا ۶۵ مرتبہ ذکر ہوئی ہے اور کتاب کی ضمن میں کئی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے ۔
ان آیات کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ جن میں قرآن کے بارے میں بات ہوئی ہے ۔ قرآن مجید کی شناخت اور اس کی محتوای کو درک کرنے اور پھر اسکے بعد قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا مراد ہے ۔ جیسا کہ سورہ فرقان آیت ۷۳ میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کا رابطہ جو قرآن مجید سے ہونا چاہیے وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں ہونی چاہیے بلکہ بصیرت والی آنکھوں اور سننے والی کانوں کے ساتھ ہونا چاہیے ۔ اس کو صحیح طریقے سے پہچان لیں اور اپنی روح اورروان کی اس کھیتی کو قرآن کی پانی سے سیراب کرنا چاہیے جیساکہ روایت میں آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا شاگر د ابوبصیر نے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی تو امام نے کہا۔
(مستبصرين ليسوا بشكاك)۔(۱۷۳)
یعنی اچھی شناخت اور بصیرت کے ساتھ قرآن کی طرف نگاہ کرے اور اس میں کبھی بھی شک و تردید نہ کرے ۔
قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پہچاننا اور اس کے مطالب پر یقین رکھنا خدا کے خاص بندوں کے خصوصیات میں سے ہیں ۔
قرآن مجید کے دوسری آیتوں میں بھی ان دو فریضوں کی طرف اشارہ ہوا ہے ۔ اس مطلب کے روشن ہونے کے لئے قرآن مجید کی چند آیتوں کو ذکر کریں گے ۔
پہلی ذمہ داری : (قرآن مجید کی شناخت ہے)کہ جس کے بارے میں خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔
( أَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) ۔
کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا (ان کے) دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔(۱۷۴)
اس آیت میں تاکید کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ قرآن مجید ہمیں تعقل اور تدبر اور اس شناخت حاصل کرنے کی تاکید کرتی ہے اور اسی کی طرف دعوت دیتی ہے ۔
کسی اور آیت میں ذکر ہورہا ہے کہ :
( وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِر ) ۔
اور بتحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟(۱۷۵)
یہ آیت اس بات کی حکایت کرتی ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو تمام انسانوں کے لئے بہت ہی آسان بنا کر بھیجا ہے تاکہ سب لوگ اس کو پہچان سکیں ۔ اس کو پہچاننے کا مقصد اور ہدف انسان کو متنبہ کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے ۔
کسی اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے۔
( وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ أَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ۔
اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو اور خاموش رہا کرو ، شاید تم پر رحم کیا جائے۔(۱۷۶)
اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو سکون اور آرامش کے ساتھ ان آیات پر دقت کرو کہ یہ قرآن کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے
اور وہ بہترین ادب جو قرآن کےمقابل ہونا چاہیے وہ اس کو بہترین طریقے سے سننا اور اپنی روح کو قرآن کے ظاہر ی اور باطنی عطر کی خوشبو سے معطر کرنے چاہیے ۔
اور دوسری ذمہ داری) : یعنی قرآن پر عمل کرنا ہے ) اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کے چند آیتوں کو ذکر کریں گے ۔
جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ :
( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيهْمْ ءَايَاتُهُ زَادَتهُمْ إِيمَانًا وَ عَلىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكلَّون ) ۔
مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔(۱۷۷)
جی ہاں ! مؤمن کے دل میں قرآن کے مقابل میں اس طرح سے خاشع اور ڈر ہو تا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سن کر ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور خدا کے ساتھ اس کا رابطہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے ۔
اسی طرح سے کسی اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے :
( يَأَيهَّا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فىِ الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين ) ۔
اے لوگو! تمہارے پروردگار کی طرف سے (یہ قرآن) تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے۔(۱۷۸)
کسی اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ :
( ...كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الحَمِيد ) ۔
یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، غالب آنے والے قابل ستائش اللہ کے راستے کی طرف۔(۱۷۹)
قرآن میں تدبر اور اس پر عمل امام علی علیہ السلام کی نظر میں :
قرآن مجید کی شناخت اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے بارے میں نہج البلاغہ میں بہت سارے مطالب بیان ہوئیں ہیں ان میں ہم یہاں پر چند مطالب کو نمونہ کے طور پر ذکر کریں گے ۔
((و تعلموا القرآن فانه إحسن الحديث, و تفقهوا فيه فانه ربيع القلوب و استشفوا بنوره فانه شفإ الصدور ))(۱۸۰)
قرآن کو یاد کرو کہ اس میں بہترین باتیں ہیں اور اس میں تفکر کرو جو دلوں کی بہار ہے اور اس کی نور سے شفاء حاصل کرو جو دلوں کی شفاء ہے ۔
(۔۔۔تَالِينَ لأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ يُرَتِّلُونَهَا تَرْتِيلًا - يُحَزِّنُونَ بِه أَنْفُسَهُمْ ويَسْتَثِيرُونَ بِه دَوَاءَ دَائِهِمْ - فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعاً - وتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقاً وظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ - وإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ - أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ - وظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ ))(۱۸۱)
پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں۔اپنے نفس کومحزون رکھتے ہیں اور اسی طرح سے گزرتے ہیں تو دل کے کانوں کو اس کی طرف یوں مصروف کردیتے ہیں جیسے جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ پکار مسلسل ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہو۔
اس طرح کی عبارتیں ہماری ان دو ذمہ داریوں ( یعنی قرآن مجید کی شناخت اور اس کے احکام پر عمل ) پر عمل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں مؤمنین کے دل پر اثر رکھتی ہے اور انسان کے فکر اور عمل کوتبدیل کرکے اس کی ترقی کا باعث بنتا ہے ۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ کتاب ہمارے لئے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی بلکہ خسارہ کا باعث بنے گا کہ جس کے بارے میں خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :
وَ لَا يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا
ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔(۱۸۲) کیونکہ شاعر فرماتا ہے ۔۔
باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست
در باغ لا له رويد و در شوره زار خس
قرآن کی اس روح سے وہ لوگ استفادہ کرسکتے ہیں جو پرہیز گار ہو ں اور جن کا وجود جہالت اور شرک و ظلم جیسی بری صفات سے پاک و پاکیزہ ہو ں اور اگر ایسا نہ ہو یہی صفات رزیلہ نہ ہی قرآن کے اس نور کو حاصل کرنے کا باعث نہیں بنتا بلکہ اس نور کے مقابل میں چمکادڑ کی طرح سے کھڑا ہوا گا ۔مثال کے طور پر جب کسی طاقت ور اور سالم کھانا ہو اور اسے کسی عالم دین اور مجاہد کو کھلایا جائے تو اس کی تعلیم و تربیت اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے کی قوت میں اضافہ ہوجائے گا اور اگر اسی کھانے کو کسی ظالم اور ستمگر کو کھلایا جائے تو اس کی ظلم اور ستم کرنے کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا تو فرق یہاں اس غذا اور کھانے میں نہیں بلکہ انسان کی مزاج اور فکر میں فرق ہے ۔
نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید صرف انسانوں کی شفا کے لئے ایک نسخہ ہی نہیں بلکہ اسی انسان کے تمام دردوں کے لئے ایک مؤثر دواء ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا درد ہو جیسا فردی اخلاقی اور اجتماعی و سیاسی درد وغیرہ ہو ۔
ایک دن امام علی علیہ السلام اپنے بعض اصحاب ( کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اچھے طریقے سے درک کئے ہوئے تھے اور شہید ہوئے تھے ) کہنے لگے کہاں ہیں میرے وہ بھائی جو سیدھے راستہ پر چلے اور حق کی راہ پر لگے رہے۔کہاں ہیں عمار ؟ کہاں ہیں ابن التیہان ؟۔کہاں ہیں ذوالشہادتین؟ کہاں ہیں ان کے جیسے ایمانی بھائی جنہوں نے موت کا عہدو پیمان باندھ لیا تھا (یہ کہہ کر آپ نے محاسن شریف پر ہاتھ رکھا اورتادیر گریہ فرماتے رہے اس کے بعد فرمایا :)
(۔۔۔۔۔۔إوه على اخوانى الذين تلوا القرآن فاحكموه ۔۔۔۔۔۔)(۱۸۲)
آہ ! میرے ان بھائیوں پر جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو اسے مستحکم کیا اور فرائض پر غورو فکر کیا تو انہیں قائم کیا ۔سنتوں کو زندہ کیا اور بدعتوں کو مردہ بنایا۔ انہیں جہاد کے لئے بلایا گیا تو لبیک کہی اور اپنے قائد پر اعتماد کیا تواس کا اتباع بھی کیا۔
امام علی علیہ السلام نے اس عبارت میں ان کی چھ خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے پہلی خصوصیت قرآن مجید کے ساتھ انکا مضبوط اور مستحکم رابطہ ہے ۔
اسی بنا پر امام کی نظر میں ایک بہترین اور ممتاز شاگرد وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کے ساتھ نیک اورگہرا رابطہ رکھتا ہو ۔
قرآن سے صحیح استفادہ کرنے والوں کے چند نمونے :
جب سے قرآن مجید نازل ہوئی ہے اس وقت سے ابھی تک بہت سارے نمونے موجود ہیں ۔
ایسے افراد کہ جنہوں نے بہت ہی عمیق اور گہرے طریقے سے قرآن مجید سے استفادہ کیا ہے اسی قرآن پر عمل کرکے اپنی فکر اور عمل میں تبدیلی لائے ہیں اور اسی قرآن کی نور سے اپنی زندگی کے تمام تاریکیوں اور ظلمتوں کو دور کئے ہوئے ہیں ۔ ہم یہاں پر انکے چند نمونے ذکر کریں گے ۔
۱۔ ابوذر غفاری کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام ایک رات کو خدا کی عبادت کرنے کو اٹھے اور ساری رات صرف اس آیت کی تلاوت اور اس کی تفکر میں گزارے :
( إِن تُعَذِّبهُمْ فَإِنهُّمْ عِبَادُكَ وَ إِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحَكِيم ) ۔(۱۸۳)
اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ ( یعنی نہ ہی آپ کا عذاب کرنا بے حکمتی کی نشانی ہے اور نہ ہی بخشش آپ کی ضعیفی کی نشانی ہے )
پیغمبر اسلام اس رات کو صبح ہونے تک اسی آیت کو تکرار کرتے رہے ۔(۱۸۴)
۲۔ ام عقیل جو کہ ایک دیہاتی اور مسلمان عورت تھی جو قرآن مجید کے ساتھ بہت ہی گہرا رابطہ رکھتی تھی ایک دن وہ اپنے گھر کے کام میں مشغول تھی انکو بتایا گیا کہ آپ کا ایک بیٹا اونٹوں کے زد میں آکر مرگیا ہے ۔ اس وقت انکے گھر میں دو مہمان تھے لہذا ام عقیل نے انکو کچھ نہیں بتایا تاکہ وہ ناراض نہ ہوجائیں اچھے طریقے سے انکی مہمان نوازی کی ان کو کھانا کھلایا ۔
کھانے کے بعد انکو پتہ چلا کہ انکا بیٹا مرگیا ہے انہوں نے ام عقیل کی حوصلہ اور صبر و تحمل دیکھ کر بہت متعجب ہوئیں جب مہمان چلے گئے تو کچھ لوگ ام عقیل کو تعزیت دینے آئے تو ام عقیل نے انکو کہا ( کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے قرآن کی آیات پڑھ کر تعزیت دے تاکہ میں سکون حاصل کروں ؟ ) تو ان میں سے ایک شخص قرآن کی ان دو آیتوں کے تلاوت کی :
( وَ بَشِّرِ الصَّابرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئكَ عَلَيهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) ۔
اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں: ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پران کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔(۱۸۵)
ام عقیل ان آیات کی تلاوت سن کر انکی اضطراب اور پریشانی ختم ہوئی اور سکون و آرامش حاصل کی اچانک کھڑی ہوئی اور وضو کرکے دو رکعت نماز پڑھی نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرکے خضوع و خشوع کے ساتھ خدا کی درگاہ میں عرض کرنے لگی خداوندا ! آپ کی حکم ہم تک پہنچ گئی آپ کی اس حکم پر میں صبر کرونگی اور اس صبر کے بدلے میں جو آپ نے اجر اور پاداش رکھا ہے وہ مجھے عطا کرے(۱۸۶)
جی ہاں ! اسی قرآن کے ساتھ انس اور رابطہ اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کی فکر اور روح میں تبدیلی آجاتی ہے جو اس جیسے ناگوار حادثے کے مقابل میں م انسان کو محکم اور صبور بناتا ہے ۔
۳۔ پیغمبر اسلام نے ایک دن ان آیات کی تلاوت کی :
( إِنَّ فىِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النهَّارِ لاَيَاتٍ لّأِوْلىِ الْأَلْبَاب ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔)
۔بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں (ان)صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں.جو اٹھتے بیٹھتے اوراپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، (اور کہتے ہیں:) ہمارے پروردگار ! یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا، تیری ذات(ہر عبث سے)پاک ہے، پس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔(۱۸۷)
افسوس ہو اس شخص پر جو ان آیات کی تلاوت تو کرتا اور انکو دھراتا رہتا ہے لیکن ان پر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔(۱۸۸)
۴۔ شہید سعید بن جبیر جو بہت بڑے مفسر تھے وہ ایک رات اس آیت کو پڑھتا ہے (کہ جس میں قیامت کے دن خدا کی آواز کے بارے میں بیان کرتی ہے )
( وَامْتَازُواْ الْيَوْمَ أَيهُّا الْمُجْرِمُون ) ۔
مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اے مجرمو! آج تم الگ ہو جاؤ۔(۱۸۹) رات کی ابتدا سے صبح ہونے تک اسی آیت کو پڑھتے اور اسی میں غور و فکر کرتے ہوئے روتے تھے ۔(۱۹۰)
۵۔ فضیل بن عیاض ۔ جو کہ دوسری صدی میں زندگی کررہے تھے جو ڈاکوؤں کے سردار شمار ہوتے تھے وہ ایک رات کسی کے ناموس پر برے نظر رکھ کر انکے گھر چلے گئے گھر کے دیوار پھلانک کر اندر داخل ہوئے تو اس گھر کے ہمسایگی میں کسی کی قرآن تلاوت کرنے کی آواز سنی اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت ہورہی تھی ۔
( أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تخْشَعَ قُلُوبهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ الحَقّ ) ِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے ؟(۱۹۱)
اس آیت کے سنتے ہی فضیل بہ متاثر ہوئے اور اچانک ان میں تبدیلی آگئی اسی جگہ پر اس نے توبہ کی اور خدا کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرکے روتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے (خدایا ! اب آپ کے سامنے خضوع اور خشوع کرنے کے وہ وقت آگیا ہے ) فضیل اسی وقت اپنے اس بری حرکت سے پیشمان ہوکر واپس ہوئے راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کاروان جارہا ہے اور اس کاروان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے جلدی گزر جائیں تاکہ فضیل اور ان کے ساتھی ہماری کاروان کی غارت نہ کریں ؟ تو فضیل نے انکو اپنا تعارف کرایا اور ان کو کہنے لگا کہ آپ لوگ امان میں ہیں ۔
جی ہاں ! فضیل نے اس طرح سے قرآن کی احترام کی اور قرآن کی اس آواز کو حقیقی معنی میں اس نے سنا اور اس کو اپنے دل میں قبول کیا اور خدا کے مقرب ترین بندوں میں سے قرار پایا اس کے بعد وہ مکہ کیا اور وہاں خانہ کعبہ کے اطراف میں زندگی کرنے لگا اور اپنی زندگی کو لوگوں کی تربیت میں گزارا اور یہاں تک کہ سن ۱۸۷ ہجری میں وفات پاگئے ۔(۱۹۲)
یہ عباد الرحمن کے کچھ صفات تھی کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اچھی طرح سے پہچان لیا تھا اور اس کے احکام پر عمل کیا تھا اور اپنی روح قرآن کی نور سے روشن کیا ہواتھا ۔
اور ان کے مقابل میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو گھونگے اور بہرے تھے وہ بھی قرآن کو پڑھتے تھے لیکن قرآن کی وہ نور ان کو حاصل ہونے کے بجائے ان کا دل کالا ہوتا جاتا تھا جیسا کہ خوارج تھے ۔
ایک رات کمیل بن زیاد امیرالمؤمنین کے ساتھ کوفہ کے کسی گلی سے گزر رہے تھے تو کمیل نے قرآن کی اس آیت ( سورہ زمر آت ۹ ) کی تلاوت سنی جو بہت ہی میٹھی آواز میں تلاوت ہورہی تھی کمیل ان کو نہیں جانتے تھے لیکن ان کی اس میٹھی آواز سے بہت ہی متاثر ہوئے اور اپنے دل میں کہنے لگے اے کاش کہ میں اس کے جسم کا ایک بال ہوتا تو ہر روز اس کے قرآن پڑھنے کی آواز کو سنتا !
امام علی علیہ السلام اگر چہ کمیل کی آوازکو نہیں سنا لیکن اس کو پتہ چلا کہ کمیل اس آواز کی وجہ سے دھوکے میں آیا ہے کہنے لگے اس قرآن پڑھنے والے کی اس عمگین آواز نے آپ کو تعجب میں ڈالا ہے ؟ آپ حیران اور تعجب نہ کرے وہ جہنمیوں میں سے ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد آپ کو بتادوں گا ۔
کچھ ہی مدت کے بعد جنگ نہروان واقع ہوا وہی قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کو آئے اور اسی جنگ میں ہی قتل ہوئے ۔ اور کمیل این زیاد بھی اسی جنگ میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے امام نے کمیل کو اس شخص کے جنازے پر لے گئے اور اپنی تلوار کو اس شخص کے جنازے پر رکھتے ہوئے کہنے لگے اے کمیل اس رات کو جو بھی ہی میٹھی آواز میں قرآن تلاوت کرتے تھے وہ یہی شخص تھے ۔ تو کمیل بہت پریشان ہوئے اور اپنی غلطی کی طرف متوجہ اور بہت ہی غمگین ہوئے اپنے کو امام کے پاؤ ں پر گرادیا اور بوسے لیتے ہوئے خدا سے بخشش طلب کرنے لگے ۔(۱۹۳)
یہی وہ خوارج تھے جو گھونگے اور بہرے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے ۔ لیکن عباد الرحمن ایسے لوگ تھے جو اپنی کان اور دل کھول کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے احکام پر عمل کرتے تھے ۔
نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ انس اور رابطہ رکھے اور اس کو اپنا معلم اور استا د جانے تاکہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری شفاعت کرے اور عباد الرحمن ( یعنی خدا کے مقرب بندوں )کے شامل ہوجائیں اور کل قیامت کے دن پیغمبر اسلام کی اس شکایت میں شامل نہ ہوجائے کہ جس میں وہ فرمائے گا ۔ (وَ قَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتخَّذُواْ هَاذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ) ۔(۱۹۴)
رسول کہیں گے: اے پروردگارا! میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا۔
اپنی آخری کلام کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی اس نورانی کلام سے اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ فرمایا : جانلو اور یاد رکھو کہ وہ ایسا شفعا ہے جس کی شفاعت مقبول ہے اور ایسا بولنے والا ے جس کی بات مصدقہ ہے۔جس کے لئے قرآن روز قیامت سفارش کردے اس کے حق میں شفاعت مقبول ہے اور ایسا بولنے والا ہے جس کی بات مصدقہ ہے۔جس کے لئے قرآن روز قیامت سفارش کردے اس کے حق میں شفاعت قبول ہے اور جس کے عیب کو وہ بیان کردے اس کا عیب تصدیق شدہ ہے۔
روز قیامت ایک منادی آوازدے گا کہ ہر کھییم کرنے والا اپنی کییہ اور اپنے عمل کے انجام مں مبتلا ہے لیکن جو اپنے دل مںے قرآن کا بجد بونے والے تھے وہ کامیاب ہیں
( فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِه وأَتْبَاعِه - واسْتَدِلُّوه عَلَى رَبِّكُمْ واسْتَنْصِحُوه عَلَى أَنْفُسِكُمْ - واتَّهِمُوا عَلَيْه آرَاءَكُمْ واسْتَغِشُّوا فِيه أَهْوَاءَكُمْ ) .(۱۹۵)
لہٰذا تم لوگ انہیں لوگوں اور قرآن کی پرعوی کرنے والوں میں شامل ہو جائو۔ اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بنائو اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصحتی کرو اور اپنے خیالات کو متہم قراردو اور اپنے خواہشات کو فریب خوردہ تصور کرو۔
منبع: ماهنامه پاسداراسلام ، شماره ۲۳۳ـ ارديبهشت ۱۳۸۰
تمت بالخیر :
والحمدلله رب العالمین
تاریخ : ۲۰/رجب المرجب سنه۱۴۳۹هجری
____________________
۱ سوره لقمان (۳۱) آيه ۱۲ و ۱۳.
۲ سوره لقمان, آيات ۱۳ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹. (اما آيه ۱۴ و ۱۵ ؛خداکا کلام ہے اور یہ مطلب لقمان کی حکمت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے خداوند عالم نے اپنے کلام کو ان کے کلام کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔
۳ مسعودى, مروج الذهب, ج۱, ص۴۶.
۴ المواعظ العدديه, ص۱۴۲.
۵ مروج الذهب, ج۱, ص;۴۶ تفسير برهان, ج۳, ص۲۷۳.
۶ محدث قمى, سفينه البحار, ج۲, ص۵۱۵, فخرالدين حر مكى, مجمع البحرين, واژه لقم; علامه مجلسى, بحار, ج۱۳, ص۴۲۵.
۷ اعلام قرآن خزائلى, ص۷۱۶.
۸ اس کے بارے میں نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں امام علی کی کلام میں سولہ مرتبہ ذکر ہوا ہے اور ان میں سے تیرہ مرتبہ امام حسن کو لکھے ہوئے نامہ ۳۱ نہج البلاغہ میں ذکر ہواہے ۔, اور اسی طرح سے بحار, ج۷۷, ص۲۳۸ تا ۲۴۱, اميرمومنان على(ع) کی وہ وصیت جو امام حسين(ع) کو کی ہے اس کی طرف رجوع کریں کہ جس میں , حضرت على(ع) نے امام حسين(ع) کو مخاطب قرار دیتے ہوئے تقریبا سترہ مرتبہ (يا بنى) کا جملہ استعمال کیا ہے , اصل میں یہ وصیت نامہ تحف العقول, ص۸۸ میں ذکر ہوا ہے ۔
۹ جوادى آملى, سيره پيامبران در قرآن, ص۲۳۴.
۱۰ شيخ حر عاملى, با تصحيح على مشكينى, المواعظ العدديه, ص۱۴۲.
۱۱ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن, ص۲۱۳ و ۲۱۴.
۱۲ نسإ (۴) آيه۷۷.
۱۳ آل عمران (۳) آيه۱۸۵.
۱۴ بقره (۲) آيه ۲۶۹.
۱۵ نهج البلاغه, خطبه۱۳۳.
۱۶ .نهج البلاغه, نامه ۳۱.
۱۷ نهج البلاغه,, حكمت ۸۰.
۱۸ نهج البلاغه, حكمت ۱۹۷.
۱۹ تحف العقول, ترجمه احمد جنتى عطايى, ص۶۱۸.
۲۰ علامه مجلسى, بحارالانوار, ج۱۳, ص۴۳۰.
۲۱ بحارالانوار, ص۴۲۴, مجمع البيان, ج۸, ص۳۱۵.
۲۲ بحارالانوار, ج۷۰, ص;۲۴۲ كنزالعمال, حديث ۵۲۷۱.
۲۳ علامه طبرسى, تفسير مجمع البيان, ج۸, ص۲۱۵.
۲۴ تفسير مجمع البيان , ص۳۱۶ و ۳۱۷.
۲۵ بحارالانوار, ج۲۲, ص۳۳۰.
۲۶ تفسير مجمع البيان, ج۸, ص۳۱۵ و ۳۱۶.
۲۷ لقمان (۳۱) آیه۱۳
۲۸ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۷۷، ص۱۰۷
۲۹ حج (۲۳) آیه ۳۱، اور آیه ۴۱ اور سوره عنكبوت میں بھی اس طرح اسی معنی میں آیا ہے
۳۰ كامل ابن اثیر، ج۲، ص۵۴۲
۳۱ تفسیر مجمع البیان، ج۱۰، ص۵۵۲
۳۲ .تفسیر مجمع البیان ، ص۵۵۱
۳۳ توبه (۹) آیه۲۸
۳۴ نساء (۴) آیه ۴۸
۳۵ بحار، ج۳، ص۱۴
۳۶ بحار، ج۳، ص۲۰۶ و ۲۰۷
۳۷ بحار ، ج۷۲، ص۹۲
۳۸ اصول كافی، ج۲، ص۳۹۸
۳۹۔ لقمان، آیه ۱۶.
۴۰ ۔ ابراهیم، آیه۴۱، ص، آیه۱۶، ۲۶، ۵۳، غافر، آیه۲۷.
۴۱۔ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۷۰، ص۷۳.
۴۲ ۔ غرر الحكم، میزان الحكمة، ج۲، ۴۰۵.
۴۳۔ بحار، ج۷۰، ص۷۰.
۴۴۔ بحار، ج۷۸، ص۲۷۹.
۴۵۔ محدث كلینی، اصول كافی، ج۱، ص۲۱۹.
۴۶۔ اصول کافی، ص۲۱۹ و ۲۲۰.
۴۷۔ بحار، ج۷۰، ص۷۰.
۴۸۔ همان، ج۷۷، ص۸۶.
۴۹۔ غرر الحكم، میزان الحكمة ، ج۲، ص۴۰۹.
۵۰۔ محدث قمی، سفینة البحار، ج۱، ص۴۸۸ (لفظ ذنب)
۵۱۔ سفینة البحار ، ص۲۵۰ (لفظ حسب)
۵۲۔ اصول كافی، ج۲، ص۲۸۷.
۵۳۔ اصول کافی ، ص۲۸۸ (به طور اقتباس)
۵۴۔ یعنی: خردمند لوگ وہ ہیں جو صلہ رحم انجام دیتے ہیں کہ جو خدا کا ایک حکم ہے اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور بر ے حساب سے بھی خائف رہتے ہیں۔. (رعد، آیه۲۱)
۵۵۔ تفسیر نورالثقلین، ج۲، ص۴۹۴.
۵۶۔ لقمان، آيه ۱۷.
۵۷۔ محدث كلينى، فروع كافى، ج ۳، ص ۲۶۶.
۵۸۔ كنزالعمال، حديث ۱۸۸۶۹.
۵۹۔ علامه مجلسى، بحارالانوار، ج ۸۲، ص ۲۲۷.
۶۰۔ فروع كافى، ج ۳، ص ۲۶۴.
۶۱۔ بحار، ج ۷۷، ص ۷۰.
۶۲۔ بحار ، ص ۱۲۷.
۶۳۔ بحار، ج ۸۲، ص ۳۱۰.
۶۴۔ ابراهيم، آيه ۳۷.
۶۵۔ ابراہیم ، آيه ۴۰.
۶۶۔ مريم، آيه ۵۵.
۶۷۔ مریم ، آيه ۳۱.
۶۸۔ بحار، ج ۸۲، ص ۲۱۹.
۶۹۔ سيره حلبى، ج ۳، ص ۲۴۳.
۷۰۔ عنكبوت، آيه ۴۵.
۷۱۔ طه، آيه ۱۴.
۷۲۔ منافقون، آيه ۹، طه آيه ۲۴.
۷۳۔ معارج آيات ۱۹ تا ۲۴.
۷۴۔ وسائل الشيعه، ج ۳، ص ۴.
۷۵۔ شرح غرر آقاجمال، ج ۲، ص ۱۶۶.
۷۶۔ سفينة البحار، ج ۲، ص ۱۳۱.
۷۷۔ مائده، آيه ۲۷.
۷۸۔ فروع كافى، ج ۳، ص ۲۶۹.
۷۹۔ علامه طبرسى، مجمع البيان، ج ۸، ص ۲۸۵.
۸۰۔ علامه حاج شيخ على يزدى، الزام الناصب، نشر حق بين قم، ج ۲، ص ۶۳ و ۶۴.
۸۱۔ سوره لقمان، ۱۷.
۸۲۔ تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۶۳.
۸۳۔ جیسے آیه ۳ سوره عصر، آیه مورد بحث (لقمان - ۱۷)، آیه ۱۹۹ و ۱۵۷ اعراف، آیه۱۶۳ و ۱۶۶ همین سوره، آیه ۱۰۴ و ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۱۱۴ آل عمران، آیه ۴۱ حج، آیه۷۱ توبه و ۱۱۱ و ۱۱۲ همین سوره.
۸۴۔ جیسا که سوره توبه آیت ۷۱ میں اس مطلب کی تصریح ہوئی ہیں
۸۵۔ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۳۹۲.
۸۶۔ نهج البلاغه، خطبه۱۹۲.
۸۷۔ همان، خطبه۱۵۶.
۸۸۔ همان، حكمت۳۷۴.
۸۹۔ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۳۹۵.
۹۰۔ یہ مسئلہ وہی ہے جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں که « وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة; اور اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں تم میں سے صرف ظلم کرنے والے ہی نہیں (سب) آئیں گے .» (انفال - ۲۵)
۹۱۔ بقره، ۱۹۵.
۹۲۔ تفسیر الدر المنثور، طبق نقل تفسیر المیزان، ج۷، ذیل آیه ۱۹۵ بقره.
۹۳- لقمان ۱۷.
۹۴- بقره ۱۵۷.
۹۵- المنجد, واژه صبر.
۹۶- نهج البلاغه, خطبه ۲۳۶.
۹۷- انفال ۶۵, بقره ۲۵۰.
۹۸- بقره ۲۴۹.
۹۹- اقتباس از گفتار امام صادق(ع); تفسیر نورالثقلین, ج۳, ص۴۴۷ و ۴۴۸.
۱۰۰- مضمون آیه ۸۳ سوره انبیإ, بحار ج۱۲, ص۳۶۸ و ۳۶۹.
۱۰۱- سوره ((ص)) ۴۴.
۱۰۲- بحار, ج۳۹, ص۵۶.
۱۰۳- اعلام الورى, ص۹۲.
۱۰۴- بحارالانوار, ج۲۲, ص۱۵۲.
۱۰۵- همان مدرک, ص۱۵۷ و ۱۵۶.
۱۰۶- نهج البلاغه خطبه۳.
۱۰۷- بقره ۴۵, تفسیر صافى, ذیل همین آیه.
۱۰۸- مقتل خوارزمى, ج۲, ص۲۸.
۱۰۹- مقتل الحسین مقرم, ص۳۴۵.
۱۱۰- مشکاه الانوار, ص۵۶.
۱۱۱- کامل ابن اثیر, ج۴, ص۳۳.
۱۱۲- مقتل الحسین مقرم, ص۴۶.
۱۱۳- محدث قمى, انوار البهیه, ص۵۰۰ ـ ۵۰۲.
۱۱۴- حجرات ۹.
۱۱۵- نهج البلاغه نامه ۵۳.
۱۱۶-سوره لقمان ، ۱۸.
۱۱۷-۔ المصباح المنیر، ص ۳۴۱; بحارالانوار ج۷۸، ص ۱۷۶.
۱۱۸۔ اصول كافی، ج ۲، ص ۱۲۴.
۱۱۹۔ بحارالانوار، ج ۱۸، ص ۳۸۲.
۱۲۰۔ محدث قمی، كحل البصر، ص ۱۰۰و۱۰۱.
۱۲۱۔ همان، واعیان الشیعه، چاپ ارشاد، ج ۱، ص ۳۳۳.
۱۲۲۔ معراج السعادة، ص ۳۰۰.
۱۲۳۔ محمدمحمدی اشتهاردی، میزان الحكمه، ج۶، ص۵۰۰ تا ۵۰۹.
۱۲۴۔ بحارالانوار، ج۱، ص۱۳۶.
۱۲۵۔ غررالحكم ترجمه محمدعلی انصاری، ج ۱، ص ۳۳۵.
۱۲۶۔ نهج البلاغه، خطبه ۱۹۲.
۱۲۷۔ نهج البلاغه
۱۲۸۔ تنبیه الخواطر (مجموعه ورام)، ص ۱۶۶.
۱۲۹۔ وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص ۹; سیره ابن هشام، ج ۳، ص ۷۱.
۱۳۰۔ اقتباس از المحجةالبیضاء، ج ۶، ص ۲۷۱.
۱۳۱۔ بحارالانوار، ج ۷۳، ص ۱۶۹.
۱۳۲۔ نهج البلاغه، حكمت ۲۲۸.
۱۳۳۔ اصول كافی، ج ۲، ص ۳۲۰.
۱۳۴۔ نهج البلاغه، حكمت ۳۴۷.
۱۳۵۔ كنزالعمال، حدیث ۲۹۳۶۴.
۱۳۶۔ اصول كافی، ج ۲، ص ۱۸۵.
۱۳۷۔ نهج البلاغه، حكمت ۴۰۶.
۱۳۸. لقمان - ۱۸.
۱۳۹. نهج البلاغه، حكمت ۲۶.
۱۴۰. مزمل - ۱۰.
۱۴۱. تفسیر مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۳۷۹.
۱۴۲. بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۱۷۱.
۱۴۳. بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۱۲۰.
۱۴۴. فرقان - ۶۳.
۱۴۵. اسراء - ۳۷.
۱۴۶. تفسیر نورالثقلین، ج ۴، ص ۲۰۷; ثواب الاعمال، ص ۲۴۵.
۱۴۷. بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۳۰۳; معانی الاخبار شیخ صدوق ، ص ۲۳۷.
۱۴۸. بحارالانوار، ج ۷۶، ص ۳۰۲.
۱۴۹. بحارالانوار ، ص ۳۰۵.
۱۵۰. اسراء ۳۷.
۱۵۱. لقمان - ۱۹; اصول كافی، ج ۲، ص ۳۶.
۱۵۲. محدث قمی، كحل البصر، ص ۱۶۳
۱۵۳ ۔ سوره لقمان ، آیه۱۹.
۱۵۴ ۔ بقره ، ۱۴۳.
۱۵۵ ۔تفسیر نورالثقلین، ج۱، ص۱۳۴.
۱۵۶۔ حجرات، آیات ۳- ۲ ; لقمان، ۱۹.
۱۵۷ ۔لقمان، ۱۹.
۱۵۸۔تفسیر مجمع البیان، ج۸، ص۳۲۰ (ذیل آیه)
۱۵۹۔ تفسیر مجمع البیان، ج۸، ص۳۲۰
۱۶۰۔حجرات، ۲، نظیر این مطلب در آیه ۶۳ سوره نور آمده است.
۱۶۱۔ المحجة البیضاء، ج۳، ص۴۵۰.
۱۶۲۔ بحارالانوار، ج۲، ۶۲.
۱۶۳ ۔ نهج البلاغه، خطبه۱۲۴، و نامه۱۶.
۱۶۴ ۔غرر الحكم، ترجمه محمد علی انصاری، ج۱، ص۹۷.
۱۶۵ ۔ نساء، ۱۴۸.
۱۶۶ ۔ اقتباس از تفسیر مجمع البیان ، ج۹، ص۱۳۰.
۱۶۷۔ وسائل الشیعه، ج۴، ص۶۱۹.
۱۶۸ ۔ صحیفه نور، ج۱۸، ص۲۱.
۱۶۹ ۔ صحیفه نور، ، ج۱۶، ص۲۴۳.
۱۷۰۔ سوره فرقان (۲۵) آيه۷۳
۱۷۱۔ شيخ كلينى, اصول كافى, ج۲, ص۶۲۷.
۱۷۲۔شيخ كلينى , روضه الكافى, ص۱۷۸, حديث۱۹۹.
۱۷۳۔سوره محمد (۴۷) آيه۲۴.
۱۷۴۔وره قمر (۵۴) آيه۱۷.
۱۷۵۔سوره اعراف (۷) آيه۲۰۴.
۱۷۶۔ انفال, (۸) آيه۲.
۱۷۷۔ يونس(۱۰) آيه۵۷.
۱۷۸۔ ابراهيم (۱۴) آيه۱.
۱۷۹۔ سيد رضى, نهج البلاغه, خطبه۱۱۰.
۱۸۰۔ نهج البلاغه, خطبه۱۹۳.
۱۸۱۔ اسرإ (۱۷) آيه۸۲.
۱۸۲۔ نهج البلاغه, خطبه۱۸۲.
۱۸۳۔ مائده(۵) آيه۱۱۸.
۱۸۴۔ المحجه البيضإ, ج۲, ص۲۳۷.
۱۸۵۔ بقره (۲) آيه۱۵۶ و ۱۵۷.
۱۸۶۔ محدث قمى , سفينه البحار, ج۲, ص۷ (واژه صبر)
۱۸۷ ۔ آل عمران (۳) آيه ۱۹۰ تا ۱۹۴.
۱۸۸ ۔ علامه طبرسى, مجمع البيان, ج۲, ص۵۵۴ (ذيل آيات مذكور)
۱۸۹ ۔ يس (۳۶) آيه ۵۹.
۱۹۰ ۔ عالمحجه البيضإ, ج۲, ص۲۳۷.
۱۹۱ ۔ حديد (۵۷) آيه۱۶.
۱۹۲ ۔ سفينه البحار, ج۲, ص۳۶۹ (واژه فضيل) ; وفيات الاعيان, ج;۲ ص۲۱۵.
۱۹۳ ۔ سفينه البحار, ج۲, ص۴۹۷ (واژه كميل).
۱۹۴ ۔ فرقان (۲۵) آيه۳۰.
۱۹۵ ۔ نهج البلاغه, خطبه۱۷۶.
فہرست
حضرت لقمان کون ہے ؟ ۴
حکمت کا معنی ا اور ان کے ابعاد : ۶
حکمت عملی کے آثار : ۸
حضرت لقمان کا حکیم ہونا اور اس کا راز : ۹
نتیجہ اور جمع بندی : ۱۰
لقمان کی دس حکمتیں قرآن میں: ۱۱
پہلی حکمت : توحید اور خدا شناسی : ۱۲
توحید کے اقسام : ۱۲
توحید ناب پیغمبراسلام اور امیر المؤمنین کے کلام میں : ۱۴
شرک کا سب سے بڑا ظلم ہونا : ۱۵
دوسری حکمت : حساب وکتاب : ۱۶
حساب و کتاب قرآن کی دوسری آیتوں میں : ۱۷
حساب و کتاب روایات کی نظر میں : ۱۸
حساب و کتاب کے بارے میں تجزیہ و تحلیل : ۱۹
تیسری حکمت : نماز قائم کرنا : ۲۳
۱۔ نماز کی اہمیت : ۲۳
۲۔ نماز کے آثار اور اسکا فلسفہ : ۲۵
۳۔ نماز کے قبول ہونے اور اس کے اسرار میں تامل : ۲۷
نماز کے قبول ہونے میں حضور قلب اور خشوع کا کردار : ۲۸
حضور قلب کے بغیر پڑھی جانے والی نماز جماعت سے امام زمانہ کی بے اعتنائی : ۲۹
چوتھی اور پانچویں حکمت : ۳۰
امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر : ۳۰
قرآن کی آیات اور روایات کی طرف ایک نگاہ : ۳۲
نظارت عمومی اور آزادی کا مسئلہ : ۳۳
قرآن کے دو سؤالوں کے جواب : ۳۴
حضرت لقمان اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مسئلہ : ۳۶
چھٹی حکمت : صبر و استقامت : ۳۷
تجزیہ وتحلیل : ۳۸
صبر کے اقسام : ۳۸
صبر اور استقامت کے مختلف انواع اور اقسام ہیں : ۳۸
حضرت ایوب صبر کا قرآنی نمونہ : ۴۰
پیغمبر اکرم ص اور ائمہ معصومین ع کا صبر : ۴۱
ایک سؤال کا جواب : ۴۵
ساتویں حکمت تواضع اور فروتنی : ۴۵
تواضع کا معنی اور اس کے اقسام : ۴۶
تواضع کے اقسام : ۴۷
تواضع اور ذلت پذیری کے درمیان فرق : ۴۹
تواضع کی علامت اور اس کے درجات : ۵۲
آٹھویں اور نویں حکمت : ۵۲
بد رفتاری اور غرور: ۵۲
۱۔غرور اور تکبر سے دوسروں سے رخ پھیرنا : ۵۳
۲۔ غرور اور تکبر کے ساتھ چلنا : ۵۵
دسویں حکمت : آواز میں اعتدال : ۵۶
آواز میں اعتدال کا معنی : ۵۷
آواز پر کنٹرول کرنا قرآن کی نظر میں : ۵۹
آواز میں اعتدال بزرگوں کے کلام میں : ۶۰
استثناءات : ۶۱
امام خمینی کی ایک نصیحت : ۶۲
گیا رویں حکمت : قرآن مجید سے بہرہ مند ہونا: ۶۳
۳۔ پیغمبر اسلام نے ایک دن ان آیات کی تلاوت کی : ۶۹