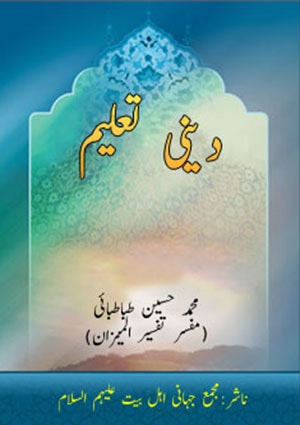یہ کتاب برقی شکل میں نشرہوئی ہے اور شبکہ الامامین الحسنین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں تنظیم ہوئی ہے
دینی تعلیم
محمد حسین طباطبائی
(مفسر تفسیر المیزان)
مرتّبہ: سید مہدی آیت اللّہی
مترجم: سید قلبی حسین رضوی
ناشر: مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام
پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا:
( اِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیْراً )
(سورۂ احزاب : آیت ٣٣)
اے اہلبیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس اور گندگی کو دور رکھے اور تمہیں اسی طرح پاک رکھے جوپاک وپاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔
شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم کی بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیۂ مبارکہ پنجتن اصحاب کساء کی شان میں نازل ہوئی ہے اور '' اہل بیت'' سے مراد وہی حضرات ہیں اور وہ : محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم ، علی ، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام ہیں۔نمونہ کے طور پر ان کتابوں کی طرف رجوع کریں:مسند احمد بن حنبل(وفات ٢٤١ ھ ):ج١، ص٣٣١،ج٤،ص١٠٧، ج٦،ص٢٩٢ و ٣٠٤؛ صحیح مسلم(وفات٢٦١ ھ) : ج٧،ص١٣٠؛ سنن ترمذی(وفات ٢٧٩ ھ ): ج٥،ص٣٦١ و...؛ الذریة الطاہرة النبویة دولابی(وفات: ٣١٠ ھ ): ص١٠٨؛ السنن الکبریٰ نسائی(وفات ٣٠٣ ھ ): ج٥ ،ص١٠٨ و ١١٣؛ المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری(وفات: ٤٠٥ ھ ):ج٢، ص ٤١٦، ج٣،ص١٣٣و ١٤٧ و ١١٣؛ البرہان زرکشی(وفات ٧٩٤ ھ ) ص١٩٧؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری ابن حجر عسقلانی(وفات ٨٥٢ ھ):ج٧،ص١٠٤؛ اصول الکافی کلینی(وفات ٣٢٨ ھ ): ج١،ص ٢٨٧ ؛ الامامة و التبصرة ابن بابویہ (وفات ٣٢٩ ھ): ص٤٧، ح٢٩؛ دعائم الاسلام مغربی(وفات ٣٦٣ ھ):ص٣٥ و ٣٧؛ الخصال شیخ صدوق(وفات ٣٨١ ھ):ص٤٠٣ و ٥٥٠؛ الامالی شیخ طوسی(وفات ٤٦٠ ھ):ح ٤٣٨،٤٨٢ و ٧٨٣ نیز مندرجہ ذیل کتابوں میں اس آیت کی تفسیر کی طر ف مراجعہ کریں: جامع البیان طبری(وفات ٣١٠ ھ)؛ احکام القرآن جصاص(وفات ٣٧٠ ھ )؛ اسباب النزول واحدی(وفات ٤٦٨ ھ)؛ زاد المسیر ابن جوزی(وفات٥٩٧ ھ)؛ الجامع لاحکام القرآن قرطبی(وفات ٦٧١ ھ)؛ تفسیر ابن کثیر (وفات ٧٧٤ ھ)؛ تفسیر ثعالبی (وفات٨٢٥ ھ)؛ الدر المنثور سیوطی(وفات ٩١١ ھ)؛ فتح القدیر شوکانی(وفات ١٢٥٠ ھ)؛ تفسیر عیاشی(وفات ٣٢٠ ھ)؛ تفسیر قمی(وفات:٣٢٩ ھ)؛ تفسیر فرات کوفی (وفات ٣٥٢ ھ) آیۂ اولوا الامر کے ذیل میں ؛ مجمع البیان طبرسی(وفات ٥٦٠ ھ) اور بہت سی دوسری کتابیں۔
حرف اول
جب آفتاب عالم تاب افق پرنمودار ہوتاہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ ونکھار پیدا کرلیتی ہیں تاریکیاں کا فور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کاسورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔
اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کردیا، آپ کے تمام الہی پیغامات، ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ٢٣ برس کے مختصر عر صے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماندپڑگئیں ، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کرلیا۔
اگر چہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی یہ گرانبہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام او ر ان کے پیروؤں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اورناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کاشکار ہوکراپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمۂ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنھوں نے بیرونی افکارو نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگیں تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیاہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن او رمکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف اٹھی او رگڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکر و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسلام سے اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، یہ زمانہ عملی اور فکری مقابلے کازمانہ ہے اورجو مکتب بھی تبلیغ او رنشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیاتک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔
(عالمی اہل بیت کو نسل) مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروؤں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایاہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر اندازسے اپنا فریضہ ادا کرے، تا کہ موجود دنیا ئے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف وشفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہوسکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوتصلىاللهعليهوآلهوسلم و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق وانسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خون خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔
ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین ومصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنی خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، علامہ طباطبائی کی گرانقدر کتاب ''دینی تعلیم'' کو مولانا سید قلبی حسین رضوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیاہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیںاور مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں او رمعاونیں کا بھی صمیم قلب سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنی جہاد رضائے مولی کا باعث قرار پائے۔
والسلام مع الاکرام
مدیر امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام
دینی معلومات
لفظ ''دین'' کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ایک ہے ۔عام طور پر دیندار اسے کہتے ہیں جو کائنات کے لئے ایک خداکا قائل ہو اور اس کی خوشنودی کے لئے خاص قسم کے اعمال بجا لاتاہو۔
ممکن ہے ہر معاشرے اور ملت میں ، قانون کے مطابق معاشرہ کے ہر فرد کے لئے فرائض معین ہوئے ہوں ،اور ان پر لوگ عمل کرتے ہوں، تو یہ تصور کیا جائے کہ وہاں پھر''دین'' کی ضرورت نہیں ہے ،لیکن اسلام کے احکا م اور ضوابط پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اس معنی کے خلاف ثابت ہو تا ہے ،کیونکہ دین اسلام صرف خدا کی عبادت و ستائش تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس میں انسا ن کے تمام انفرادی و اجتماعی مسائل کے لئے جامع قواعد و ضوابط اور مخصوص قوانین وضع کئے گئے ہیں اور بشریت کی وسیع دنیا کے بارے میں حیرت انگیز صورت میں تحقیق کی گئی ہے۔اور انسان کی ہر انفرادی و اجتماعی حرکت و سکون کے لئے مناسب قوانین وضع کئے گئے ہیں ۔ایسے دین کو تکلفاتی اور رسمی دین سے تشبیہ یا نسبت نہیں دی جاسکتی ہے ۔
خدائے متعال نے قرآن مجید میں دین اسلام کو مذکورہ بیان شدہ کیفیت میں تو صیف فرمائی ہے اور اس کے علاوہ یہودیت و نصرانیت کوکہ جن کی آسمانی کتا بیں توریت و انجیل ہیں اور ان میں اجتماعی احکام وقواعدوضوابط ہیں ۔اسی صورت میں بیان فر مایا ہے، چنانچہ فر ماتا ہے:
( وکیف یُحکّمو نکَ وعندهم التّورٰة فیها حکم اللّه انّا انزلنا التورٰة فیها هدیَ وّ نور یحکم بها النبیّون الّذین اسلموا للّذین هادوا والرّبّنیون والاحبار.وقفینا علی أثارهم بعیسیٰ ابن مریم وء اتینه الانجیل فیه هدی وّنور و مصدقاً لما بین یدیه من التورٰة و هدی وّ موعظة للمتّقین و لیحکم اهل الانجیل بما انزل اللّه فیه و انزلنا الیک الکتٰب بالحق مصد قاً لما بین یدیه من الکتب ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل اللّه ) (مائدہ٤٣۔٤٨)
'' اوریہ کس طرح آپ سے فیصلہ کرائیں گے جب کہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں حکم خدا بھی ہے... بیشک ہم نے توریت کو نازل کیاجس میں ہدایت اور نور ہے اور اس کے ذریعہ اطاعت گزار انبیاء یہودیوں کے لئے فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ والے علماء یہود... اور ہم نے انھیں انبیاء کے نقش قدم پر عیسی بن مریم کو چلا یا۔...اور ہم نے انھیں انجیل دیدی جس میں ہدایت اور نور تھا اور وہ اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کر نے والی اور ہدایت تھی اور صاحبان تقوی کے لئے سامان نصیحت تھی اہل انجیل کو چاہئے کہ خدانے جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں ۔...اور اے پیغمبر!ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی توریت اور انجیل کی مصداق اور محافظ ہے لہذا آپ ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں ''
توریت اور انجیل۔ جو اس وقت یہودو نصاری کے ہاتھ میں ہیں۔ بھی اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں،کیونکہ توریت میں بہت سے قوانین اور تعزیراتی ضوابط موجود ہیں اورظاہری طور پرانجیل بھی توریت کی شریعت کی تائید وتصدیق کرتی ہے۔
نتیجہ
مذکورہ بیان سے واضح ہوتا ہے کہ''قرآن مجید کی اصطلاح میں دین '' کہ وہی زندگی کی روش ہے،اور اس سے انسان پہلو تہی نہیںکرسکتا ۔دین اور ایک اجتماعی قانون کے درمیان جو فرق پایا جا تا ہے وہ یہ ہے کہ دین خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور اجتماعی قانون لو گوں کے افکار کی پیداوار ہو تا ہے ۔دوسرے الفاظ میں دین لوگوں کی اجتماعی زندگی اور خدائے متعال کی پر ستش اور اس کی فرمانبرداری کے درمیان ایک ربط پیداکرتا ہے ،لیکن اجتماعی قانون میں اس رابط کی کوئی اہمیت نہیں ہو تی ہے۔
خداکے قانون سے رابط کا اچھا اثر
''دین''انسان کی اجتماعی زندگی اور خدائے متعال کی پر ستش کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے نتیجہ میں انسان کے تمام انفرادی و اجتماعی اعمال کو خدائی ذمہ داری قرار دے کر اس کو خدا کے لئے جواب دہ جانتاہے ۔چو نکہ خدائے متعال اپنی لامحدود قدرت اوربے پناہ علم کی بناپر ہر جہت سے انسان پر احاطہ رکھتا ہے اور اس کے دل ودماغ کے تمام اسرارو افکارسے مکمل طور پر آگاہ ہے اور اس سے کوئی چیز پو شیدہ نہیں ہے، اسی لئے دین نے بشری قانون کی طرح امور کے نظم و نسق کو باقی رکھنے کے لئے محافظ اور نگہبان مقرر کئے ہیں اور مخالفت وسرکشی کر نے والوں کی سزاکے لئے قوانین وضع کر کے بشری قانون کی نسبت ایک اور امتیاز حاصل کیاہے اور وہ یہ کہ :دین،انسان کی حیرت اور ہوشیار ی کی باگ ڈور کو ایک باطنی و ابدی محافظ کے ہاتھ میں دیتا ہے۔کیو ںکہ دین سے نہ غفلت ہوتی ہے اور نہ خطا اور اس کی جزا اور سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا ۔خدائے متعال فرماتا ہے:
( وهو معکم این ما کنتم ) (حدید٤)
''اور تم جہاں بھی ہو ،وہ تمہارے ساتھ ہے''
( واللّه بمایعملون محیط ) (انفال٤٧)
''اور اللہ ان کے کام کااحاطہ کئے ہوئے ہے''
( وانکلا لما لیوفینهم ربّک اعمالهم ) ( ہود١١١)
''اور یقینا تمہارا پروردگار سب کے اعمال کاپوراپورا بدلہ دے گا۔''
اگرہم قانون کے دائرہ میں زندگی کر نے والے کے حالات کادین کے دائرہ میں زندگی کرنے والے کے حالات سے مواز نہ کریں گے تو دین کی برتری واضح اور روشن ہو جائے گی ۔کیونکہ جس معاشرے کے تمام افراد متدین ہوں اور اپنے دینی فرائض کو انجام دیں، ہر حالت میں خدائے متعال کو اپنے کاموں میں حاضر وناظر جانیں ،تو وہ ایک دوسرے سے بد ظن نہیںہوتے ہیں ۔
اس لئے ایسے ماحول میں زندگی کر نے والے عوام الناس،ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہتے ہیں اور نہایت ہی آرام و مسرت کی زندگی گزارتے ہیں اور انھیں کوابدی سعادت نصیب ہوتی ہے۔لیکن جس ماحول میں صرف بشری قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پر،جب تک لوگ اپنے کام پرکسی کو نگراں محسوس کرتے ہیں اس وقت تک وہ کام میں کوتاہی نہیں کرتے ،ورنہ ممکن ہیکہ وہ ہر طرح کی کوتاہی کے مر تکب ہو ں ۔
جی ہاں ،اخلاق کے پابند معاشرے میں ،جو دلی سکون پایا جاتا ہے،وہ اسی دین کا مرہون منت ہوتاہے نہ کہ قانون کا ۔
دوسرے الفاظ میں ،دین،ایسے عملی و اخلاقی عقائد وضوابط کا مجموعہ ہے ،جسے انبیاء خدا کی طرف سے انسان کی راہنمائی اورہدایت کے لئے لائے ہیں ۔ان عقائد کو جاننا اور ان احکام پر عمل کرنا انسان کے لئے دونوں جہاںمیں سعادت کا سبب بنتا ہے ۔
اگر ہم دیندار ہوں اور خداو پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے احکام کی اطاعت کریں تو اس ناپائدار دنیا میں بھی خوش قسمت اوردوسری دنیا کی ابدی اور لامحدود زندگی میں بھی سعادت مند ہوں گے۔
وضاحت:ہم جانتے ہیں کہ سعادت مند وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی اشتباہ اور گمراہی میں نہ گزاری ہو ،اس کے اخلاق پسندیدہ ہوں اور نیک کام انجام دیتا ہو۔خدا کا دین ہمیں اسی سعادت اور خوش بختی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ:
اولاً:جن صحیح عقائد کو ہم نے اپنی عقل وشعور سے درک کیا ہے ،انھیں مقدس و محترم جانیں ۔
ثانیا ً: ہم پسندیدہ اخلاق کے مالک ہوںاور حتی الامکان اچھے اور شائستہ کام انجام دیں، اس بناء پر دین تین حصوں میں تقسیم ہو تا ہے :
١۔عقائد
٢۔اخلاق
٣۔عمل
١۔عقائد
اگر ہم اپنی عقل وشعور کی طرف رجوع کریں تودیکھیں گے کہ اس عظیم اور وسیع کائنات کی ہستی،اس حیرت انگیز نظا م کے ساتھ ، خودبخود وجود میں آنا ۔ اور اس کا اول سے آخر تک کانظم و نسق،کسی منتظم کے بغیر ہونا ممکن نہیں ہے۔یقینا کوئی خالق ہے،جس نے اپنے لامحدودعلم وقدرت سے اس عظیم کائنات کوپیدا کیا ہے اور تمام امور میں پائے جانے والے ثابت وناقابل تغیر قوانین کے ذریعہ کائنات کے نظام کوانتہائی عدل وانصاف کے ساتھ چلایاہے ۔کوئی بھی چیز عبث خلق نہیں کی گئی ہے اور کوئی بھی مخلوق خدائی قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہے ۔
لہذا یہ باور نہیں کیا جاسکتا ہے کہ،ایسا مہر بان خدا،جو اپنی مخلوق پر اس قدر مہربان ہے،انسانی معاشرے کوانسان جو زیادہ ترنفسانی خواہشات کا اسیر بن کر،گمراہی اور بدبختی سے دوچار ہو تا ہے ۔کی عقل کے رحم وکرم پر چھوڑدے ۔
اس بناپر،معصوم انبیاء کے ذریعہ بشرکے لئے ایسے قواعد وضوابط کابھیجنا ضروری ہے تاکہ ان پر عمل کر کے انسان سعادت و خوش بختی تک پہنچ جائے ۔
چونکہ پروردگار کے احکام کی اطاعت کی جزا اس دنیا کی زندگی میں مکمل طور پر ظاہر نہیں ہو سکتی ،لہذا ایک دددوسرے جہان کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں پرلوگوں کا حساب و کتاب ہو، اگر کسی نے نیک کام انجام دیا ہے تو اسے اس کی جزا ملے اور اگر کسی سے کوئی برا کام سرزد ہوا ہو تو اسے اس کی سزا ملے ۔
دین ،لوگوں کو ان اعتقادات اوردیگر تمام حقیقی عقائد ۔جن کو ہم بعد میں تفیصل سے بیان کریں گے ۔کی طرف تشویق کر تاہے اور انھیں جہل وبے خبری سے پرہیز کرنے کی تاکید کرتا ہے۔
٢۔اخلاق
دین،کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ زندگی میں پسندیدہ صفات اختیار کریں اور اپنے آپ کو قابل ستائش اورنیک خصلتوں سے آراستہ کریں ۔ہم فرض شناس،خیر خواہ، انسان دوست، مہر بان ،خوش اخلاق اور انصاف پسند بن کر حق کا دفاع کریں ۔اپنے حدوداور حقوق سے آگے نہ بڑھیںاور لوگوں کے مال ،عزت ،آ برو او رجان پر تجاوز نہ کریں ۔علم ودانش حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کے ایثار اور فدا کار ی سے دریغ نہ کریں، خلاصہ یہ کہ اپنی زندگی کے تمام امور میں عدل وانصاف اور اعتدال کو اپنا شیوہ قرار دیں ۔
٣۔عمل
دین ،ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کام انجاں دیں جن میں ہماری اپنی اور اپنے معاشرے کی خیر وصلاح ہو ۔اورفساد وتباہی مچانے والے کاموں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ دین ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ خدائے متعال کی عبادت وپرستش کے عنوان سے کچھ اعمال جیسے نماز، روزہ وغیرہ ۔جو بندگی اور فرمانبرداری کی نشانی ہے۔کو بجا لائیں۔
یہ وہ قواعد وضوابط اور احکام ہیں ،جنھیں دین لے کر آیا ہے اور ہمیں ان کی طرف دعوت دیتا ہے ۔چنانچہ واضح ہے کہ ان ضوابط اور احکام میں سے کچھ کا تعلق عقیدہ سے کچھ کا اخلاق سے اور کچھ کا عمل سے ہے ، جیسا کہ بیان ہوچکا ہے کہ ان کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا ہی انسان کے لئے سعادت و خوش بختی ہے ،کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے لئے سعادت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ حقیقت شناس ہو اور پسندیدہ اخلاق و اعمال پر مبنی زندگی بسر کرے۔
دین کافطری ہون
انسان اپنی فطرت اورخداداد طینت کے لحاظ سے دین کاخواہاں ہے ،کیو نکہ انسان اپنی زندگی کے سفر میں سعادت حاصل کرنے کے لئے مسلسل ہاتھ پائوں مارتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ان اسباب ووسائل سے استفادہ کرتاہے جواس کے مقاصد میں مؤثر ہیں ،بیشک وہ ہمیشہ ایسے سبب کی تلاش میں ہوتاہے جو مؤثر ہو اور وہ ناکام نہ ہو ۔دوسری طرف ہم عالم طبیعت میں کوئی ایسا سبب نہیں پاتے ہیں جس کا اثر دائمی ہو اور وہ کبھی رکاوٹوں کے مقا بلہ میں نا کام نہ ہو۔
انسان فطرت کے مطابق اپنی سعادت کے لئے ایک ایسا سبب چاہتا ہے جو ناکام نہ ہو اور ایک ایسا پشت پناہ بھی چایتا ہے کہ جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے تاکہ اپنی زندگی کو اس سے منسلک کر دے اور باطنی آرام وسکون حاصل کر سکے ،حقیقت میں دین بھی یہی چاہتاہے۔ کیونکہ صرف خدائے متعال ہے جو اپنے ارادہ میں ہر گز مغلوب و ناکام نہیں ہو تا ہے اور عذر و قصور اس کے لئے قابل تصور نہیں ہے، اور خدائے متعال سے مربوط زندگی کے طریقوں کا نام ہی ''دین اسلام ہے''۔
اس بنا ء پریہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کی فطری خواہش ،دین کے تین بنیادی اصو لوں توحید،نبوت اور معاد کو ثابت کرنے کے بہترین دلائل میں سے ایک ہے،کیونکہ فطری ادراک دوستی اور دشمنی کے مفہوم کو مخلوط نہیں کر تاہے اورتشنگی کو سیراب نہیں سمجھتا ہے۔
یہ صحیح ہے کہ بعض اوقات انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ پرندے کے مانند اس کے بھی پر ہوتے تا کہ پر واز کر تا یاایک ستارہ کے مانند آسمان پر ہو تااور طلوع وغروب کرتا ،لیکن ان کی حقیقت محض ایک تصور ہے یہ اور بات ہے کہ انسان دل کی گہرائیوں سے اپنی سعادت، مطلق راحت وسکون یا انسانی تقاضوں کی بناپر وہ سنجیدہ زندگی کی خاطر ایک پناہ گاہ کی تلاش میں ہے اور ہر گز اس سے منہ نہیں موڑ تا ہے۔
اگر کائنات میں ناقابل مغلوب سبب (خدا)نہ ہو تا تو انسان اپنی بے آلائش طبیعت سے اس کی فکر میں نہیں پڑ تا اور اگر مطلق وآرام (جوآخرت کا سکون وآرام ہے)کا وجود نہ ہوتاتو انسان فطری طورپر اس کو پانے کی فکر ہی نہ کرتا اور اگر دینی طریقہ(جو نبوت کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے ) حق نہ ہو تا ،تو انسان کے باطن میں اس کی تصویر بھی نہ ہو تی ۔
انسان مختلف قسم کی جسمانی و روحانی ،مادی ومعنوی ضرورتیں رکھتا ہے کہ جس کو اجتماعی زندگی کے ذریعہ دور کیا جا سکتا ہے اور انسانی معاشر ے کا ہر فرد عام و سائل کو استعمال کر کے،کسی رکاوٹ کے بغیر ،اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو آرام وآسائش میں گزارتا ہے اور دوسری دنیا کے لئے زادراہ حاصل کرتا ہے،پس انسانی معاشرے میں ایک ایسا قانون نافذ ہونا چاہئے جو خالق کائنات کے ارادہ کے مطابق اور فطرت و خلقت سے ہم آہنگ ہو۔ اس قانون کے مطابق ہر ایک کو اپنی جگہ پر قرار پانا چاہئے اور معاشرے میں اپنی قدرو منزلت کے مطابق اس سے استفادہ کرے اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنے سے پرہیز کرے آخر کارمعاشرے کے تمام لوگ خدائے متعال کے ارادہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور سب آپس میں بھائی بھائی اور حق وانصاف کے مقا بلہ میں برا بر ہو جائیں ۔
دین کے فائدے
مذکورہ بیانات سے ثابت ہوگیا کہ فرداور معاشرے کی اصلاح میں دین ایک گہرا اثر رکھتاہے بلکہ یہ سعادت ونیک بختی کا منفرد وسیلہ ہے ۔جو معاشرہ دین کا پابند نہ ہو وہ حقیقت پسندی اورجدت فکرسے محروم ہے ،ایسے معاشرے کے لوگ اپنی قیمتی زندگی کو گمراہی اور ظاہر داری میں گزارتے ہیں ،عقل کو پامال کر کے حیوانوں کی طرح تنگ نظری اور بیوقوفی میں زندگی گزارتے ہیں اور اخلاقی انحطاط اورکردار کی پستی کا شکار ہوتے ہیں اور اس طرح انسانی خصو صیات و امتیازات سے محروم ہوجاتے ہیں ۔
اس قسم کا معاشرہ ،علاوہ اس کے کہ ابدی اور انتہائی کمال وسعادت تک نہیں پہنچتا ہے،اس دنیا کی ،اپنی مختصر اورناپائدار زندگی میں بھی انحرافات اور گمراہیوں کے منحوس نتائج سے دوچار ہو تا ہے اور کسی نہ کسی وقت اپنی غفلت کے برے نتائج کو بھگتے گا اور واضح طورپر اسے معلوم ہو گا کہ سعادت کا راستہ دین ہی تھا اورسر انجام اپنے کردارسے پشیمان ہو گا۔ خدائے متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے :
( قد افلح من زکّها٭وقد خاب من دسّها ) (شمس٩۔١٠)
''بیشک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنالیا.اوروہ نامرادرہا جس نے اسے آلودہ کرلیا ''
البتہ جاننا چاہئے کہ جس چیز سے انسان کی سعادت اورفردو معاشرے کی خوش بختی وابستہ ہے ،وہ دینی ضوابط پر عمل کرنا ہے ۔صرف نام سے کام نہیں چلتا،کیونکہ جس چیز کی اہمیت و قیمت ہے وہ خود حقیقت ہے نہ حقیقت کا دعویٰ۔جوشخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کا باطن تاریک ہے اوروہ اخلاقی طور پر گراہوا اور بد کردار ہے،اس کے باوجود سعادت کے فرشتہ کا منتظر ہے،تو اسکی مثال اس بیماری کی جیسی ہے جو طبیب کے نسخہ کو جیب میں رکھ کر صحت یابی کی تو قع رکھتا ہے، یقینا ایسا انسان اس فکر کے ساتھ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے ۔خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے:
( انّ الذّین ء امنوا والّذین هادوا والنّصٰارٰی والصّٰائبین من اٰمن باللّه و الیوم الاخر و عمل صٰالحاً فلهم اجرهم عند ربّهم ) (بقرہ٦٢)
''جو لوگ بظاہر ایمان لائے یا یہودی ،نصاریٰ اور صابیئن(۱) ہیں ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اس کے لئے پروردگار کے یہاں اجر وثواب ہے ...''
ممکن ہے اس آیہ شریفہ کے مضمون سے یہ تصور کیا جائے کہ جولوگ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دئے ہوں ،اگر چہ انہوں نے تمام پیغمبروں یا بعض پیغمبروںکو قبول بھی نہ کیا ہو ،تب بھی وہ نجات پائیں گے ۔لیکن جاننا چاہئے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر ١٥٠ اور١٥١ میں پروردگار عالم ان لوگوں کو کافر جانتاہے جو تمام پیغمبروں یا بعض پیغمبروں پر ایمان نہ رکھتے ہوں ۔
تاریخ ادیان کا ایک خلاصہ
ادیان کے وجود میں آنے کے بارے میں اجمالی تحقیق ، مطمئن ترین راہ ۔جس پر دینی نقطہ نگاہ سے اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید ہی کا بیان ہے، کیونکہ یہ ہر قسم کی خطا،اشتباہ، تعصب اور خود غرضی سے منزہ و پاک ہے۔
( انّ الدّین عند اللّه الا سلام ) (آل عمران ١٩)
''دین خدا ، دین اسلام ہی ہے''
جوانسان کی پیدائش کے پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ تھا ،جیسا کہ قرآن مجید میں تاکید ہوئی ہے کہ،بشرکی موجودہ نسل کی ابتداء میں دو شخص ایک مرد اور ایک عورت تھے ۔مرد کا نام''آدم '' اور اس کی بیوی کا نام ''حوا''تھا ۔ حضرت آدم پیغمبر تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی ۔حضرت آدم کا دین بہت سادہ اور چند کلیات پر مشتمل تھا ،جیسے ،لوگوں کو خداکو یادکر نا چاہئے اورآپس میں ، خاص کراپنے والدین کے ساتھ احسان ونیکی کرنا چاہئے،فساد ،قتل اور برے کاموں سے پر ہیز کرناچاہے۔
آدم اور اُن کی بیوی کے بعد ،ان کی اولاد انتہائی سادگی اوراتفاق واتحاد کے ساتھ زندگی گزارتی تھی ،چونکہ دن بدن ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا جارہا تھا ،لہذا رفتہ رفتہ انہوں نے اجتماعی زندگی اختیار کرلی۔
اس طرح وہ بتدریج زندگی کے طورطریقوں کو سیکھتے تھے اور تہذیب و تمدن سے قریب ہوتے تھے ۔چونکہ آبادی بڑھتی گئی اس لئے وہ مختلف قبیلوںمیں تقسیم ہو گئے اورہر قبیلہ میں کوئی نہ کوئی بزر گ پیدا ہوتاتھااورقبیلہ کے لوگ اس کااحترام کرتے تھے،یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مجسمہ بنا کر اس کا احترام و ستائش کرتے تھے ۔اسی زمانہ سے لوگوں میں بت پرستی کا رواج پیدا ہوا ،چنانچہ ائمہ علیہم السلام کی روایتوں میں آیا ہے کہ بت پرستی اسی طرح شروع ہوئی ہے اور بت پرستی کی تاریخ بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے۔رفتہ رفتہ طاقتور افراد کمزوروں اور ضعیفوں پر زیادتی کرنے لگے اوراسطرح لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتاچلاگیا ۔ اوریہ اتفاقی طور پر پیداہونے والے اختلافات ان کی زندگی میں گوناگوں کشمکش اور لڑائی جھگڑے پیداکرنے کا سبب بنے۔
یہ اختلافات ۔جو انسان کو سعادت کی راہ سے منحرف کر کے بدبختی اور ہلا کت کی طرف لے جاتے تھے ۔اس امر کاسبب بنے کہ خدائے مہر بان نے کچھ انبیاء کو منتخب کرکے آسمانی کتاب کے ساتھ بھیجا تا کہ انسان کے اختلافات کو دور کریں ،چنانچہ خدائے متعال اپنے کلام میں فر ماتا ہے:
( کان النّاس امّة واحدة فبعث اللّه النبیّن مبشّرین و منذرین وانزل معهم الکتٰب بالحق لیحکم بین النّاس فیما اختلفوا فیه ) (بقرہ٢١٣)
''(فطری اعتبار سے)سارے انسان ایک قوم تھے ۔پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ بر حق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں''
دین اسلام اور اس کی آسمانی کتاب
دین اسلام ، ایک عالمی اور ابدی دین ہے۔اس میں اعتقادی ،اخلاقی اور عملی ضوابط کے امورکا ایک سلسلہ ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان دنیا وآخرت کی سعادت وخوش بختی حاصل کرتا ہے ۔
دین اسلام کے قواعد وضوابط ۔جو خالق کائنات کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ۔ایسے ہیں کہ اگر انسانی معاشرے کا کوئی فرد یاانسانی معاشروں میں سے کوئی معاشرہ ان پر عمل کرے تو اس کے لئے زندگی کے بہترین شرائط اور ترقی یافتہ ترین انسانی کمال حاصل ہو سکتے ہیں ۔
دین اسلام،کے نیک آثارہر فرداورہر معاشرے کے لئے مساوی ہیں اور چھوٹے بڑے،عالم و جاہل،مردوعورت،سفید فام و سیاہ فام اور مشرقی ومغربی، بلا استثناء اس مقدس دین کے فوائداور خوبیوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے ،اوراپنی ضرورتوںکو اچھی طرح پورا کرسکتاہے ۔
دین اسلام نے اپنے معارف و ضوابط کوفطرت کی بنیاد پراستوا رکیا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو مدنظر رکھا ہے ،اور ان کوپورا کرتا ہے اور انسان کی فطرت اور ساخت بھی مختلف افراد،نسلوں اور متعدد زمانوں میں یکسان ہے ،اس لحاظ سے واضح ہے کہ انسانی معاشرہ مشرق سے لے کرمغرب تک ایک ہی قسم کا خاندان ہے اور وہ انسانی ساخت کے اصول وارکان میں آپس میں شریک ہیں اور مختلف افراداور نسلوں کی ضرورتیںبھی مشابہ ہیں اور بشر کی آنے والے نسلیں بھی اسی خاندان کی اولاد ہیں اور یقیناانہی کے وارث ہیںاوراُن کی ضرورتیںانہی کی ضرورتیں جیسی ہوںگی۔
نتیجہ کے طور پر،اسلام ایک ایسا دین ہے جوانسان کی واقعی اور فطری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اورسبھی کے لئے کافی اور ابدی ہے۔
اسی لئے خدائے متعال نے اسلام کودین فطرت کا نام دیا ہے اور لوگوں کو انسانی فطرت کو زندہ رکھنے کی دعوت دیتا ہے اور دین کے بزرگوں نے فرمایا ہے:
''اسلام ایک آسان دین ہے جو انسان پر میں سختی نہیں کرتا ۔''
خدائے متعال نے دین اسلام کوفطرت کی بنیاد پر بنایا ہے لہذا اس کی کلیات سبھی کے لئے قابل فہم ودرک ہیں ،لیکن پھر بھی اس نے اس کے اصلی معارف وضوابط کی بنیادوں کو پیغمبراکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب ''قرآن مجید'' میں فرمایاہے۔ دین مقدس اسلام،آخری آسمانی دین ہے اس لئے یہ مکمل ترین دین ہے ۔اس دین کے آنے کے بعدگذشتہ دین منسوخ ہوگئے ،کیونکہ کامل دین کے ہوتے ہوئے ناقص دین کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ دین اسلام ہمارے پیغمبرحضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ بشر کے لئے بھیجا گیا ہے۔نجات اورسعادت کا یہ دروازہ دنیا کے لوگوں کے لئے اس وقت کھولاگیا جب انسانی معاشر ہ اپنی فکری ناتوانی کے دور سے گزر رہاتھااور انسانیت کے کمال کو حاصل کرنے کے لئے مکمل طور پرآمادہ ہوچکا تھا اور الٰہی معارف اور اس کے بلند مطالب کو حاصل کرنے کی لیاقت پیدا کر چکا تھا۔اسی لئے اسلام حقیقت پسندانسان کے لئے قابل فہم حقائق ومعارف اورپسندیدہ اخلاق لیکر آیا۔جو انسان کا امتیاز ہے،اور انسان کی زندگی کے انفرادی و اجتماعی کاموں کو منظم کرنے والے ضوابط، لائے اور ان پر عمل کرنیکی نصیحت کی ۔
ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کے معارف کلی طورپر تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں : ''اصول دین ،اخلاق اورفروع فقہی '' نیز واضح رہے کہ اصول دین ،یعنی دین کی اصلی بنیادیں ،تین ہیںاور اگرانسان میں ان میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے:
١۔توحید،یعنی خداکی وحدانیت پر عقیدہ رکھنا۔
٢۔انبیاء کی نبوت پر عقیدہ رکھنا،جن کے آخری پیغمبرحضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ٣۔معاد پر ایمان ،یعنی یہ عقیدہ ہوکہ،خدائے متعال مرنے کے بعدسبھی کوزندہ کرے گاان کے اعمال کاحساب لے گا ۔نیک لوگوں کو نیکی کی جزااور برے لوگوں کوسزادے گا۔مذکورہ تین اصولوں میں مزیددواصول اضافہ کئے جاتے ہیںجو مذہب شیعہ کے مخصوص عقائدہیں کہ جن کے نہ پائے جانے پر انسان شیعہ مذہب سے خارج ہوتا ہے ،اگر چہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور وہ دو یہ ہیں :
١۔امامت
٢۔عدل
____________________
١۔جنہوں نے مجوسی مذہب سے یہودی مذہب کی طرف تمائل پیدا کر کے مجو سیت اور یہو دیت سے ایک در میانی دین ایجاد کیا،انھیں صابئین کہتے ہیں ۔
دین ،قرآن مجید کی نظر میں
( ان الدّین عند اللّه الاسلام ومااختلف الّذین اوتوا الکتاب الاّٰ من بعد ما جآ ء هم العلم بغیاً بینهم و من یکفر بایٰات اللّه فا ن اللّه سریع الحساب ) (آل عمران١٩)
''دین،اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا صرف آپس کی شرارتوں کی بناپر اور جو بھی آیات الہی کا انکار کرے گاتوخدابہت جلد حساب کرنے والا ہے۔''
انبیاء نے جس دین کی طرف لوگوں کودعوت دی ہے وہ خداپرستی اور اس کے احکام کے مقابلہ میں تسلیم ہونا ہے۔ادیان کے علمائ،باوجود اس کے کہ حق کی راہ کو باطل سے تشخیص دیتے تھے ،تعصب ودشمنی کی وجہ سے حق سے منحرف ہوکرہر ایک نے ایک الگ راستہ اختیار کیا ،اور نتیجہ کے طور پر دنیا میں مختلف ادیان وجود میں آگئے ۔حقیقت میں لوگوں کے اس گروہ نے آیات الہی کی نسبت کفر اختیار کیا ہے اور خدائے متعال ان کے اعمال کی جلد ہی سزا دے گا:
( ومن یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخٰاسرین ) (آل عمران ٨٥)
''اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا۔''
( یا ایّها الذین ء آمنوا ادخلوا فی السّلم کافّةً ولا تتّبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدوّمّبین ) (بقرہ٢٠٨)
''ایمان والو !تم سب مکمل طریقہ سے اسلام میں داخل ہو جائو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو وہ تمہاراکھلا ہوا دشمن ہے۔''
( واوفوا بعهد اللّه اذاعٰاهد تّم ولا تنقضوا الایمٰان بعد توکیدهٰا وقد جعلتم اللّه علیکم کفیلا ان اللّه یعلم ماتفعلون )
(نحل ٩١)
'' اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کوان کے استحکام کے بعد ہر گز مت توڑو جب کہ تم اللہ کو کفیل اور نگران بنا چکے ہو کہ یقینا اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔''
اس آیة شریفہ کا مقصد یہ ہے کہ، مسلمان جو بھی عہد و پیمان خدا یا بندوں سے کریں ،انھیں اس پر عمل کرنا چاہئے اور اسے نہ توڑیں ۔
( ادع الی سبیل ربّک بالحکمةوالموعظة الحسنة وجٰادلهم بالّتی هی احسن ان ربّک هو اعلم بمن ضلّ عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین ) (نحل ١٢٥)
''آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دیں اور ان سے اس طریقہ سے بحث کریں جو بہتر ین طریقہ ہے کہ آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بہک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں ۔''
مقصد یہ ہے کہ،دین کی تر قی کیلئے مسلمان کوہر ایک کے ساتھ اس کی عقل وفہم کے مطابق اس کے لئے مفید ہو ،اور اگردلیل و برہان اور نصیحت سے کسی کی راہنمائی نہ کر سکا ،تو جد ل (جو کہ مطلب کو ثابت کر نے کا ایک طریقہ ہے )کے ذریعہ اس کو حق کی طرف دعوت دے۔
( واذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلّکم ترحمون )
(اعراف٢٠٤)
''اور جب قرآن کی تلا وت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو شاید تم پررحمت نازل ہوجائے ۔''
( یا ایّها الّذینء امنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول و اولی الامرمنکم فان تنٰازعتم فی شی ئٍ فرُدّوه الی اللّه و الرّسول ان کنتم تومنون باللّه و الیوم الاٰخر ذلک خیر واحسن تاویلا ) ( نسائ٥٩)
''ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمھیںمیں سے ہیں ،پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہوجائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو اگرتم اللہ اورروزآخرت پر ایمان رکھنے والے ہو ،یہی تمہارے حق میں خیر اورانجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔''
مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشروں میں ، اختلاف دور کرنے کا وسیلہ ،قرآن مجید اور پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے،اور ان دودلیلوں کے ذریعہ ہر اختلاف کو حل کرنا چاہئے اوراگر کسی مسلمان نے عقل سے اختلاف دور کیا،تووہ بھی اس لئے ہے کہ قرآن مجید نے عقل کے حکم کو قبول کیا ہے ۔
( فبما رحمةٍ من اللّه لنت لهم ولو کنت فظّاً غلیظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه ان اللّه یحبّ المتوکّلین )
(آل عمران ١٥٩)
''پیغمبر!یہ اللہ کی مہر بانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے نرم ہو ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے ،لہذتم انھیں معاف کردو ۔ان کے لئے استغفار کرو اور ان سے جنگ کے امورمیں مشورہ کرو اور جب ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتاہے''
کیونکہ نیک برتائو ،خیر خواہی اور امور میں مشورہ کرنا ،انس ومحبت کا وسیلہ ہے اورمعاشرہ کے افراد کو اپنے سر پرست سے محبت کرنی چاہئے تاکہ وہ ان کے دلوں میں نفوذ کرسکے۔ خدائے متعال مسلمانوں کے سر پرست کو خوش اخلاقی اور مشورہ کا حکم دیتا ہے،اوریہ حکم اس لئے ہے کہ ممکن ہے لوگ اپنی سوچ میں غلطی کریں لہذا حکم دیتا ہے کہ مشورت کے بعد اپنے فیصلہ میں آزاد ہو اور اس لئے کہ خدا کے ارادہ سے کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے ،اپنے امور میں خداپر توکل کر کے اپنے کام اسی کے سپرد کرے ۔
معاشرے میں دین کا کردار
دین،ایک بہترین روش ہے،جس سے انسانی معاشرہ کو منظم کیا جا سکتا ہے اوریہ دوسری تمام روشوںسے زیادہ لوگوں کو اجتماعی قوانین کی رعایت کرنے پرابھارتاہے، اور جب ہم ان اسباب وعلل کا مطالعہ کرتے ہیں جو ماضی میں انسانی معاشرے کے وجود میں آنے کاسبب بنے ہیں تو یہ حقیقت مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے ۔
انسان زندگی میں اپنی سعادت و کامرانی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چاہتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے ۔البتہ یہ سعادت زندگی کے تمام وسائل کی فراہمی کے بغیرممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف انسان اپنے خداداد فہم و شعور سے درک کرتاہے کہ وہ ان تمام ضرورتوںکوتنِ تنہاپورا نہیں کرسکتا کہ جن سے وہ اپنی من پسند سعادت کو حاصل کرسکے۔ واضح ہے کہ زندگی کی تمام ضرورتوں کوپورا کرنا ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے ، خواہ وہ کتناہی طا قتور کیوں نہ ہو ۔اس لحاظ سے انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے ہی جیسے لوگوںسے مدد لینے پر مجبور ہے تا کہ اپنے ضروری اورحیات آفرین وسائل کو حاصل کر سکے،اس صورت میں کہ ہرایک ان وسا یل میں سے کسی ایک کو حاصل کرنے کی ذمہ داری کوقبول کرتاہے اوراسے فراہم کرتا ہے ،اس کے بعدتمام افراد اپنی فعالیتوں کے ماحصل کو ایک جگہ جمع کر تے ہیںاوران میں سے ہر شخص اپنی فعالیت اور حیثیت کے مطابق حصہ لیتا ہے اور اس سے اپنی زندگی کو چلاتا ہے ۔
اس طرح ،انسان اپنی سعادت کو پورا کرنے کے لئے اپنے ہم نوع انسانوں کا تعاون کرتاہے اوراُن سے تعاون لیتاہے ،یعنی مختصر یہ کہ تمام لوگ ایک دوسرے کے لئے کام کرتے ہیں اور اس کا م کے نتیجہ کوجمع کرتے ہیں اورمعاشرے کاہر فرد اپنی حیثیت اور فعالیت کے مطابق اپنا حصہ لے لیتا ہے ۔
معاشرے کو قوانین کی ضرورت
لوگوں کی محنت و مشقت کا ماحصل چونکہ ایک ہوتا ہے اورسب اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے معاشرے کوکچھ قوانین کی ضرورت ہے تاکہ ان کی رعایت سے بغاوت اور لاقانونیت کو روکاجا سکے ۔واضح ہے کہ اگر معاشرے کانظام چلانے کے لئے کچھ ضوابط وقوانین نہ ہوں تو افراتفری پھیلتی ہے اور انسانی معاشرہ اپنی زندگی کوایک دن بھی جاری نہیں رکھ سکتا ۔
البتہ یہ قوانین معاشرے اقوام ، لوگوںکی فکری سطح اور حکومتی دفاتر کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں ۔ بہر حال کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں پایا جاسکتا جوایسے قوانین سے بے نیاز ہو کہ جن کا اکثر افراداحترام کرتے ہوں۔تاریخ بشریت میں ہرگز ایسا کوئی معاشرہ نہیں پایاگیا جس میں کسی قسم کے مشترک آداب ورسو م و قوانین وضوابط نہیں تھے۔
قوانین کے مقابلہ میں انسان کاآزاد ہونا
چونکہ انسان اپنے تمام کام اپنے اختیار سے انجام دیتاہے ،اس لئے وہ ایک طرح کی آزادی محسوس کرتا ہے اور وہ اس آزادی کو''مطلق ''یعنی بدون قیدوشرط تصور کر کے ،مکمل آزادی چاہتا ہے اور ہر قسم کی پابندی سے بھاگتاہے۔اسی وجہ سے وہ ہرطرح کی رکاوٹ ومحرو میت سے رنجیدہ ہوتا ہے اور مختصر یہ کہ وہ ہر دھمکی سے اپنے اندردباؤ اور خاص ناکامی کا احساس کرتا ہے ،اس لحاظ سے اجتماعی قوانین چاہے کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں ،چونکہ وہ ایک حد تک انسان کوپابند کرتے ہیں ،لہذا وہ اسکی حریت پسندی کے خلاف ہوں گے۔
دوسری طرف انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر معاشر اور اس کے نظم و نسق کے تحفظ کے لئے وضع کئے گئے قوانین کے مقابلہ میں اپنی آزادی سے کسی حد تک دستبردار نہ ہو جائے تو افراتفری پھیل کر اس کی پوری آزادی و آسائش ختم ہو جائے گی ،چنانچہ اگر وہ کسی کے ہاتھ سے ایک لقمہ لے گا تو دوسرے لوگ اس کے ہاتھ سے پورا کھانا چھین لیں گے اوراگروہ کسی پر ظلم کرے گا تودوسرے بھی اس پر ظلم کریں گے۔
اس لحاظ سے اسے چاہیے کہ اپنی آزادی کے ایک حصہ کو محفوظ رکھے ،اور اس کے دوسرے حصہ سے صرف نظر کرے تو اس طرح وہ اجتماعی قوانین وضوابط کا احترام کرے گا۔
قوانین کی ترقی میں کمزوریاں
مذکورہ مطالب کے پیش نظر،انسان کی آزاد پسند ذہنیت اور اجتماعی ضوابط کے درمیان ایک قسم کا ٹکرائواورتضاد موجود ہے ۔یعنی قوانین ایک قسم کی زنجیر ہے جو اس کے پائوں میں پڑی ہے اور وہ ہمیشہ اس زنجیر کو توڑنا چاہتاہے تاکہ اس پھندے سے رہائی پائے اور یہ اجتماعی قوانین کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے جو اس کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتاہے ۔
اسی لئے ہمیشہ قوانین اور عملی فرائض کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کے لئے کچھ اور قواعدوضوابط بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جاسکے ،اس سلسلہ میں کبھی لوگوں کو قوانین کی اطاعت کرنے کی تشویق کے لئے انعا مات کی امید دلائی جاتی ہے ۔البتہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ مسئلہ (یعنی سزا کاخوف اور جزا کاشوق) قوانین کے نفاذ میں کسی حدتک مدد کرتا ہے ۔لیکن یہ خلاف ورزی کے راستہ کو سو فیصد بند کر کے قانون کے اثر و تسلط کو مکمل طور پر تحفظ نہیں بخش سکتا، کیونکہ تعزیراتی قوانیں بھی دوسرے کارآمد قوانین کے محتاج ہونے کی وجہ سے خلاف ورزی سے محفوظ نہیں ہیں اور انسان کی آزادپسند طبیعت کی طرف سے انہیںہمیشہ خطرہ لاحق رہتاہے ۔چونکہ جو لوگ مکمل طور پر نفوذ اورطاقت رکھتے ہیں وہ کسی خوف وہراس کے بغیر کھلم کھلا مخالفت کرسکتے ہیں یانفوذ کے ذریعہ ،عدلیہ اور انتظامی محکموں کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں ۔
جو لوگ نفوذ وطاقت نہیں رکھتے ہیں ،وہ بھی معاشرے کی ہدایت کرنے والوں کی غفلت یا کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مخفیانہ طور پر خلاف ورزی کر سکتے ہیں ،یا رشوت اور سفارش کے ذریعہ یا معاشرے کے بااثر اشخاص کے ساتھ دوستی اوررشتہ داری کے ذریعہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں اور اس طرح معاشرے کے نظم کو عام حالات سے خارج کرکے ناکارہ بنا سکتے ہیں ۔
اس بات کابہترین ثبوت یہ ہے کہ ہم مختلف انسانی معاشروں میں اس قسم کی مخالفتوں اور قانونشکنی کے ہزاروں نمونے روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں ۔
قانون میں خامی کااصلی سر چشمہ
اب دیکھنا چاہئے کہ اس خطرہ کا سرچشمہ کہاں ہے اورانسان کی سرکش اورآزادی پسند طبیعت کو کیسے قابو میں کیا جائے اور نتیجہ میں قانون کی مخالفت کو روکا جائے؟
اس خطرہ کا سرچشمہ۔ جو معاشرے میں فسادبرپاکرنے کا سب سے بڑا سبب ہے یہاں تک کہ قوانین بھی اسے روک نہیں سکتے ۔یہ ہے کہ عام اجتماعی طریقے ،جو قوانین کو وجود میں لاتے ہیں ، کہ جن کا تعلق افراد کے مادی مراحل سے ہے ،وہ ان کی معنویات اور باطنی فطرتوں کی کوئی اعتنا نہیں کرتے اور ان کامقصد صرف ہما ھنگی اورنظم و نسق کا تحفظ اور لوگوں کے اعمال کے درمیان توازن بر قرار رکھنا ہوتا ہے تاکہ اختلاف اور کشمکش کی نوبت نہ آئے ۔
اجتماعی قانون کا تقاضایہ ہے کہ قانون کی شقوں پر عمل کیا جائے اور معاشرے کے امور کو کنٹرول کیا جائے ۔اس قانون کا انسان کے داخلی صفات اور باطنی جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے ،جو ان اعمال کے محرک اور قوانین کے داخلی دشمن ہیں ۔
اس کے باوجود اگر انسان کی آزادی پسند فطرت اور دوسرے سیکڑوں جبلتوں (جیسے خودخواہی اورشہوت پرستی جومفاسد کے اصلی سبب ہیں )کی طرف توجہ نہ کی جائے تو معاشرے میں افراتفری اورلاقانونیت رائج ہوجائے گی اوراختلافات کادامن روز بروز پھیلتا جائے گا ،کیونکہ تمام قوانین کو ہمیشہ قوی باغیوں اور سر کشوں کے حملہ کاخطرہ لاحق ہوتا ہے جوانہی جبلتوں سے پیدا ہوتے ہیں اور کوئی قانون بُرے کو کنٹرول کر کے اختلافات کو نہیں روک سکتا ہے۔
تمام قوانین پردین کی ترجیح
قانون کے تحفظ کے لئے آخری طریقہ ،تعزیراتی قوانین وضع کرنا اور محا فظ مقرر کرنا ہے لیکن جیسا کہ بیان کیاگیا ، تعزیراتی قوانین اور محافظ انسان کی سر کشی اور دیگر جبلتون کو روک نہیں سکتے تاکہ اجتماعی قوانین پر عمل ہو سکے۔
دین کے پاس مذکورہ وسائل کے علاوہ مزید دوطاقتور وسیلے بھی موجود ہیں ،جن سے وہ ہر مخالف طاقت کو مغلوب کر کے اسے تہس نہس کر سکتا ہے :
١۔ہر دین دار فرددین کی راہنمائی سے اس حقیقت تک یہنچتاہے کہ اس کی زندگی اس ناپائدار اور گزرجانے والی دنیا کی چند روزہ زندگی تک محدود نہیں ہے ،بلکہ اس کے سامنے ایک ابدی اورلامحدود زندگی ہے ،جو موت سے نابود نہیں ہوتی ۔اس کی ابدی سعادت اورآسائش صرف اس میں ہے کہ وہ پرودردگار عالم کی طرف سے اس کے پیغمبروں کے توسط سے بھیجے گئے قوانین کی پیروی کرے ،کیونکہ وہ جانتاہے کہ دینی قوانین ، ایک ایسے دانا اور بینا پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ،جو انسان کے باطن وظاہر سے آگاہ ہے اوراپنی مخلوق سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتا ۔ایک ایسادن آنے والا ہے جس دن وہ اسی انسان کو اپنے پاس بلائے گا،اس کے پنہاں اور آشکار اعمال کا حساب و کتاب لے گا اور نیک اعمال کی پاداش اور برے اعمال کی سزادے گا ۔
٢۔ہر دیندا رشخص اپنے دینی عقائد کے مطابق جانتا ہے کہ جب دینی حکم کو بجا لاتا ہے تووہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے ،اس کے باوجودوہ بندگی کی رسم کے مطابق کسی اجر پاداش کامستحق نہیں ہے ، لیکن پروردگار کے فضل وکرم سے اس کو نیک پاداش ملے گی ،اس لحاظ سے ہر اطاعت کو انجام دے کر اس نے حقیقت میں اپنے اختیارسے ایک معاملہ اور ایک لین دین کیاہے ۔چونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی آزادی کے ایک حصہ سے دست بردار ہواہے اور اس کے مقابلہ میں اپنے پروردگارکی خوشنودی و مہر بانی حا صل کی ہے ،اس لئے اسے اپنی نیکیوں کی پاداش ملے گی۔
دیندار شخض، دینی قوانین وضوابط کی پیروی کر کے اپنی پوری خوشی سے معاملہ کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور جو کچھ اپنے اختیار سے دیتا ہے اس کے کئی گنا نفع کماتا ہے ۔وہ ایک چیز کو بیچ کراس کے بدلے میں اس سے بہتر مال خرید لیتا ہے ۔لیکن جو شخص دین کا پابند نہیں ہو تا ،چونکہ وہ ضوابط کی رعایت اور قانون کی پیروی کو اپنے لئے ایک نقصان تصور کرتاہے اور اس کی آزادی پسند طبیعت اس کی آزادی کے ایک حصہ کو کھو دینے سے ناراض ہوتی ہے ۔وہ اس موقع کی تلاش میں ہو تا ہے کہ اس زنجیرکو توڑ کراپنی آزادی حاصل کرے ۔
نتیجہ
مذکورہ بیانات سے معلوم ہوتاہے کہ معاشرے کی زندگی کے تحفظ کے لئے دین کا اثر غیر دینی طریقوںکی نسبت زیادہ قوی اور عمیق ہے ۔
دوسروں کی کوشش
دنیا کے پسماندہ ممالک ،جو قرن اخیر میں ترقی وپیش رفت کی فکر میں ہیں ،اگر چہ انہوں نے اجتماعی حکو مت کو قبول کیا ہے ،لیکن قانون کی ضعیف شقوں کی طرف توجہ نہیں کی ہے اور دین کی طاقت سے استفادہ نہیں کیا ہے ،اس لئے ان کی دنیا تاریک ہوئی ہے اوران کی زندگی کا ماحول جنگل کے قانون میں تبدیل ہواہے ۔
ان کے مقابلہ میں ،دنیا کی ترقی یافتہ اور ہوشیار قوموں نے ،قوانین کی کمزوری سے آگاہ ہو کر ،قانون کو حتمی ناکامی سے نجات دلانے کے لئے ،کچھ کوششیں کر کے ایک دوسرا راستہ اختیار کیاہے۔
ان قوموں نے تعلیم و تربیت کے نظام کو ایسے منظم کیا ہے کہ لوگوں میں خود بخود صحیح اخلاق پید ہوںاور جب وہ عملی میدان میں قدم رکھیں ، تو قانون کو مقدس اور ناقابل مخالفت سمجھیں ۔
اس قسم کی تر بیت قانون کے عام طورپر نافذ ہونے کاسبب بنتیہے اور نتیجہ میں قابل توجہ حد تک معاشرے کی سعادت کو پورا کر کے قانون کو ناکامی سے نجات دلائی جاتی ہے۔ لیکن جاننا چاہئے کہ ایسے معاشروں میں پرورش پانے والے افکار دو قسم کے ہوتے ہیں :
١۔انسان دوستی جیسے عقائد و افکار، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیرخواہی اور رحم دلی ،جو حقیقت پسندی پر استوار ہوں ،بیشک ان کو آسمانی ادیان سے لیا گیاہے اور قدیم زمانے سے ( جبکہ ترقی یافتہ معاشرے وجود میں نہیں آئے تھے )دین، لوگوں کو ان افکار کی طرف دعوت دیتا رہا ہے ۔
لہذا، جو خوش بختی اور سعادت ان افکار کے ذریعہ ترقی یافتہ معاشروں میں نظر آرہی ہے، وہ دین کے برکات میں شمار ہوتی ہے ۔
٢۔بیہودہ اور افسانوی عقائد وافکار ، جن کی خرافات کے بازار کے علاوہ کہیں کوئی اہمیت نہیں ہے ،مثال کے طور پر افراد کو تلقین کی جاتی ہے کہ اگر وطن کی نجات کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھائی یاقتل کئے گئے تو،تمہارا نام تاریخ کے صفحات میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گااگرچہ ،اس قسم کے خرافاتی تصورات کا ایک عملی نتیجہ ہوتا ہے اوریہ بھی ممکن ہے کوئی شخص اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر میدان جنگ میں جان نثاری کا ثبوت دے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کردے،لیکن وہ فائدے کے بجائے قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے ،کیونکہ یہ تفکرانسان کو خرافاتی بنا کر اس کی حقیقت پسندانہ فطرت کو بیکار بنادیتی ہے ،جو لوگ خدااور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور موت کو نابودی اورفنا سمجھتے ہیں ،ان کی نظر میں موت کے بعد ابدی اور کامیاب زندگی کامفہوم ومعنی نہیں ہے ۔
انسان کے آرام وآسائش میں اسلام کی اہمیت
جیسا کہ ہم نے بیان کیا ،دینی قوانین ،دوسرے اجتماعی طریقوں کی بہ نسبت ممتاز ہیں۔ تمام ادیان میں اسلام کو برتری حاصل ہے۔اس لحاظ سے انسانی معاشروں کے لئے اسلام دوسرے تمام روشوں سے زیادہ مفید ہے۔اوراسلام اوردوسرے ادیان اور اجتماعی طریقوں کے موازنہ سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے ۔
اسلام کا دوسرے ادیان سے موازنہ
اسلام ،تمام ادیان کے درمیان منفرد دین ہے جوسو فیصد اجتماعی ہے۔اسلام کی تعلیمات آج کل کے عیسائی دین کے مانند نہیںہیں جو صرف لوگوں کی اخروی سعادت کو مد نظر کھتا ہے اور ان کی دینوی سعادت کے بارے میں خاموش ہے اورنہ ہی یہودیوں کے موجودہ دین کے مانند ہیں جو صرف ایک ملت کی تعلیم و تر بیت کی مقبو لیت کو مد نظر رکھتاہے ۔اسلام کی تعلیمات مجوس اوردیگر مذاہب کے مانندصرف اخلا ق واعمال سے مربوط چند موضوعات تک محدود نہیں ہیں ،بلکہ اسلام میں تمام لوگوں کے لئے دنیاوآخرت کی تعلیم و تربیت کو ہمیشہ کے لئے اور ہرزمان و مکان میں ،مد نظر رکھا گیا ہے بدیہی ہے کہ اس کے علاوہ معاشرے کی اصلاح اور لوگوں کی دنیاوآخرت کی سعادت کے لئے کوئی اور راستہ نہیں ہے :
اوّلاً:تمام انسانی معاشروں میں ۔جو اچھے روابط سے روزبروزنزدیک اور محکم تر ہو رہے ہیں ۔صرف ایک معاشرہ یا ایک ملت کی اصلاح کرناحقیقت میں ایک فضول کوشش ہے اور ایک بڑے آ لودہ تالاب یانہرکے ایک قطرہ پانی کو تصیفہ کرنے کے مانند ہے ۔
ثانیا: دوسرے معاشروں کے بارے میں غفلت کرتے ہوئے صرف ایک معاشرے کی اصلاح کرناایک ایسا امر ہے جو اصلاح طلبی کی حقیقت کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات میں کائنات اور انسان کی خلقت کے بارے میں انسان کے ذہن میں پیداہونے والے افکار ،اخلاق اورانسانی زندگی میں پائی جانے والی تمام سر گرمیاں ،کی تحقیق کی گئی ۔
لیکن اسلام میں افکار کے بارے میں ،جو عقائد حقیقت پسندانہ پہلوؤں پر مشتمل ہیں اور ان میں سر فہرست خدائے متعال کی وحدانیت ہے ،وہ اصل اوربنیاد قرار پائے ہیں۔ اوراخلاق اسلامی میں ،وہ حقیقت جسے عقل سلیم قبول کرتی ہے ،وہ توحید کی بنیاد پر استوار ہوئی ہے پھر اس کے بعد اخلاق کی بنیادپر، قواعد وضوابط اور عملی قوانین بیان کئے گئے ہیں،جس کے نتیجہ میں ہرکالے گورے،شہری و دیہاتی ،مردوعورت،چھوٹے بڑے،غلام و آقا،حاکم ورعایا،امیر وغریب اورعام وخاص کے لئے انفرادی واجتماعی فرائض بیان کئے گئے ہیں :
( ...کلمةً طیبةً کشجرة طیبةٍ اصلها ثابت وفرعها فی السّمائ ) (ابراہیم٢٤)
''... کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے جس کی اصل ثابت ہے اوراس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔''
جو شخص اسلام کے بنیادی معارف،اخلاقی تعلیمات اور فقہ اسلامی پر محققانہ نظر ڈالے، گاتو وہ ایک ایسے بے کراںسمندر کا مشاہدہ کرے گا جس کی حدوداور گہرائیوںتک پہنچنے میں انسانی عقل وشعور قاصر ہے اس کے باوجوداس کا ہر جزء و دوسرے اجزاسے متصل اور متناسب ہے اور یہ سب اجزاء مل کرخدا پرستی اور انسان پروری کو تشکیل دیتے ہیں ، جیسا کہ خدا ئے متعال نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ہے ۔
سماج کے رسم ورواج سے اسلام کا موازنہ
جب ہم دنیا کے ترقی یافتہ معاشروںکے طور طریقوں پر سنجیدگی سے نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہ ان معاشروں کی سائنسی اور صنعتی ترقی نے عقلمندوں کومتحیر کر دیا ہے،وہ طاقت وترقی کے بل بوتے پرمریخ اور چاند پرکمندڈال رہے ہیں ،ان کی ملکی تشکیلات نے انسان کوحیرت میں ڈال دیا ہے ،لیکن یہی ترقی کے راستے اپنی قابل ستائش ترقی کے باوجود ،عالم بشریت پر بدبختی وبدنصیبی ایسے مصائب کا سبب بنے ہیں ۔پچیس سال سے کم عرصہ میں دنیا کو دوبار خاک وخون میں غرق کرکے لاکھوں انسانوں کو نابود کردیا ہے اور اس وقت بھی تیسری عالمی جنگ کا فرمان ہاتھ میں لئے ہوئے عالم بشریت کو نابود کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں ۔انہی طریقوں نے اپنی پیدائش کے پہلے ہی دن سے ''انسان دوستی اور آزادی دلانے''کے نام پر دنیا کے دیگر ممالک اور ملتوں کے ماتھے پر غلامی کے داغ لگا کردنیا کے چار بڑے براعظموں کو اپنی استعماری زنجیروں میں جکڑ کرکسی قید وشرط کے بغیر براعظم یورپ کا غلام بنادیا ہے اورایک حقیر اقلیت کو کروڑوں بے گناہ انسانوں کے مال،جان ور عزت پر مسلط کر دیا ہے ۔
البتہ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ترقی یافتہ ملتیں اپنے ما حول میں مادی نعمتوں اور لذتوں سے سرشارہیں اور بہت سے انسانی آرزؤوں جیسے اجتماعی انصاف اور ثقافتی وصنعتی ترقی تک پہنچ چکے ہیں۔لیکن وہ اس کے ساتھ ہی بے پناہ بدبختیوں اور بے شمار تاریکیوں سے دوچار ہوئے ہیں کہ ان میں سے اہم ترین یہ ہے کہ بین الاقوامی کشمکش اور خون ریزیاں دنیا کے مستقبل کوعوامی سطح پر اور ہر لمحہ ماضی سے بدتروحوادث کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں ۔
واضح ر ہے کہ یہ سب تلخ وشرین نتائج ،ان ملتوں ومعاشروں کی تہذیب وتمدن اور زندگی کے طور طریقوںکے درخت کا پھل ہیں جو بظاہر ترقی کی راہ پر گامزن ہیں ۔
لیکن جاننا چاہئے کہ اس کے میٹھے پھل جن سے انسان نے بہرہ مند ہوکرمعاشرے کوباسعادت بنادیاہے،ان ملتوںکے بہت سے پسندیدہ اخلاق جیسے سچائی،صحیح کام،فرض شناسی،خیرخواہی اور فداکاری کا نتیجہ ہے ،نہ صرف قانون کا!کیونکہ یہی قوانین پسماندہ ملتوں ،جیسے ایشیااور افریقہ میں بھی موجود ہیں حالانکہ ان کی پستی اور بدبختی میں دن بدن اضافہ ہوتا جارہا ہے۔
لیکن اس درخت کا تلخ پھل ۔جس سے انسان آج تک کو تلخ کام ہے وہ انسان کے لئے تاریکی اوربدبختی کاسبب بناہے اور خود ان ترقی یافتہ ملتوں کو بھی دوسروں کی طرح نابودی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ کچھ ناپسندیدہ اخلاق ہیں،جن کاسرچشمہ:حرص،طمع، بے انصافی،بے رحمی،غرور،تکبر،ضد،اور ہٹ دھرمی ہے۔
اگرہم دین مقدس اسلام کے قوانین پر سنجیدگی سے غور کریں ،توہم متوجہ ہوں گے کہ اسلام مذکورہ صفات کے پہلے حصہ کا حکم دیتا ہے اور دوسرے حصہ سے روکتا ہے ،مختصر یہ کہ کلی طورپر تمام حق اور نیک انسان کی مصلحت کے امور کی دعوت دیتا ہے اور انھیں اپنی تربیت کی بنیاد قرار دیتا ہے اور ہر اس ناحق اوربرے کام سے روکتا ہے جو انسان کی زندگی کے آرام میں خلل ڈالتا ہے (خواہ کسی خاص قوم وملت سے مربوط ہو)
نتیجہ
مذکورہ بیانات کے نتیجہ کے طور پر مندرجہ ذیل چند نکات ذکر کئے جاتے ہیں :
١۔اسلام کا طریقہ دوسرے تمام اجتماعی طریقوں سے زیادہ پسندیدہ اورانسانیت کے لئے زیادہ مفید ہے:
( ذلک دین القیّم ولکن اکثر النّاس لا یعلمون ) (روم٣٠)
''...یقینا یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے ''
٢۔موجودہ دنیا کی تہذیب وتمدن کے واضح نقوش اور میٹھے پھل سبھی دین مقدس اسلام کی برکتیں اور اس کے آثار کی زندہ شقیں اور اصول ہیں جو مغرب والوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں ،کیونکہ اسلام ،مغر بی تمدن کے آثار کے رونما ہونے سے صدیوں پہلے لوگوں کو انہی اخلاقی اصولوں کی طرف دعوت دے رہا تھا کہ یورپ والوں نے ان پر عمل کرنے میں ہم سے پیش قدمی کی ۔
امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات میں لوگوں سے فرماتے تھے:
''تمہارا برتائوایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن مجید پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائیں'' ۔(۱)
٣۔اسلام کے حکم کے مطابق ''اخلاق''کو اصلی مقصد قرار دینا چاہئے اور قوانین کو اس کی بنیاد پر مرتب کرنا چاہئے ،کیونکہ پسندیدہ اخلاق کو فراموش کرنا(جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے کا سبب ہے)انسان کو معنویت سے مادیت کی طرف ڈھکیل دیتا ہے اور اس کو بھیڑئیے،چیتے اور گائے جیسا درندہ بنادیتا ہے نیز اس میں گوسفند کے صفات پیدا کر دیتا ہے ۔
اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:
''بُعِثتُ لاتِّمم مکارم الاخلاق'' (۲)
''میری بعثت کا اصلی مقصد ،لوگوں کی اخلاقی تر بیت ہے ''
طبیعی وسائل سے اسلام کی ترقی
غیرطبیعی وسائل ،کہ جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہے، ناکام ہوتے ہیں اور جلد یا کچھ مدت بعد نا بود ہوجا تے ہیں، اسلام جیسے دین میں جو کہ بشریت پر ہمیشہ حکو مت کرنا چاہتا ہے، ان غیر طبیعی وسائل سے استفادہ کرنا صحیح نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنی ترقی میں طاقت کا سہارا نہیں لیا ہے .یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ''اسلام تلوار کا دین ہے''حقیقت میں یہ لوگ صدراسلام کی جنگوںکو ظاہری طور پردیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہوجاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں ۔جودین علم وایمان کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو ،اس کے لئے بعید ہے کہ وہ اپنی ترقی اور لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کے لئے تلوار کا سہارا لے لے (اسلام میں جہاد کے فلسفہ کا مطالعہ فرمائیں )اسی لئے اسلا م نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے نیرنگ ،جھوٹ اورسیاسی شعبدہ بازی کا سہارا نہیں لیاہے اورانہیں صحیح نہیں جاناہے ،کیونکہ اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ حق زندہ ہواور باطل نابود ہو اور حق تک پہنچنے کے لئے باطل کی راہ پر گامزن ہونا ،حق کی نابودی کا سبب بنتا ہے۔
خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے:
'' خداظالموں ،بدکاروں اور حق کو چھپانے والوں کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیتا ''(۳)
تبلیغ اور دعوت اسلام
اسلام نے لوگوں کی ہدایت اور حق کو پھیلانے کے لئے ایک ایسے راستہ کاانتخاب کیا ہے جو انسان کی فطرت اور خلقت کے عین مطابق ہے اور وہ''تبلیغ اور دعوت کا راستہ ''ہے ،جو انسان کے لئے حقائق،حقیقت پسندانہ فطرت اور سعادت طلبی کو واضح کر کے اسے بیدار کر دیتا ہے اور آسانی کے ساتھ اسے حق کے حوالے کرتا ہے ۔
یہ روش،یعنی تبلیغ ودعوت،ایک ایسی روش ہے جسے تمام انبیاء علیہم السلام نے اختیار کیاہے۔اسلام ،جو خاتم ادیان اوربھر پور صلاحیتوں کاحامل دین، میں اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا گیا ہے اور اس راستہ کا اپنا نا مسلمانوں پر واجب کیا گیا ہے، تا کہ دین کی نشر و اشاعت میں کوتاہی نہ کریں۔
خدائے متعال اپنے پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتاہے:
'' میرا او ر میرے پیرؤں کا راستہ یہ ہے کہ وہ مکمل بصیرت کے ساتھ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں ''(۴)
تبلیغ کا طریقہ
مذکورہ آیہ شریفہ سے معلوم ہوتاہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام مکمل بصیرت سے انجام پاناچاہئے، مختصر یہ کہ مبلغ کو تبلیغ سے مربوط دینی مسائل سے آگاہ ہوناچاہئے،اور تبلیغ کے طریقہ کار، شرائط اور اس کے آداب سے پوری طرح باخبر ہونا جاہئے۔ البتہ تبلیغ کے شرائط و آداب بہت زیادہ ہیں، جیسے: خوش اخلاقی ، خندہ پیشانی، وقار و بردباری او رحق و انصاف کا احترام و غیرہ لیکن ان میں سب سے اہم علم وعمل ہے۔ کیونکہ جو شخص علم کے بغیر تبلیغ کرتاہے، چونکہ وہ حقیقت سے آگاہ نہیں ہے اس لئے باطل کی تبلیغ کرنے والوں کی طرح ، لوگوں کی حق تلفی کرنے اور انھیں گمراہ کرنے میں پروا نہیں کرتاہے اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، حقیقت میں وہ جو کچھ کہتاہے، اس کی اپنے عمل سے تردید کرتاہے اور جس چیز کی اپنی زبان سے تعریف کرتاہے، اس کی اپنے کردار سے، مذمت کرتا ہے جو شخص کسی چیز کی طرف دوسروں کودعوت دیتاہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے، جو ایک ہاتھ سے کسی چیز کو کھینچتاہے اور دوسرے ہاتھ سے اسے ڈھکیلتا ہے۔
خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتاہے:
''کیا تم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟''(۵)
ہمارے آٹھویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے:
''لوگوں کو اپنے گفتار و کردار سے دعوت دو، نہ صرف گفتار سے ''(۶)
____________________
١۔ نہج البلاغہ ،صبحی صالح،ص٤٢٢۔
۲۔بحار الانوار ،ج٧١،ص٣٧٣۔
۳۔بقرہ١٥٩و١٧٤۔
۴۔ یوسف١٠٨۔
۵۔ (اتامرون النّاس بالبّر و تنسون انفسکم ...) (بقرہ/ ٤٤)۔
۶۔ بحار الانوار ، ج ، ص ٣٠٨۔
اسلام میں تعلیم و تربیت
اسلام،جہل و نادانی کی سرزنش کرتے ہوئے علم و دانش کی مدح کرتاہے، اور اپنے پیروؤں کو علم و فضیلت حاصل کرنے کی تشویق کرتاہے، جبکہ دوسرے ادیان کی کتابیں آزادانہ غورو فکر اور مخالفوں کی باتوں کی تحقیق کرنے سے منع کرتی ہیں۔ اسلام کی آسمانی کتاب(قرآن مجید) حق کو قبول کرنے، کا حکم دینی ہے خواہ وہ مخالف ہی کی طرف سے کیوں نہ ہواور انسان کے ساتھ استدلال اور آزادانہ طریقہ سے گفتگو کرتی ہے اور لوگوں کو آسمان وزمین اور ان میں موجودہر چیز کی پیدائش،انسان کی خلقت ،اسلاف کی تاریخ اور کائنات کی فطری گردش کے بارے میں غوروفکر کرنے کی تاکید کرتی ہے ،بلکہ اس کے علاوہ محسوسات کے دائرہ سے آگے بڑھ کر اور ماوراء طبیعت کے بارے میں غور و فکر کی تاکید کرتی ہے ۔
اس مو ضوع کے بارے میں جوآیات اور روایات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشینوں سے ہم تک پہنچی ہیں ،وہ بے شمار ہیں۔پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم علم حاصل کرنے کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا: ''علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے''(۱) ۔
اسلامی تعلیمات کے دواہم شاہکار
مختلف انسانی معاشروں میں موجود ہر روش میں کچھ اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں، اگر وہ اسرار
عام لوگوں پر ظاہر ہوجائیں، تو معاشرے کو چلانے والے حکام اور ان کی شہوانی خواہشات متاثر ہوتی ہیں، اس لئے وہ ہمیشہ کچھ حقائق کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اس مطلب کاسبب یہ ہے کہ بہت سے مطالب اور ضوابط ان کے دماغ کی اپج ہوتے ہیں، چونکہ انھیں اپنی عقل اورمعاشرے کی مصلحت کے خلاف پاتے ہیں، اس لئے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ اسرار فاش ہوگئے تو ان پر اعتراضات کی بوچھار ہوجائے گی اور ان کے مفاد خطرہ میں پڑجائیں گے۔
اسی وجہ سے عیسائیوں کے کلیسا اور دوسرے ادیان کے روحانی مراکز انسان کو آزادانہ غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ، بلکہ دینی معارف او رمذہبی کتابوں کی توضیح و تفسیر کا حق صرف اپنے سے مخصوص کرتے ہیں اور لوگوں کوان کی ہر بات چون وچرا اور بحث ومباحثہ کے بغیر قبول کرناہوتی ہے۔ اسی روش نے بہت سی دینی روشوں کو نقصان پہنچایا ہے اور عیسائیوں کی موجودہ روش اس بیان کی سچائی کی گواہ ہے۔ لیکن اسلام اپنی حقانیت پر اطمینان و اعتماد رکھتاہے اور اپنی راہ میں کسی قسم کے مبہم اور تاریک گوشہ کو نہیں پاتا اس لئے دوسرے تمام مذہبی اور غیر مذہبی طریقوں کے برخلاف حسب ذیل دومسائل پرزیادہ توجہ دیتاہے:
١۔ اسلام کسی بھی حقیقت کو پوشیدہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اپنے پیرؤں کو اس بات کی اجازت دیتاہے کہ کسی حقیقت کو چھپائیں، کیونکہ اس مقدس دین کے قوانین فطرت اور خلقت کے قانون کے مطابق مرتّب ہوئے ہیں اور حق و حقیقت کی روسے اس کی کوئی چیز قابل تردید نہیں ہے۔
اسلام میں ، حقائق کو چھپانا گناہان کبیرہ میں شمار ہوتاہے اور خدائے متعال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ١٥٩ میں حق کو چھپانے والوں پر لعنت کی ہے۔
٢۔ اسلام اپنے پیرؤں کو حکم دیتاہے کہ حقائق او رمعارف کے بارے میں آزادانہ طور پر غور و فکر کریں اور جہاں پر بھی معمولی سا ابہام نظر آئے ، و ہیں رک جائیں اور آگے نہ بڑھیں تا کہ ان کا روشن ایمان شک و شبہہ کی تاریکی سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رہے اور اگر شک و شبہہ سے دوچار ہوجائیں تو نہایت انصاف اور حق پسندی سے اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں اور آزادانہ طور پر ان کو حل کریں ۔ خدائے متعال فرماتاہے:
''جس چیز کاتمھیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ۔(۲) ''
آزادی فکر اور حق پوشی
غور و خوض کے ذریعہ حقائق کو درک کرکے انھیں قبول کرنا انسان کے ذہن و دماغ کی گراں قیمت پیدا وار ہے اور انسان کو حیوان پر امتیاز ، فضیلت ، شرف او رفخر بخشنے کاواحد سبب ہے، اور انسان دوستی و حقیقت پسندی کی فطرت کردیا جائے، تقلیدی افکار کوتھوپ کرانسان کی آزادی فکر کو سلب کرلیا جائے یا حقائق کو چھپا کر اس کی عقل کو گمراہ کردیا جائے۔ مختصر یہ کہ اسبابات کی اجازت نہیں دیتی کہ خدا پسند افکار کو ناکارہ بنادیا جائے ۔ لیکن اس حقیقت سے بھی غافل نہیں رہنا چاہئے کہ جہاں پر انسان کسی حقیقت کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا مد مقابل کی ہٹ دھرمی اور سخت رویہ کی وجہ سے ومنزلت کے لئے،
انسان کے ذہن ودماغ کی گمراہی اور دوسرے مالی، جانی اور عزت کو پہنچنے والے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے حقائق کی پردہ پوشی کو جائز سمجھتی ہے۔
ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنی بہت سی حدیثوں میں لوگوں کو بعض ایسے حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا ہے جن کو سمجھنے کی انسان میں استعداد نہیں ہوتی۔ خدائے متعال نے بھی اپنے کلام میں دوموقعوں پر تقیہ کے طور پر حق چھپانے کو جائز جاناہے۔(۳)
نتیجہ
اسلام چند مواقع پر حق وحقیقت کے چھپانے کو بلامانع بلکہ ضروری سمجھتاہے:
١۔ تقیہ کے موقع پر : یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں حق کے آگے بڑھنے کی کوئی امید نہیں ہو، بلکہ اس کے اظہار سے مال، جان اور عزت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔
٢۔ ایسے موقع پر جہاں حق کسی کے لئے قابل فہم نہ ہو بلکہ اس کا اظہار گمراہی کاسبب بنے یا خود حق کی بے حرمتی کا باعث ہو۔
٣۔ ایسے مواقع پر جہاں آزاد فکر، استعداد کے فقدان کی وجہ سے، حق کو بر عکس دکھاتے اور گمراہی کاسبب بنے۔
____________________
١۔ ''طلب العلم فریضةعلی کل مسلم'' (بحار الانوار ، ج ١، ١٧٢)۔
۲ (ولا تقف مالیس لک به علم...)(اسرائ/٣٦)
۳۔سورہ آل عمران، آیت ٢٨ اور سورہ نحل آیت١٠٦۔
سماجی زندگی میں اسلام کی خدمات
افراد کے منافع کاتحفظ اوررفع اختلاف
گزشتہ بحثوں سے واضح ہوا کہ دین مقدس اسلام،ایک مکمل اجتماعی طریقہ ہے ،اور واضح ہے کہ ایک معاشرے کی مکمل سعادت اور سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہوں اور زندگی کو لاحق کشمکش اوران زیادتیوں کا حتی الامکان سدّ باب کیا جائے جن سے زندگی اور اس کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہے تاکہ معاشرہ آرام اور تکامل کی طرف بڑھ سکے ۔
البتہ ایک انسان کی فطری آرزو یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں حقیقت پسندی کے ساتھ ساتھ جسم وروح کے لحاظ سے سالم ہو اور اس کے شایان شان روٹی، کپڑا، مکان اس کے پاس ہو۔ اوروہ خاندان کو تشکیل دے کر اپنی جوانی اور بوڑھاپے کی آرزئوں کو پا سکے ،اور امن وامان کے ماحول میں آرام کی زندگی گزارے ،اس طرح انسانیت کی شا ہراہ پرکسی مزاحمت اور روکاوٹ کے بغیر اپنی تلاش وکوشش کو جاری رکھے اور تکامل تک پہنچ جائے۔
ایک انسانی معاشرہ بھی اپنے افرادکے لئے ،اس سے بڑھ کر آرزو نہیں رکھتا ہے اسلام نے اس انفرادی اور اجتماعی آرزو کو عملی جامہ پہنایا ہے ،کیونکہ اس نے معاشرے کوایک ایسا نہج دے دیا ہے کہ اگر اس کو حقیقت بینی کی روشنی میں قبول کیا جائے تو انسان کی زندگی کے مفادات محفوظ رہیں گے اور ان کے اختلافات دور ہوجائیں گے ۔
اسلام کا طریقہ کار اور اس کی بنیاد
اسلام نے اپنی پہلی توجہ انسان کی حقیقت پسندی کے نہج پر مرکوز ہے ،کیونکہ یہ مقدس نہج انسان کی تر بیت کرناچاہتا ہے اور ایسے بے زبان حیوان نہیں پالنا چاہتا کہ جس کا مقصد پیٹ بھرنا اورجنسی خواہشات کوپورا کرنا ہو۔انسان ایک ایسی زندہ مخلوق ہے ،جو جذبات اورہمدردیوں کے علاوہ عقل اور حقیقت پسندی کی توانائی سے بھی مسلح ہے۔
انسان اپنی فطرت،یعنی اپنی خالص حقیقت پسندانہ فطرت کے مطابق ،درک کرتا ہے کہ وہ عالم ہستی کا ایک جزو ہے اور عالم ہستی کے دیگر اجزاء کے مانند ماورائے طبیعت ،یعنی ایک لامتناہی زندگی،قدرت اور علم سے وابستہ ہے ،عقل بھی اسی (خدا) کی مخلوق ہے۔ اسی لئے اسلام نے اپنی روش کو''توحید''کی بنیاد پر استوار کیا ہے اور جوشخص خداپرست نہ ہو ،وہ اسے انسان نہیں جانتا۔
یہاں پر ''توحید''سے مرادخدا کی یکتائی پرعقیدہ رکھنا ہے،جو اپنے دین کے ذریعہ انسان کو سعادت کی دعوت دیتا ہے اور ایک دن اسکے اعمال کاحساب لیکر اسے مناسب جزادے گا ۔
خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے :
''یہ سب(یعنی توحیدسے بے خبر لوگ)جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ گمراہ ہیں ''۔(۱)
توحیدکے جو معنی بیان کئے گئے ہیں ان کے مطابق وہ اسلام کی پہلی اصل اور اس کابنیادی ستون ہے۔
اسلام کا دوسراستون ''پسندیدہ اخلاق'' ہے ،جو توحید پر استوار ہے ،کیونکہ اگراانسان توحید کے مطابق اخلاق نہ رکھتا ہو ،تواس کامقدس ایمان محفوظ نہیں رہے گا ۔
اور اسی طرح،جیسا کہ بیان کیا گیا ،قوانین اورضوابط خواہ کتنے ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہوں، ہرگز ایک ایسے معاشرے کونہیں چلاسکتے جس میں اخلاقی انحطاط پایا جاتا ہو۔
اس لحاظ سے ،اسلام میں عقیدئہ توحید کے مطابق اخلاقیات کا ایک طویل سلسلہ جیسے:انسان دوستی،رحم دلی،عفت اور عدالت کے جیسے دوسرے امورانسانی معاشرے کے لئے مرتب کئے گئے ہیں جو توحید کے عقیدہ کے نفاذ کے ضامن اور قوانین وضوابط کے محافظ ہیں ۔
معاشرے کی سعادت میں مفید و مؤثرہونے کی وجہ سے اخلاق کادوسرا درجہ ہے،چوں کہ توحیدپہلے درجہ پر ہے ۔
توحید اور اخلاق کے اصولوں کو مستحکم اور استوار کرنے کے بعداسلام نے قوانین کا ایک طویل سلسلہ وضع کیا ہے ،جن کا تعلق اخلاق سے رابطہ ہے ،یعنی مذکورہ قوانین کا سر چشمہ پسندیدہ اخلاق ہے اور پسندیدہ اخلاق بھی اپنے قوانین کے ذریعہ مستحکم ہوتا ہے۔اور یہی قوانین و ضوابط ہیں جو معاشرے کے حیات بخش مفاد کا تحفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے اختلافات کو دور کرتے ہیں۔
سماجی اختلافات
انسان کے اختلافات ،جو اتحاد واتفاق کے رشتہ کوتودیتے ہیں اور اجتماعی نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں ،دوقسم کے ہیں :
١۔وہ اختلافات جو اتفاقی طور پر دوافراد کی ذاتی چپقلش کے نتیجہ میں رونما ہوتے ہیں، جیسے دوافراد کے درمیان کسی موضوع پر ہونے والا جھگڑا اور ایسے اختلافات کو عدلیہ رفع کرتی ہے ۔
٢۔وہ اختلافات جو طبیعی طور پر معاشرے کو دو مختلف گروہوں میں تقسیم کردیتے ہیں ،اور اجتماعی انصاف کی طرف کسی قسم کی توجہ کئے بغیر ،ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر مسلط کیا جا تا ہے اور کمزورطبقہ کی سعی و کوشش کے ماحصل کو طاقتور گروہ کے نام مخصوص کیا جاتا ہے، جیسے:حاکم ومحکوم ،دولت مند و فقیر ،عورت و مرداور ملازم وافسرکے طبقے ترقی یافتہ اور بے دین معاشروں میں اسی صورت میں زندگی کرتے ہیں اور ہمیشہ طاقتور لوگ کمزوروں اور اپنے ماتحتوں کا استحصال کرتے ہیں ۔
منافع کی حفاظت اوررفع اختلافات کے بارے میں اسلام کا عام نظریہ اسلام کلی طور پر،معاشرے کی سعادت، جو کہ لوگوں کے مفاد کی حفاظت اور ان کے اختلافات کے سدِّ باب کی مر ہون منت ہے ،کودو چیزوں کے ذریعہ فراہم کرتا ہے :
١۔طبقاقی امتیاز کو کلی طور پر لغو کر کے اس کی اہمیت کو ختم کردیتاہے ،اس معنی میں کہ اسلامی معاشرے میں لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیںاور کسی کو ہر گز یہ حق نہیں ہے کہ دولت یا اجتماعی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں پر برتری جتائے او رانھیں حقیر و خوار سمجھے اور ان سے فروتنی اختیار کرنے او رتسلیم ہونے کا تقاضا کرے، یا اپنے مخصوص عہدہ کی بناپر خود کو بعض اجتماعی ذمہ داریوں سے مستثنیٰ قرار دے یا کسی جرم کے مرتکب ہونے پرخود کو معاف اور سزا سے بری سمجھے۔ قوانین و ضوابط کے نفاذ میں معاشرے کے سرپرست کا حکم نافذ ہے اور سب کواس کے سامنے سر تسلیم خم کرناچاہئے اور اس کا احترام کرناچاہئے، لیکن اس کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد میں یہ توقع نہیں رکھنی چاہئے کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں یا جو کچھ وہ انجام دے اس کے بارے میں انھیں اعتراض و تنقید کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ معاشرے کا فرمانروا ہے، اس لئے اسے بعض عام اور سماجی ذمہ داریوں او رفرائض سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ اسی طرح ایک دولت مند شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت کو اپنے لئے فخر و مباہات کا سبب قرار دیکر غریبوں، محتاجوں اور اپنے ما تحتوں کی سرکوبی کرے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے فرمانرواؤں کو یہ توقع نہیں کرنی چاہئے کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی ہرفضول بات کو معاشرہ کے پسماندہ اورناداروںکے مسلم حق کے مقابلہ میں فوقیت دیں۔
نیز اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتاہے کہ کسی بھی طبقہ میں ایک طاقتورلوگ ناحق کمزوروں پر مطلق حکمرانی کریں۔ خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتاہے:
''اسلام کے پیرو آپس میں بھائی او رمساوی ہیں ' '۔(۲)
نیز فرماتاہے:
''خدا کا دین تمہاری (اہل کتاب اور مسلمان )آرزئوں اور خواہشوں کا تابع نہیں ہے ،جو بھی برا کام انجا م دے گا ،اسے سزا ملے گی ''۔(۳)
البتہ دین اسلام میں کچھ خصوصیات ، جیسے : دین کے پیشواؤں کی اطاعت اور والدین کا احترام، ہیں کہ اس میں مساوات نہیں ہے بلکہ صرف ایک طبقہ کے لئے دوسرے طبقہ کی نسبت کچھ فرائض ہیں، لیکن اس سلسلہ میں بھی جس کے حق میں یہ حکم ہے، وہ دوسروں پر برتری نہیں جتلا سکتا ، یعنی وہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنے مقام پر فخر نہیں کرسکتا ہے۔
جی ہاں، چونکہ انسان فطر ی طور پر امتیاز و فضیلت طلبی کی جبلّت رکھتا ہے ، اسلام نے اس کی اس فطری جبلّت کو سر کوب کئے بغیر اس کے لئے ایک عمل معین فرمایا ہے اور وہ ''تقویٰ ''ہے۔
اسلام میں حقیقی قدر و قیمت پرہیزگاری کے لئے ہے اور چونکہ تقویٰ کا حساب چکانے والا خدائے متعال ہے ، اس لئے یہ امتیاز جس قدر زیادہ ہوجائے ،کوئی رکاوٹ ایجاد نہیں کرتا، اس کے برعکس طبقاتی امتیاز معاشرے میں فسادپھیلانے کا سب سے بڑا سبب اور افراد کے آپس میں ایک دوسرے کے لئے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔
اسلام کی نظر میں ،ایک پر ہیزگارفقیر، بے تقوی ٰسرمایہ داروں کے ایک گروہ پر فضیلت رکھتا ہے اور ایک پر ہیز گا عورت سیکڑوں لا ابالی مردوں سے بہتر ہے۔
خدائے متعال فرماتا ہے :
''انسانو!ہم نے تم کو ایک مرد اورعورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میں شا خیں اور قبیلے قرار دئیے ہیں تاکہ آ پس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو ،بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے ۔''(۴)
نیز فرماتا ہے :
''میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا ،چاہے وہ مردہو یاعورت ،سب ایک نوع سے ہیں اور انسان ہیں ۔''(۵)
٢۔چوں کہ تمام افراد، انسانیت اور معاشرے کے رکن ہونے کے لحاظ سے شریک ہیں اور تمام لوگوں کا کام اوران کی کوشش محترم ہے،لہذاکچھ قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں ہر فرد کے مفادات کا تعین ہوسکے اور اجتماعی تجاوز اور کشمکش کا راستہ خود بخود بند ہو جائے۔
ابتدائی اصول کومدنظر رکھتے ہوئے یہ قوانین کچھ اس طرح بنائے گئے ہیں کہ معاشرے کے مختلف طبقاتی فاصلے بالکل ختم ہو جائیں ،دوریوں کو نزدیکیوں میں بدل دیا جائے۔ ان بیانات کی روشنی میں مفادات کے تحفظ اور معاشرے کے اختلافات کودور کرنے کے سلسلہ میں اسلام کا خاص طریقہ اجمالی طور پر واضح ہوجاتا ہے۔
عداوت و اختلاف سے اسلام کا مقا بلہ
معاشرے کے مختلف طبقات میں طبیعی طورپر پیدا ہونے والے اختلافات،جیسے رعایا اورحاکم کا طبقہ ،غلام و ما لک ا ورکام لینے والے و مزدور کے درمیان اختلا فات دو طریقوں سے وجود میں آتے ہیں :
١۔ایک شخص کا دوسرے شخص کے حقوق پر تجاوز کر نے سے:مثلا کام لینے والا، مزدورکی مزدوری ادانہ کرے ،ایک مالک اپنے نوکر کی پوری اجرت نہ دے اس کے حق میں ظلم اور ناانصافی کرے یاحاکم اپنی رعایامیں سے کسی کے حق میں ظالمانہ حکم جاری کرے۔
اسلام نے اس مشکل کو حل کرنے کے لئے بہت سے قوانین مقرر کئے ہیں،کہ ان کو نافذ کرنے سے ہرایک کے حقوق محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہر شخض اپنے کھوئے ہوئے حقوق کو پاسکتا ہے ۔اسلام نے اس کام کے لئے معاشرے کی ہرفرد کو اجازت دی ہے کہ اگرکوئی شخض اس کے ساتھ ظلم کرے (چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو)توقاضی کے پاس شکایت کرنی چاہئے۔
امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ میں ایک مسلمان کاحضرت کے ساتھ کچھ اختلاف ہوگیا،اس نے قاضی کے پاس جاکر استغاثہ کیا۔حضرت ایک عام شخض کی طرح اس قاضی (جسے خودآپ نے منصوب فرمایاتھا)کے پاس حاضر ہوئے اور فیصلہ ہوا۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ حضرت نے قاضی سے فرمایا کہ شکایت کرنے والے اورمیرے درمیان برتاؤ میں کسی قسم کا فرق نہ کرے۔
٢ ۔ ایک طاقتور شخص کا کمزور اور اپنے ماتحت کے اوپر دھونس جمانااور اس کے ساتھ زیادتی کرنا ، جیسے ایک کام لینے والا اپنے مزدوروں کو ذلیل و خوار سمجھے ،کوئی مالک اپنے سامنے کھڑار کھے ، اور اسے اپنے سامنے جھک کر تعظیم کرنے پر مجبور کرے یا حاکم اپنی رعایا سے اعتراض اور استغاثہ کا حق چھین لے، کیونکہ اس قسم کے برتاؤ میں غیر خدا کی پرستش کا پہلو پایاجاتاہے، اس لئے اسلام نے ان چیزوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی شخص اپنے ما تحت سے انجام فریضہ کے علاوہ کسی قسم کی توقع نہیں رکھ سکتا ہے اور ان پر اپنی بزرگی و عظمت کا مظاہرہ نہیں کرسکتا ہے۔ اسلام میں بہت سے ایسے اخلاقی احکام موجود ہیں جو لوگوں کو سچائی، انصاف اور حسن اخلاق کی دعوت دیتے ہیں اور عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، نیکی اور خدمت کرنے والوں کی تشویق کرتے ہیں اور ، بد کرداروں ، نا اہلوں او ر برے لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔
یہ ایسے پسندیدہ اخلاق ہیں کہ اگر معاشرے میں یہ نہ ہوں تو معاشرہ بدبختی سے دوچار ہوجائے گا اور دنیا و آخرت میں ناکامی و بدبختی میں مبتلا ہوگا۔
ممکن ہے کہ کسی کو ان قوانین سے بے اعتنائی اور ان پر عمل نہ کرنا اس کے لئے بظاہر معمولی فائدہ ہو، لیکن دوسری طرف یہ ایک ناپاک او رخطرناک ماحول کو پیدا کرتاہے کہ جو اس کو اس معمولی فائدہ سے محروم کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدوں سے اس کو محروم کرتاہے اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو ایک عمارت کے سنگ بنیاد کو باہرنکال کر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر کرتاہے اور اس طرح اس عمارت کی ویرانی کا سبب بنتاہے۔
رفع اختلاف کے لئے ایک عام وسیلہ
اسلام نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ معاشرے کے فائدے کے بارے میں سوچیں اور خود خواہی سے پرہیز کرکے اپنے ذاتی مفاد کو اسلامی معاشرے کے فائدہ میں دیکھیں اور معاشرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں۔
ایک مسلمان کو پہلے حقیقی مسلمان ہونا چاہئے، اس کے بعد وہ ایک تاجر ، کسان، صنعت گر یا مزدور بنے اور جو شخص خاندان کو تشکیل دینا چاہتا ہے، اسے پہلے مسلمان ہونا چاہئے اس کے بعد اپنے فیصلہ پر عمل کرے۔ مختصر یہ کہ وہ جو بھی کام انجام دینا چاہے اور جو بھی مقام او رعہدہ سنبھالنا چاہے، اس کے لئے صحیح دین و ایمان کی ضرورت ہے۔
ایسا شخص ہرکام اور ہر فیصلہ کے سلسلہ میں سب سے پہلے اسلام و مسلمین کی مصلحتوں اور فائدوں کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے بعد اپنی ذاتی مصلحت کو مدنظر رکھتا ہے اور وہ ہزگز کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا جس میں اسلام و مسلمین کے لئے نقصان ہو اگر چہ اس کا م میں اس کا ذاتی فائدہ بھی نہ ہو۔
البتہ معلوم ہے اگر کسی معاشرے میں اس قسم کی فکر پیدا ہو جائے تواس معاشرے کے افراد میں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا ۔خدائے متعا ل فرماتا ہے :
( واعتصموا بحبل اللّه جمیعاً ولا تفرقوا ) ۔)
(آل عمران١٠٣)
''اوراللہ کی رسی کومضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو''
نیز فرماتاہے:
( و انّ هذا صراطی مستقیماً فاتّبعوه ولاتتّبعوا السّبل فتفرق بکم عن سبیله ) (انعام١٥٣)
''اور یہ ہماراسیدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جائوکہ راہ خداسے الگ ہو جائو گے...''۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
''مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہئے تا کہ اغیار کے مقابلہ میں ایک طاقت کی صورت میں آئیں ۔''(۶)
نماز،روزہ اورحج یارفع اختلافات کا وسیلہ
اسلام کے فخرومباہات میں سے ایک مسئلہ ''عبادت'' ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے ادیان کے لوگ،جیسے یہودونصاری اپنے دینی احکام کے مطابق عمومی عبادت خانوں کے علاوہ عبادت سے محروم ہیں اور ان کے مذہبی قانون کی نظرمیں وہ کلیسا اور اپنے عبادت خانوں کے علاوہ کہیں عبادت انجام نہیں دے سکتے اورنماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ۔لیکن اسلا م میں اِن پابندیوں کو ختم کردیا گیا ہے اور ہر مسلمان پرواجب ہے کہ اپنی عبادت کوجہاں چاہے انجام دے ،مسجد میں ہو یا کہیںاور،مسلمان معاشرے میں ہو یا کفر کے معاشرے میں ،لوگوں کے درمیان ہو یاتنہا ،صحت مندی کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ۔
١۔والمسلمون تتکافأ دماؤهم وهم ید علی من سواهم ...(اصول کافی،ج١،ص٤٠٣)۔
بہر حال اپنی عبادت کوانجام دینا چاہئے ،اور یہ بذات خود اسلام کی کامیابی کے اسرار میں سے ایک ہے ۔پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:
''میرے لئے تمام روئے زمین عبادت خانہ اور پرستش گاہ ہے ۔''(۷)
اسی لئے شریعت اسلا م نے نماز،روزہ اورحج کو پہلے مرحلہ میں انفرادی قرار دیا ہے ،اس معنی میں کہ ہرفرد سے اس کی انجام دہی کا مطالبہ کیا ہے اور جماعت میں شریک ہونے کو لازم نہیں کیاہے ۔لیکن دوسرے مرحلہ میں ان عبادتوں کے اجتماعی فوائد کو بھی نظرانداز نہیں کیا ہے اور انھیں اجتماعی اہمیت دی ہے مثلا انسان اس کے ذریعہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی بندگی ونیاز مندی کا اظہار کرتا ہے لہذا جماعت میں حاضر ہونامستحب قرار دیا ہے ۔
اسی طرح روزہ جو انفرادی ریاضت کے لئے قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو سال میں ایک مہینہ دن کے میں کھانے پینے اورجنسی آمیزش سے پر ہیز کرنا چاہئے اور اس کے ذریعہ اپنے اندر پر ہیز گاری اور تقویٰ پیدا کرے، اس کے باوجود اس کے کہ یہ ایک انفرادی فریضہ ہے اور اس میں اجتماعی پہلو نہیں پایا جاتا،لیکن شوال کی پہلی تاریخ کو ماہ مبارک رمضان میں فریضہ کے انجام کے شکرانہ میں مسلمان عید منائیں اور ان پر فرض ہے کہ نماز عید فطر کو باجماعت پڑھیں ۔
اسی طرح حج میں جس کے ذریعہ ،خدا کی دعوت پر لبیک اور مادی میلانات سے دوری اورپروردگار کی ذات کی طرف توجہ کرناہوتاہے ،باوجودیکہ یہ ایک انفرادی عبادت ہے،
لیکن چونکہ عبادت کی ایک خاص ومعین جگہ ہے ،لہذادنیاکے مسلمان مجبورا ایک جگہ پر جمع ہو تے ہیںاورایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو ۔ جس دن حج کے بعض اعمال انجام دئیے جاتے ہیں ۔اسلا می عید قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایک جگہ جمع ہو کر نماز عید پڑھیں ۔
اسلام میں جو یہ اجتماعات مقرر ہوئے ہیں ،یہ لوگوں کے طبقاتی اختلافات کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے ،کیونکہ طبقاتی اختلافات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کے لئے موثر ترین طریقہ ایک دوسرے کے درمیان موجود غلط فہمی کو دورکرنا ہے اور یہ خاصیت اجتماعی عبادت میں مکمل طور پر موجود ہے کیونکہ جوخدا کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے ،اس کا خدا کے سواکسی اور کے ساتھ سرو کار نہیں ہوتا ہے اور خدا کی رحمتوںکے دروازے ہر ایک کے لئے کھلے ہیں اور اس کی ابدی نعمتوں کا خزانہ کبھی ختم ہو نیوالا نہیں ہے اور اس کی ذات اقدس رکاوٹ کے بغیرہر ایک کو قبول کرتی ہے،جس کے نتیجہ میں اجتماعی عبادت کے دوران جو انس ،اورالفت ومحبت لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ اختلافات اور کدورتوں کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔
چنانچہ پہلے بھی اشارہ کیاجاچکا ہے ،کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین مقدس اسلام کے معارف کلی طور پر تین حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں : ''اصول دین ،اخلاق اور فقہی فروع۔''
واضح ہے کہ اس کے علاوہ اصول دین ،یعنی دین کی بنیاد،تین اصولوں پر مشتمل ہے کہ انسان ان میں سے ایک کے نہ ہونے پر دین سے خارج ہوجا تا ہے:
١۔ توحید ،یعنی کائنات کے پروردگار کی یکتائی کا اعتقاد۔
٢۔خدائے متعال کے انبیاء علیہم السلام پرعقیدہ رکھنا ہے جن کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ۔
٣۔معاد پر ایمان ،یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدائے متعال موت کے بعد سب کو زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب وکتاب لیا جائے گا ،نیک لوگوں کو ان کی نیکی کی جزا دی جائے گی اور برے لوگوں کوانکی برائی کی سزادی جائے گی ۔
مذ کورہ تین اصولوں میں دواصولوں کا اور اضافہ کیا جا تاہے،جو شیعہ عقائد کاحصہ اور مسلمات میں سے ہیں ،اورانسان ان میں سے کسی ایک پر عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے شیعہ مذہب سے خارج ہوجاتا ہے،اگر چہ اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہوتا ،یہ دواصول حسب ذیل ہیں :
١۔عدل
٢۔امامت
_____________________
۱۔(ان هم الا کا لانعام بل هم اضل سبیلا ) (فرقان٤٤)
۲۔ (انّما المؤمنون اخوه... )(حجرات / ١٠)۔
۳۔(لیس باما نیکم ولا امانی اهل الکتاب من یعمل سو ء ایجز به )(نساء ١٢٢)۔
۴۔(یاایّها النّاس انّا خلقنکم من ذکرٍ و انثی وجعلنکم شعوباً وقبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عنداللّه اتقٰکم )(حجرات ١٣)۔
۵۔انّی لااضیع عمل عاملٍ منکم من ذکرٍاو انثی بعضکم من بعض ۔(العمران ١٩٥)۔
۶۔ سفینہ البحار، ج ١، ص ١٩۔
عقائد
١۔توحید
٢۔نبوت
٣۔معاد
٤۔عدل
٥۔امامت
١۔توحید
اثبات صانع
انسان جب حقیقت بینی کی فطرت سے کام لیتا ہے تو عالم ھستی کے ہر گوشہ و کنار پر نظر ڈالنے سے اسے پروردگار عالم او رخالق کائنات کے وجود کی بہت سی دلیلیں نظر آتی ہیں، کیونکہ انسان اپنی حقیقت پسند انہ فطرت سے محسوس کرتاہے کہ مخلوقات میں سے ہر ایک،وجود کی نعمت سے مالامال ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے وجود میں ،قہری طور پر ایک معین راستہ کو طے کررہا ہے اورایک مدت کے بعدوہ اپنی جگہ کو دوسرے کے لئے چھوڑتاہے، اس نے ہر گز اپنے اس وجود کو خودہی اپنے لئے فراہم نہیں کیا ہے او رجس منظم راہ پر گامزن ہے ، اسے خودہی اپنے لئے نہیں بنایا ہے اوراپنے سفر کے راستہ کی ایجاد اور اس کے نظم و نسق میں کسی قسم کی مداخلت نہیں رکھتا، کیونکہ انسان نے، انسانیت اور انسانی خصوصیات کو اپنے لئے خود اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور انسانی خصوصیات اسے عطا کی گئی ہیں۔
اسی طرح حقیقت پسندانہ انسانی فطرت اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ یہ سب اشیاء خودبخود وجود میں آئی ہوں گی اور کائنات میں موجود نظام یوں ہی کسی حساب و کتاب کے بغیر وجود میں آگئے ہوں گے، جبکہ انسان کا ضمیر اس قسم کے اتفاق کو منظم طور پر ایک دوسرے کے اوپر چنی گئی چند اینٹوں کے بارے میں قبول نہیں کرتا۔یہاں پر انسان کی حقیقت پسندانہ فطرت اعلان کرتی ہے کہ عالم ھستی کی ضرور کوئی پناہ گاہ ہے ،جوھستی کا سر چشمہ ،اور کائنات کو پیدا کرنے اوراسے باقی رکھنے کے لئے اس کی حفاظت کرنے والا ہے ،اور وہ لا محدودوجود اور علم و قدرت کاسر چشمہ،خدائے متعا ل کی ذات ہے ،اور اس کائنات کے وجود کا سر چشمہ خدا کی ذات ہے ،چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :
( الّذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی ) (طہ٥٠)
''(خالق کائنات)وہ ہے جس نے ہرشے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے ۔''
اسی فطرت کی وجہ سے،جہاں تک تاریخ بتاتی ہے ،انسانی معاشرہ کی اکثریت ،کائنات کیلئے ایک خدا کے قائل رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ دوسرے تمام ادیان جیسے نصرانیت، یہودیت ،مجوسیت اور بدھ مت اس سلسلہ میں ہم عقیدہ ہیں اور جو پروردگار کے وجود کے مخالف ہیں ،ان کے پاس اسکے وجود کے انکار کے سلسلہ میں ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ:ہم پروردگار کے وجود کی کوئی دلیل نہیں رکھتے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے عدم وجود کی کوئی دلیل ہے ۔
مادہ پرست انسان کہتاہے :''میں نہیں جانتا''یہ نہیں کہتاہے''نہیں ہے''دوسرے الفاظ میں مادہ پرست انسان مذبزب ہے نہ منکر۔
خدائے متعال اپنے کلام میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :
( وقالوا ما هی الّا حیاتنا الدّنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الّا الدّهر وما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون )
(جاثیہ٢٤)
''اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اس میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے اور انھیں اس بات کاکوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور بس۔''
ابتدائے خلقت کی بحث
انسان اپنی خداداد فطرت سے ہر مظہر وحادثہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے وجود میں آنے کی علت تلاش کرتا ہے اور ہرگز احتمال نہیں دیتا ہے کہ کوئی چیز خودبخوداور کسی سبب کے بغیر وجودمیں آئی ہوگی ۔اگرکسی ڈرائیور کی گاڑی خراب ہوجاتی ہے تو وہ گاڑی سے اتر کرگاڑی میں اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں خراب ہونے کا احتمال ہو تاہے تاکہ گاڑی کے رکنے کاسبب معلوم کرسکے اوراسے ہرگز یقین نہیں ہوتا ہے کہ گاڑی خرابی کے بغیر ر ک گئی، اور گاڑی کو پھر چلانے کے لئے اس کے تمام وسائل سے استفادہ کرتا ہے اور ہرگز اس اتفاق کا منتظر نہیں رہتا ہے کہ گاڑی خودبخود چلے گی۔
انسان کو اگر بھوک لگ جائے تو وہ روٹی کی فکر میں پڑتاہے اورجب اسے پیاس لگتی ہے تو پانی تلاش کرتا ہے اور اگر سردی محسوس کرتاہے تولباس اور آگ ڈھونڈتا ہے ۔وہ کبھی کسی اتفاق کے ذریعہ ان ضرورتوں کو دور کرنے کا انتظار نہیں کرتا اور اس خوش فہمی میں آرام سے نہیں بیٹھتا۔
جوشخض کسی عمارت کو تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ لامحالہ اس کے سازوسامان ،معماراور مزدور وغیرہ کا انتظام کرتا ہے اوروہ بالکل یہ امید نہیں رکھتا کہ اس کی آرزو خودبخود پوری ہوجائے۔ انسان جب سے ہے اسی وقت زمین پر پہاڑ،جنگل ، وسیع دریا اورسمندر موجود ہیں۔اور اس وقت سے سورج ،چاند اورچمکنے ہوئے ستاروں کو آسمان پرمنظم اورمسلسل متحرک دیکھ رہاہے ۔اس کے باوجوددنیا کے سائنسدان اپنی انتھک علمی کوشش اور تگ دو سے مخلوقات اور حیرت انگیزمظاہر کے وجود میں آنے کے اسباب وعلل کے بارے میں بحث کررہے ہیں اور وہ ہر گز یہ نہیں کہتے کہ جب سے ہم ہیں اسی وقت سے ان کواسی طرح دیکھ رہے ہیں،لہذایہ خودبخودپیدا ہوئے ہیں۔
اسی جستجو کی فطرت اور اسباب وعلل کی بحث و تحقیق نے انسان کو مجبور کردیا ہے کہ وہ عالم ہستی اور اس کے حیرت انگیز نظام کی پیدائش کے بارے میں کھوج کرے کہ کیا یہ وسیع کائنات ،جس کے اجزاایک دوسرے سے مربوط ہیں اور حقیقت میں ایک عظیم مظہر ہے ،خودبخود وجود میں آیا ہے یا اس کا سر چشمہ کہیں اور ہے ؟اور کیا یہ حیرت انگیز نظام ،جو ثابت اور بلا استثناء قوانین کے مطابق کائنات کے گوشہ وکنار میں جاری ہے اور ہرچیز کو اس کے خاص مقصد کی طرف راہنمائی کرتا ہے ،ایک بے انتہا قدرت اور علم کی طرف سے جاری اور اس کا نظام چلایا جاتا ہے،یاکسی حادثہ اور اتفاق کے نتیجہ میں پیدا ہواہے ؟
معرفت خدا اور ملتیں
ہم جانتے ہیں کہ عہد حاضر میں روئے زمین پر دین داروں کی اکثریت ہے،اور وہ خالق کائنات پراعتقاد رکھتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں ۔کل کے انسان کی حالت بھی آج کے انسان کی سی تھی ،جہاں تک تاریخ بتاتی ہے ،وہ یہ کہ انسانوں کی اکثریت دین دار تھی اوروہ کائنات کے لئے ایک خدا کے قائل تھے ۔
اگر چہ خداشناس اور دین دارمعاشروں میں ،فکری اختلاف بھی تھااور ہر قوم چشمہ تخلیق کو مخصوص اوصاف سے متصف کرتی تھی ،لیکن اصل مقصد میں وہ اتفاق نظر رکھتے تھے ،حتی قدیم ترین تمدن کے آثار جنھیں انسان نے کشف کیاہے ،ان میں دین اور خداشناسی کی علامتیں پائی جاتی ہیںاور ایسی علامتیں بھی ملی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماورائے طبیعت پر بھی اعتقاد وایمان رکھتے تھے ۔حتی جدید بر اعظموںجیسے امریکہ اورآسٹریلیا اور قدیمی براعظموں کے دور دراز جزائرجو آخری صدیوں میں کشف ہوئے ہیں ،ان کے اصل باشندے بھی خدا کے معتقد تھے،اور وہ تصور کائنات کے سلسلہ میں اختلافات نظر کے با وجود کائنات کا ایک سرچشمہ تسلیم کرتے تھے اگر چہ قدیم دنیاسے ان کے رابطہ کی تاریخ معلوم نہ ہو سکی ۔
اس بات پر غور کرنا کہ خدا کا اعتقاد انسانوں کے درمیان ہمیشہ سے موجود تھا ،اس مطلب کو واضح کر تا ہے کہ خدا کو پہچانناانسان کی فطرت ہے اور انسان اپنی خداداد فطرت سے ،کائنات کی تخلیق کے لئے ایک خدا کو ثابت کرتا ہے۔خدائے متعال نے انسان کی اس فطری خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:
( ولئن سأ لتهم من خلقهم لیقو لن اللّه ) (زخرف٧٨)
''اگر ان سے پوچھ لوگے کہ انھیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقینا کہیں گے خدانے''
نیز فرماتا ہے:
( و لئن سالتهم من خلق السمٰوات و الارض لیقولن اللّه )
(لقمان٢٥)
''اگر ان سے پوچھ لوگے کہ انھیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقینا کہیںگے : خدا''
انسان کی زندگی میں تجسس کا اثر
اگر انسان نے خالق کائنات اور اس کے نظام کے پیدا کرنے والے ۔جو کہ اس کی فطرت کا اقتضاء ہے ۔کے بارے میں مثبت جواب دیا ،تو اس نے کائنات اور اس کے حیرت انگیز نظام کی پیدائش کے لافانی مبداء کو ثابت کیا اوراس نے تمام چیزوں کو خدا کے محکم ارادہ سے جو اسکی لامحدود قدرت وعلم پرمبنی ہے ۔اور نتیجہ میں وہ پورے وجود میں ا یک قسم کے اطمینا ن واعتماد کو محسوس کرتا ہے۔اوروہ اپنی زندگی میں رونما ہونے والی ہر قسم کی مشکلات اور سختیوں سے دوچارہونے پرہرگز نا امیدنہیں ہوتا ہے بلکہ ان سے نپٹنے کے لئے ہر قسم کی تدبیر سے کام لیتا ہے ،کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی علت وسبب۔ خواہ وہ کتناقوی ہو۔ اس کی باگ ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز اس کے زیر فرمان ہے ۔
ایسا شخض کبھی اسباب وعلل کے سامنے سراپا تسلیم نہیں ہوتا اور جب کبھی دنیا کے حالات اس کے مطابق ہوتے ہیں تو غرور و تکبر سے اس کادماغ خراب نہیں ہوتا اوروہ اپنی اورکائنات کی حقیقی حیثیت کوفراموش نہیں کرتا ،کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ظاہری اسباب وعلل خود مختار نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق حکم خدا سے ہے ۔آخر کار ایسا انسان یہ جان لیتا ہے کہ عالم ہستی میں خدائے متعال کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہئے اور خدا کے فرمان کے علاوہ کسی بھی فرمان کے سامنے مطلق طورپر تسلیم نہیں ہونا چاہئے ۔لیکن جس نے مذکورہ سوالات کا منفی جواب دیا ،وہ اس امید اور حقیقت پسندی عالی منشی اور فطری شجاعت کا حامل نہیں ہے ۔
یہی وجہ ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن ملتوں میں مادیت کا غلبہ ہے وہاں روز بروز خود کشی کے واقعات زیادہ رونما ہوتے ہیں ،اور جن کااعتقاد حسی اسباب و علل تک محدود ہو وہ چھوٹے سے چھوٹے نامناسب حالات کے رونما ہونے پراپنی سعادت و کامیابی سے نا امید ہو کر اپنی زندگی کاخاتمہ کردیتے ہیں،لیکن جو لوگ خدا شناسی کی نعمت سے مالامال ہیں،وہ موت کے دہانے پربھی نا امید نہیں ہوتے ،کیونکہ وہ خدائے قادر وبینا پر ایمان رکھتے ہیں ،اس لئے مطمئن و امید وار ہوتے ہیں ۔
حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جبکہ چاروں طرف سے دشمن کے تیر وتلوار کا نشانہ بنے ہوئے تھے ،فرماتے ہیں :
''تنہا جو چیز اس ناگوار مصیبت کو میرے لئے آسان بنا رہی ہے ،وہ یہ ہے کہ میں خدائے متعال کو مستقل اپنے اعمال پر ناظر دیکھتا ہوں ۔''
توحید کے بارے میں قرآن مجید کا اسلوب
اگر انسان پاک طبیعت اور مطمئن دل سے ،کائنات پر نظر ڈالے تو اس کے ہر گوشہ وکنار میں وجود خدا کے آثار ودلائل کا مشاہدہ کرے گا اور اس حقیقت کے ثبوت میں ہر در و دیوار سے گواہی سن لے گا ۔ اس دنیا میں جو چیز بھی انسان کے سامنے آتی ہے وہ خدا کی پیدا کی ہوئی اور مظہر ہے،یا کوئی خاصیت خدانے اس میں پیدا کردی ہے ،یاایک ایسا نظام ہے جو خدا کے حکم سے ہر چیز میں جاری ہے اورانسان بھی انہی میں سے ایک ہے اوراس کاپورا وجود اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے ،کیونکہ نہ اس کااپنا وجوداپنے آپ سے ہے اورنہ ہی اس سے ظاہر ہونے والی خاصیتیں اس کے اختیار میں ہیں اورنہ اس نے اپنی زندگی کی اس نظام کو خود بنایا ہے جو اس کی پیدائش سے ابھی تک جاری ہے اوروہ یہ فرض کرسکتا ہے کہ اس کائنات کا نظام اتفاقی طور پر وجود میں آگیا ہے ،اورنہ ہی وہ اپنے وجود اور اپنے وجود کے نظام کو اس ما حول کی طرف نسبت دے سکتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے ،کیونکہ مذکورہ وجوداور یہ نظام خود اس ماحول کی پیداوار نہیں ہے اورنہ وہ اتفاقاً وجود میں آیا ہے۔
یہاں پر انسان کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ عالم ھستی کے لئے ایک سرچشمہ تسلیم کرے جو اشیا کو خلق کرنے والا اور ان کی پر ورش کرنے والا ہے ۔وہی ہر مخلوق کو پیدا کرتا ہے اوراس کے بعد بقا اورایک خاص نظا م کی شاہراہ پراس کے مخصوص کما ل کی طرف ہدایت کرتا ہے ،چونکہ انسان عالم ھستی میں اشیا ء کو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط اور ایک خاص نظا م سے منسلک پاتا ہے ،اس لئے مجبورا فیصلہ کرتا ہے کہ خلقت کاسرچشمہ اور اس کے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے۔
انسان پر یہ حقیقت معمولی توجہ سے واضح ہوجاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں پایاجاتا۔ سوائے اس کے کہ انسان کبھی زندگی کی کشمکشوں میں ایسا گرفتار ہوتاہے کہ اپنی عقل و شعور کی تمام توانائیوں کو حیاتی مبارزوں کی راہ میں استعمال کرتاہے اور اپنے تمام وقت کو زندگی کی دوڑ دھوپ میں صرف کرتاہے، اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں غور کرنے کی تھوڑی سی بھی فرصت نہیں نکال پاتا اور نتیجہ میں اس حقیقت سے غافل رہتاہے، یا یہ کہ طبیعت کے دل فریب مظاہر سے متاثر ہو کر ہوس رانیوں اور عیاشیوں میں سرگرم ہوتاہے۔ چونکہ ان حقائق کی پابندی انسان کو بہت سی مادی لاابالیوں سے روکتی ہے، اس لئے وہ فطری طور پر ان حقائق کی تحقیق کے سلسلہ میں پہلوتہی کرتا ہے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔
اس لئے قرآن مجید میں مخلوقات کی پیدائش اور ان میں جاری نظام کے بارے میں گوناگون طریقوں سے بہت زیادہ توجہ دلائے گئی ہے اور برہان و دلائل پیش کئے گئے ہیں ، کیونکہ اکثر لوگ خاص کروہ لوگ جو فطرت کے دل فریب مظاہر کے شیفتہ ہو چکے ہیں اوروہ اپنی زندگی کی سعادت و کامیابی کو عیاشیوں و خوش گزرانیوںمیں پاتے ہیں، ا ور مادیات و محسوسات سے انس و محبت کی وجہ سے فلسفی فکر او رنظریات کی عقلی تحقیق سے محروم ہیں۔
لیکن انسان ہر حالت میں عالم ھستی کا ایک جزو ہے اور کائنات کے دیگر اجزاء اور اس میں جاری جزئی او رکلی نظاموں سے ایک لمحہ بھی بے نیاز نہیں ہے، اور ہر لمحہ اپنے ذہن کو عالم ھستی اور اس میں جاری نظام کی طرف متوجہ کر سکتا ہے ، اور کائنات کے خالق کے وجود کو پاسکتا ہے۔ خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتاہے:
( اِنَّ فی السمٰوات و الارض لَایٰتٍ للمومنین، و فی خلقکم و ما یبثُّ من دابّة آیٰت لقوم یوقنون و اختلاف الّیل و النّهار و ما انزل اللّه من السمآء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الریح ء اٰیٰت لقوم یعقلون ) (جاثیہ٣۔٥)
''بیشک آسمانوں او رزمینوں میں صاحبان ایمان کے لئے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور خود تمہاری خلقت میں بھی او رجن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہنا ہے ان میں بھی صاحبان یقین کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔اور رات دن کی رفت و آمدہیں او رجو رزق خدانے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کے ذریعہ سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایاہے اور ہواؤں کے چلنے میں اس قوم کے لئے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔''
مثال اورو ضاحت
قرآن مجیدمیں آیتیں ہیں،جن میں انسان کو چاند،ستاروں،زمین ،آسمان ،سورج ،پہاڑوں، دریاؤں،نباتات، حیوانات او رخودانسان کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا جو حیرت انگیز نظام ہے اس کی یاددہانی کرائی گئی ہے۔
حقیقت میں کائنات کا نظام ، جو کائنات کی گوناگون سرگرمیوں کو خلقت کے مقاصد اور کائنات کے اہداف کی طرف بڑھاتاہے، وہ نہایت ہی حیرت انگیز او رتعجب خیز ہے۔ گیہوںکا ایک دانہ یا بادام کی ایک گٹھلی زمین سے اگنے کے بعد ایک پودے یا میوہ داردرخت میں تبدیل ہوجاتاہے۔ اوریہ دانہ یا گٹھلی مٹی میں قرار پانے کے بعد شگافتہ ہو کراس کی سبز نوک باہر نکلتی ہے اور اس میں جاتی ہے، جب یہ پودا اپنے مقصد کی منزل تک پہنچتا ہے تو اس دوران مختلف ا ور عظیم نظام سرگرم ہوتے ہیں کہ جن کی عظمت و وسعت کا مشاہدہ کرکے عقل متحیر ر ہ جاتی ہے۔
ستارے، آسمان اور چمکتا ہواسورج او ردرخشان اور زمیں ہر ایک اپنی وضعی وانتقالی گردشوں او راپنے اندر پوشیدہ توانائیوں سے اور اسی طرح اس دانہ یا گٹھلی میں قرار دی گئی ، پر اسرار طاقتیں ، اور سال کے موسم، اور ان کے حالات، ابرو ہوا اور بارش ،ا ور شب و روز، گندم کے ایک پودے کے اگنے میں مدد کرتے ہیں ،اس نئے پودے کو پرورش کے لئے اپنے گہوارہ میں سلاتے ہیں ،دایااور نرسوں کے مانندایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیںیہاں تک کہ یہ دانہ اپنی بالیدگی ورشد کے آخری مرحلہ تک پہنچ جائے۔
یہی مثال انسان کے ایک نو مولودبچے کی ہے کہ جس کا نظام پیدائش ایک پودے یاکسی دوسر ی چیز کی پیدائش سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے ۔یہ خلقت کے منظم وپیچیدہ نظام کے لاکھوں بلکہ کروڑوں سا ل کی سرگر میوں کا ماحصل ہے ۔
ایک انسان کی روز مرہ کی زندگی کی گردش۔ اپنے وجود سے باہر عالم ھستی سے رکھنے والے رابطہ کے علاوہ ۔اپنے وجود کے اندر ایک حیرت انگیزنظام سے نشاط سے مربوط ہے کہ دور اندیش سائنسدانوں کی فکریں صدیوں سے مسلسل ان کے ظاہر کا مشاہدہ کرنے میں سر گرم عمل رہی ہیں اور ہر روز ان اسرار سے پردہ اٹھا یا جاتا ہے اور ابھی بھی ان کی معلو مات مجہو لات کی نسبت بہت کم ہیں ۔
قرآن مجید کی نظر میں خداشناسی کا طریقہ
جس شیر خوار بچہ نے دودھ پینے کے لئے ماں کا پستان پکڑرکھا ہے اور دودھ پی رہا ہے، حقیقت میں وہ دودھ چاہتا ہے ،اس کے علاوہ اگر کسی چیز کو ہاتھ میں اٹھا تا ہے تواسے کھانے کے لئے اپنے منہ تک لے جاتا ہے ،در اصل اس چیز کو اس نے کھانے کے لئے اٹھا یا تھااور جو ں ہی احساس کرتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اٹھائی ہوئی چیز کھانے کی نہیں ہے ،تو اسے پھینک دیتا ہے ۔
اسی تر تیب سے ،انسان جس مقصد کے پیچھے دوڑتا ہے ،اصل میں وہ حقیقت کو چاہتا ہے، اگر اس کے لئے واضح ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے اور غلط راہ پر چلا ہے ،تو اپنی غلطی اور خطاسے ناراض ہو تا ہے اورغلط مقصد کی راہ کی محنت پر افسوس کرتا ہے اور مختصر یہ کہ انسان ہمیشہ اشتباہ اور خطا سے پر ہیز کرتا ہے اور حتی الامکان حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ۔
یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطرت اور جبلت کی رو سے حقیقت پسند ہے ، یعنی لامحالہ ہمیشہ حقیقت کی جستجو اور حق کی پیروی کرنے والا ہو تا ہے ،اس نے اس فطری عادت کو کسی سے یاد اور کہیں سے نہیں سیکھا ہے ۔
انسان اگر کبھی سخت رویہ اختیار کر کے حق کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا ہے ،وہ اس لئے ہے کہ وہ خطا واشتباہ سے دو چار ہوتا ہے اور حق و حقیقت اس کے لئے واضح نہیں ہوتی ہے اگر اس کے لئے حق واضح ہو تاتو غلط راستہ پر نہ چلتا ۔
کبھی انسان نفسانی خواہشات کی پیروی میں ایک قسم کی دماغی بیماری سے دو چار ہوتا ہے اور حق کی شیرینی کا مزہ اس کے منہ میں کڑوا بن جاتا ہے ،اس وقت حق کو جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی نہیں کرتا ہے ۔اس کے باوجود کہ وہ حق کی حقانیت اور یہ کہ اسے اس کی پیروی کرنی چاہئے ،کااعتراف کرتا ہے ،لیکن اسکی اطاعت کرنے سے سر کشی کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے اتفاقات بھی ہو تے ہیں کہ انسان مضر اورنقصان دہ چیزوں کا عادی ہو کر ،اپنی انسانی فطرت ،جوکہ خطرہ اورضررسے محفوظ رکھتی ہے ،کو پامال کر تا ہے ،اور ایک ایسے کام کو انجام دیتا ہے ،جس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ (جیسے :سگریٹ ،شراب اور نشہ آور چیزوں کے عادی لوگ )قرآن مجید انسان کو حق پسندی اور حق کی پیروی کر نے کی دعوت دیتا ہے اور اس سلسلہ میں زیادہ تاکید کرتا ہے اور گوناگون بیانات کے ذریعہ انسان سے درخواست کرتا ہے کہ حق پسندی اور حق کی پیروی کی فطرت کو اپنے اندر زندہ رکھے۔
خدائے متعال فرماتا ہے:
( فماذا بعد الحق الا الضلل ) ۔ (یونس٣٢)
''اورحق کے بعد ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے ۔''
( والعصر انّ الانسان لفی خسر الّا الذین ء آمنوا وعٰملوا الصّٰلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر ) (عصر ١۔٣)
''قسم ہے عصر کی ،بیشک انسان خسارہ میں ہے ۔علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کئے اور ایک دوسرے کوحق اور صبر کی وصیت ونصیحت کی۔''
واضح ہے کہ خداوند عالم کی یہ ساری تاکید یں اس لئے ہیں کہ اگر انسان اپنی حقیقت پسندی کی فطرت کو زندہ نہ رکھے اور حق و حقیقت کی پیروی کی کوشش نہ کرے تو اپنی سعادت و کامیا بی کا پابند نہ ہو گا اور وہ نفسانی خواہشات اوراپنی مرضی کے مطابق جوچاہے گا کہے گا اور جو چاہے گا کرے گا۔ اور غلط تصورات اور خرافی افکار میں گرفتار ہو گا اور اس وقت ایک چوپایہ کی طرح اپنی راہ ( جو انسانی سر مایہ ہے) سے بھٹک کر ، ہوا و ہوس ،لا ابا لی اور اپنی نادانی کی پھینٹ چڑھ جائیگا ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( ارء یت من اتّخذ الٰهه هوٰه افانت تکون علیه وکیلا ٭ ام تحسب ان اکثر هم یسمعون او یعقلون اِنْ هم الّا کالانعام بل هم اضلّ سبیلا ) (فرقان ٤٣،٤٤)
''کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے،کیاآپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہیں ؟کیاآپ کاخیال یہ ہے ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہے؟ ہرگز نہیں یہ سب جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ گم کردہ راہ ہیں ۔''
البتہ جب انسان کی حقیقت پسندانہ فطرت زندہ ہو تی ہے اورحق کی پیروی کرنے کی عادت اس میں کارفرما رہتی ہے ،تو یکے بعد دیگرے اس کے لئے حقائق واضح ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ جس حق وحقیقت کو پالے گا اسے دل سے قبول کرے گا اور سعادت و خوشبختی کی راہ میں روزبروز آگے بڑ ھتا چلاجائے گا ۔
خداوندمتعال تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے
کمال کیا ہے؟
ایک گھر کو اس وقت کامل گھر کہہ سکتے ہیں ،جب ایک گھرانے کی ضروریات زندگی کے تمام چیزیں اس میں موجود ہوں ،چنانچہ اس میں مہمان خانہ،باو رچی خانہ ،غسل خانہ وغیرہ کے لئے کافی کمرے موجود ہوں ،جس گھر میں جس قدر یہ وسائل کم ہوں اسی قدر اسے ناقص سمجھا جائے گا ۔
اسی طرح ایک انسان میں اس کی فطری خلقت کے مطابق جن چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے ،اگر وہ سب اس میں پائی جاتی ہوں تو وہ کامل ہے ،اگر ان میں سے کسی ایک کی کمی ہو، یعنی وہ ہاتھ ،پائوں یا آنکھ سے محروم ہو تو اسی ا عتبارسے ناقص سمجھا جائے گا ۔
لہذامذکورہ بیان سے معلوم ہواکہ صفت کمال وہ چیز ہے کہ جو خلقت کی ضرور توںکو پیداکرتی ہے اوراس کے نقص کو دو ر کرتی ہے ،علم کی صفت کے مانند کہ جہل کی تاریکی کو دور کر کے عالم کے لئے معلوم کو واضح کردیتا ہے اور'' قدرت''کہ صاحب قدرت شخص کے مقاصد اور ا غراض کو ممکن بنادیتی ہے اور اسے ان پر مسلط کر دیتی ہے ا یسے ہی دوسرے صفات ہیں جیسے صفت حیات وغیرہ ۔
ہماراضمیر فیصلہ کر تا ہے کہ خالق کائنات ( جو ھستی عالم اور مخلو قات عالم کا سر چشمہ ہے، ہر فرض کی گئی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور ہر نعمت وکمال کو فراہم کرتا ہے) تمام صفات کمال کا مالک ہے ، کیونکہ ایک حقیقت پسندنظر کے مطابق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی شخص ا یسی نعمت کسی کو بخش دے جوخودنہ ر کھتاہویا جس عیب میں وہ خود مبتلا ہو دوسروں سے اس کو دور کرے۔خدائے متعال اپنے کلام پاک میں اپنے تمام صفات کمال کی ستائش کرتا ہے اور خود کو ہر قسم کے عیب ونقص سے پاک ومنزہ قرار دیتاہے:
( وربّک الغنیّ ذوالرّحمة ) (انعام ١٣٣)
''تیرا پروردگار بے نیاز اور مہر بان ہے''
( اللّه لا اله الّاله هوله الاسما ء الحسنی ) (طہ ٨)
''وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے،اس کے لئے بہترین نام ہیں ۔''
وہ زندہ، عالم،د یکھنے والا،سننے والا،قادر،خالق اور بے نیاز ہے ، پس خدائے متعال کو تمام صفات کمال کا مالک اور اس کی ذات اقدس کو ہر صفت نقص سے پاک و منزہ جاننا چاہئے ،کیونکہ اگر اس میں نقص ہو تا تو اسی لحاظ سے نیاز مند ہوتا اور اس اعتبارسے اس سے بالاتر کسی اور خدا کو ہونا چاہئے تھا جو اس کی نیاز مندی کو دور کر سکتا ۔
( سبحانه وتعالی عمّا یشرکون ) (یونس ٥)
''وہ پاک و پاکیزہ ہے اور ان کے شرک سے بلند وبرتر ہے''
توحید اور یکتائی
( لوکان فیهما آلهة الّا اللّه لفسد تا ) (انبیاء ٢٢)
'' یاد رکھو اگر زمین وآسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں بر باد ہو جاتے۔''
وضاحت
اگر کائنات پر کئی خدائوںکی حکومت ہوتی ،جیسا کہ بت پرست کہتے ہیںکہ کائنات کے ہر شعبہ کاایک الگ خدا ہے ۔ز مین وآسمان اور دریا و جنگل کا الگ الگ خدا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کائنات کی ہر جگہ پر خدائوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے الگ الگ انتظام بر قرار ہو تا اور اس صورت میں کائنات کا کام لامحالہ تباہی وبر بادی سے دوچار ہوتا ،چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے تمام اجزاء آپس میں ھم آہنگ اور مکمل طور پر موافق ہیں اور سب مل کر ایک نظام کو تشکیل دیتے ہیں ،اس بناپر، کہنا چاہئے کہ خالقِ کائنات ایک سے زیادہ نہیں ہے۔
یہاں پر یہ تصور نہیں کرنا چاہئے کہ فرض کئے گئے خدا، چونکہ عاقل ہوں گے اور وہ جانتے ہوں گے کہ ان کا اختلاف کائنات کو تباہی وبربادی کی طرف لے جائے گا،لہذا وہ ہر گز آپس میں اختلاف نہیں کریں گے ،کیونکہ اس صورت میں وہ ایک دوسرے کے کام میں مؤثر ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کی موافقت اور اجازت کا محتاج ہو گا اور اکیلے ہی کوئی کام انجام نہیں دے سکتا ۔ جب کہ خدائے تعالی کو ا حتیاج سے منزہ وپاک ہونا چاہئے ۔
خدائے متعال کا وجود،قدرت اور علم
اس وسیع وعریض کائنات کے آپس میں ملے ہوئے اجزاء ،اور اس کی عام اورحیرت انگیز گردش، اور کائنات کے گوشہ وکنار میں جاری، آپس میں مرتبط اور آنکھوں کو خیرہ دینے والے جزئی نظام اور نتیجہ کے طور پر مختلف انواع کے مظاہر اپنے خاص مقصد کی طرف، انتہائی نظم وتر تیب کے ساتھ حرکت میں ہیں ،یہ نظم ہر عقلمند انساں کے لئے واضح کر دیتا ہے کہ عالم ھستی اور جو کچھ اس میں ہے اپنے وجود وبقا کے لئے ایک لا فانی وجود سے متصل ہیں ،جس نے اپنی لا محدود قدرت و علم سے کائنات اور کائنات میں مو جود ہر شئے کو خلق کیا ہے اوراپنی ہر مخلوق کو پرورش کے گہوارہ میں قرار دیا ہے اور اپنی خاص عنایتوں سے ان کے مطلوب کمال کی طرف ابھار تا ہے ِیہ وہی ہے جس کی ھستی لافانی ہے اور ہر چیز کو جانتاہے اور اس پر قادر ہے،خدائے متعال فرماتا ہے :
( له ملک السمٰوات والارض یحی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر٭هوالاوّل والاٰخر والظّاهر والباطن وهو بکل شی ء علیم ) (حدید٣٢)
''آسمان وزمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی حیات وموت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے ۔وہی اول ہے وہی آخر وہی ظاہر ہے وہی باطن اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔''
خدا کی قدرت
( وللّه ملک السمٰوات والارض وما بینهما یخلق ما یشآء واللّه علی کل شی ء قدیر ) ( مائدہ ١٧)
''اور اللہ ہی کے لئے زمین وآسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے۔وہ جیسے بھی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہرشے پر قدرت رکھنے والا ہے ''
وضاحت
جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص موٹر کار خرید نے کی قدرت رکھتا ہے ،تو ہمارا مقصد یہ ہو تا ہے ،کہ جو موٹر کار خرید نے کا محتاج ہے اس کے پاس اس کے خریدنے کی مالی طاقت ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص بیس کلو گرام وزنی پتھر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے ،تو ہمارا مقصد یہ ہو تا ہے کہ اس میں بیس کلو گرام پتھراٹھانے کی طاقت موجود ہے ۔
حقیقت میں ،کسی چیز پر توانائی و قدرت ر کھنے کے یہ معنیٰ ہیں کہ اس کے تمام ضروری وسائل اس کے پاس ہیں،اور چونکہ عالم ھستی میں جس وجود کو بھی فرض کیاجائے ،اس کی نیاز مندی اور زندگی کی گردش کی ضرورت خدا کے وجود سے پوری ہوتی ہے ،یہ کہنا چاہئے کہ خدائے متعال ہر چیز کی قدرت و توانائی رکھتا ہے اور اسی کی ذات پاک کائنات کا سر چشمہ ہے۔
خدا کا علم
)( لا یعلم مَن خلق ) ۔ (ملک١٤)
''کیاپیداکرنے والا نہیں جانتا ہے؟''
وضاحت
چونکہ ہرمخلوق اپنی پیدائش وھستی میں خدائے متعال کی لا محدود ذات کی محتاج ہے،اس لئے اس مخلوق اور خدا کے درمیان پردے اور رکاوٹ کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے یا اس کا خداسے پو شیدہ ہونا تصور نہیں کیا جاسکتا،بلکہ اس کے لئے ہر چیز آشکار ہے اور ہر چیز کے داخل وخارج پر تسلّط اور احاطہ کرتا ہے۔
خداکی رحمت
جب ہم ایک ناتوان محتاج کو دیکھتے ہیں ،تو اپنی توانائی کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں ،یاکسی مصیبت زدہ بے چارہ کی مدد کرتے ہیں یاایک نابینا کاہاتھ پکڑ کر اسے اس کی منرل مقصود تک پہنچاتے ہیں ۔ایسے کاموں کو ہم مہر بانی اوررحمت شمار کر کے پسندیدہ اور قابل ستائش جانتے ہیں ۔
جن کاموں کو کارساز اور بے نیازخدا انجام دیتا ہے ،وہ رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنی بے شمار نعمتوں کو بخش کر سبھی کو بہرہ مند کرتا ہے اور ہر بخشش سے۔خود کسی کا نیاز مند ہوئے بغیر۔مخلوقات کی ضرورتوں کے ایک حصہ کو پورا کرتا ہے ،چنانچہ فرماتا ہے:
( وإ ن تعدوا نعمت اللّه لا تحصوها ) ۔ (ابرا ھیم ٣٤)
''اگرتم اس کی نعمتوں کو شمار کرناچاہوگے تو ہر گزشمار نہیں کرسکتے۔''
( ورحمتی وسعت کلّ شیئ ) ۔ (اعراف١٥٦)
''اور میری رحمت نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔''
تمام صفات کمالیہ
( وربّک الغنیّ ذوالرّ حمة ) ۔ (انعام٣٤ ١)
''تمہارے پروردگار بے نیاز اور صاحب رحمت ہے''
وضاحت
کائنات میں موجود ہر خوبی اورزیبائی ،جس کمال کی صفت کے بارے میں تصور کریں ،وہ ایک نعمت ہے جسے خدائے متعال نے اپنی مخلو قات کو عطا کیا ہے اور اس کے ذریعہ خلقت کی ضرورتوں میں سے کسی ایک کوپورا کیا ہے ،البتہ اگر وہ خود اس کمال کا مالک نہ ہوتا ،تو اس کمال کو دوسروں کو بخشنے میں عاجز ہوتا اور خود بھی ضرورتوں میں دوسروں کا شریک بن جاتا ،پس خداوند عالم کے تمام صفات کمال خود اسی کے ہیں اور اس نے کوئی کمال کسی دوسرے سے حاصل نہیں کیا ہے اور اس نے کسی کے سامنے دست نیاز دراز نہیں کیا ہے، بلکہ خود تمام صفات کمال ،جیسے:حیات، علم ،قدرت وغیرہ کا مالک ہے اورتمام صفات عیب اورنیاز مندی واحتیاج کے اسباب جیسے:ناتوانی ،نادانی ،موت،گرفتاری وغیرہ سے پاک ومنزہ ہے ۔
٢۔نبوت
انسان کوپیغمبر کی ضرورت
خدائے متعال نے اپنی کامل قدرت سے جو کہ ہراعتبار سے بے نیاز ہے کائنات اور کائنات میں گوناگوں مخلو قات کو خلق کیا اور انھیں بیشمار نعمتوں سے نوازا ہے۔
انسان اورتمام دوسری جان دار وغیر جان دار مخلو قا ت کی پرورش پیدائش کے دن سے لیکر کائنات کے آخری دن تک ،خدا ہی کرتا ہے ،اور ان میں سے ہر ایک ،خاص نظم و نسق اور خاص تربیت سے ایک معلوم و معین مقصد کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور اسی کی طرف بڑ ھتے ہیں جبکہ تمام لمحات میں وہ اپنی شایان شان عنایتوں سے نوازے جاتے ہیں ۔
اگرہم صرف اپنی زندگی کے بارے میں غور وخوض کریں ،یعنی شیرخوارگی ،بچپن ،جوانی اور بوڑھاپے کے دورپر نظر ڈالیں ،تو خدائے متعال کا وہ کامل لطف و کرم جو ہمارے شامل حال ہے، کے بارے میں ہماراضمیر گواہی دے گا ،اور جب یہ مسئلہ ہمارے لئے واضح ہو جائے گا تو یقینا ہماری عقل فیصلہ دے گی کہ خالق کائنات ،اپنی مخلوق کے لئے سب سے زیادہ مہر بان ہے ۔اسی مہربانی کی وجہ سے ہمیشہ ان کے حالات کے مطابق مصلحت کی رعایت کرتا ہے اور حکمت و مصلحت کے بغیر ہر گز ان کے فساد وتباہی کے کاموں سے راضی نہیں ہوتا ۔انسان،خدا کی ایک ایسی مخلوق ہے ۔کہ جس کی فلاح و بہبود اور سعادت اس میں ہے کہ حقیقت پسنداور نیک منش ہو ،یعنی اس میں صحیح عقائد ،پسندیدہ اخلاق اور نیک کردار ہونا چاہئے۔
ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی خدا داد عقل سے اچھے اور برے کو پہچان سکتا ہے اور چاہ کو را ہ سے تشخیص دے سکتا ہے ،لیکن یہ جاننا چاہئے کہ عقل اکیلے ہی اس گرہ کو کھول کر انسان کی حقیقت پسندی اور نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی ،کیونکہ انسانی معاشرے میں جو مشاہدہ کیا جارہا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر برائیاں ان لوگوں سے انجام پارہے ہیں ،جو عقل و شعور اور برے بھلے کی تمیز رکھتے ہیں ،لیکن خود پرستی ،منا فع پر ستی اور ہوس رانی کے نتیجہ میں ان کی عقل اس کے جذبات اور ہواوہوس کی تابع ہو کرگمراہی سے دوچار ہو تی ہے ۔لہذا خدائے متعال کوایک دوسرے راستہ سے یا ایک ایسے وسیلہ سے سعادت کی طرف ہماری راہنمائی کرنا چاہئے جو کبھی ہوا وہوس سے مغلوب نہ ہواور اپنی رہبری میں کبھی اشتباہ و غلطی کاشکارنہ ہو،ایسا راستہ صرف نبوت کا ہے۔
انبیاء کی تبلیغ
ہماری عقل جو فیصلہ کرتی ہے اوراس کے مطابق حکم دیتی ہے کہ انسان کے لئے ''نبوت'' کے نام کا ایک راستہ کھلا ہونا چاہئے ۔ یہ چیزعملابھی مورد تاکید قرار پاکر انجام پایا ہے۔ انسانوں میں سے (انبیائ)نامی کا ایک گروہ خدائے متعا ل کی طرف سے منتخب ہوا ہے ۔ جنہوںنے لو گوںکی ہدایت کے لئے اعتقادی کچھ عملی قوانین وضوابط پیش کئے اور ان کو صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دی ہے
ان پیغمبروں نے اپنے دعوی کے صحیح ہونے اوراپنے دین کے سچے ہونے کومعقول طریقوں سے لوگوں کے لئے ثابت کیا ،اور اپنے تربیتی مکتب میں کچھ شائستہ افراد کی پرورش کی ۔
عقل معاش، جسے ہم عقل علمی بھی کہتے ہیں (وہ شعورجس سے ہم اپنی زندگی کو چلاتے ہیں)ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فائدے کے لئے ہر قابل استفادہ چیز سے استفادہ کریں ،جیسے:فضا،ہوا،درختوں،ان کے پھل،پتوںاور لکڑیوں حیوانات،ان کے گوشت،دودھ ،اون اورکھال سے استفادہ کریں ۔اسی طرح ہم اپنی بے شمار ضرورتوں کے پیش نظر اپنے ہم نوع انسانوں کی سر گرمیوں سے بھی اپنے نفع میں استفادہ کرتے ہیں ۔
ان چیزوں کے مصرف اور استفادہ کا حکم ہمیں ہماری عقل و شعورنے دیا ہے اور اسی نے ان کے جائز ہونے کی تصدیق کی ہے ،اس لئے ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھوک کے وقت تم کیوں کھانا کھاتے ہو ؟ پیاس کے وقت کیوں پانی پیتے ہو؟یا ہوا میں کیوں سانس لیتے ہو؟تو اس کے یہ سوالات مضحکہ خیز ہوں گے۔
لیکن جب ہم اپنے ہم نوع انسان کے کام وکوشش سے استفادہ کرنے کے لئے ان سے پہلی بار رابطہ بر قرار کرتے ہیں تو معلوم ہوتاہے کہ وہ بھی ہماری طرح ہیں جس طرح ہم ان کی سر گرمیوں کے نتیجہ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ،اسی طرح وہ بھی ہماری سر گرمیوں کے نتیجہ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ۔کیونکہ ہم اپنی سر گرمیوں کے نتیجہ کو انھیں مفت میں دینے کے لئے تیارنہیں ہیںلہذا ان کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اسے مفت میں دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ۔
یہی وجہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک دوسرے کا تعاون کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اپنے ہم نوع انسان کی زندگی کی ضرورتوںکو پورا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ اس کے مقابلہ میں وہ بھی ہماری مدد کریں ۔
اسی احتیاج وضرورت کے پیش نظر،مختلف انسان آپس میں جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کی مدد اور کام سے استفادہ کرتے ہیں ،حقیقت میں مختلف افراد کے کام اور ان کی کوششیں ایک دوسرے پر بٹ جاتی ہیں ،اور اس کے بعدہر ایک اپنی حیثیت اور اجتماعی سر گرمی کے مطابق اس سے استفادہ کرتا ہے ۔
معاشرے میں قوانین و قواعد کی ضرورت
جیسا کہ بیان کیا جاچکا کہ انسان مجبور ہوکر اجتماعی تعاون پرآمادہ ہوتا ہے ورنہ فطری طور پر وہ صرف اپنی زندگی کے نفع کاخواہان ہے ،لہذا جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ دوسروں کے منافع پر تجاوز کرتا ہے جبکہ اس نے اپنے منافع سے کوئی چیزدوسروں کو ا نہیں دی ہے کہ تعادل بر قراررہے ۔اسی لئے ہر معاشرے میں کچھ قوانین ومقررات کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی رعایت کرنے سے ،انسان کی اجتماعی قدروقیمت محفوظ رہے،اور ان کو تجاوز کر نے سے رو کا جا سکے۔ قوانین وضوابط کو لوگوں کے اتفاق نظر یا ان کی اکثریت کی رائے سے منطور کیا جانا چاہئے تاکہ ہر فرد اپنے انفرادی واجتماعی فرائض سے آگاہ ہو جائے۔
قواعدوضوابط کی تکوینی بنیاد
قوانین وضوابط ایسے فرائض ہیں جو انسانی زندگی کی مصلحتوں کی حفاظت کے لئے وضع ہوئے ہیں ۔اس لحاظ سے ان کی قدروقیمت اجتماعی ہے نہ فطری وتکوینی ۔یعنی فطرت میں حکم فرماقوانین کا خودبخود کوئی اثر نہیں ہے ،بلکہ جب معاشرے کے لوگ انھیں جاری کر تے ہیں تو یہ جاری ہوتے ہیں ورنہ یہ ایک بے اثر افسانہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔
اس کے باو جود یہ قوانین وضوابط ،فطرت وتکوین سے بے ربط بھی نہیںہیں،بلکہ ان میں تکوین کی ا صل موجود ہے ۔ فطرت اورانسان کی فطری ضرورت ان کاسرچشمہ ہے .یعنی خدائے متعال نے انسان کی خلقت کچھ اس طرح کی ہے کہ خواہ نخواہ اجتماعی افکار کے ایک سلسلہ کو وجودمیں لاکر انھیں قابل استفادہ قرار دیتا ہے اور اپنی تکوینی زندگی کو ان پر تطبیق کرتا ہے اور اپنے وجودی مقاصد تک پہنچتا ہے۔
زندگی کے قوانین کی طرف تکو ینی ہدایت
ہم جانتے ہیں کہ خدائے متعال اپنی عنایت کاملہ اور بے پناہ محبت کی بدولت اپنی ہر مخلوق کواس کے وجودی مقصد تک پہنچاتا ہے اور انسان بھی اس قانون سے مستثنی نہیں ہے ،پس خدائے متعال کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے لئے کچھ ایسے قوانین وضوابط وضع کر ے جو اس کی زندگی کی راہ ورسم کو تشکیل دے اور ان پر عمل کے ذریعہ ا نسان کی مصلحتیں اور منافع پورے ہو سکیں اوران کو حاصل کرنے کے لئے صرف عقل کافی نہیں ہے ۔کیونکہ کبھی خودعقل بھی درک کرنے میں خطا کرتی ہے اور اکثر اوقات عقل عادت ،تقلید اور وراثت میں ملی صفات سے متاثر ہوکر ہواوہوس سے مغلوب ہو کر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے ۔جیسا کہ ہم جان چکے کہ،عقل انسان کو منافع طلبی کے قانون کی طرف رہنمائی کرتی ہے ،اور اگر انسان کبھی دوسروں کے لئے حق کا قائل ہوتا ہے اور عام قانون کی پیروی کرتا ہے،تو وہ بنابر مجبوری اور اپنے شخصی منافع کو حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے ،اسی وجہ سے اکثر لوگ جب قدرت و توانائی کے عروج پر پہنچتے ہیں تو اپنے مقابلہ میں کسی حریف اور مخالف کو کچھ نہیںسمجھتے ،ہر قانون وحکم کی سر کشی کرتے ہیں اور دوسروں کے منافع کو اپنے لئے مخصوص کر اتے ہیں اور ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں ۔
لہذا خدائے متعال کو چاہئے کہ لوگوں کو ان کی زندگی کی راہ و رسم کے بارے میں ایک ایسے طریقہ سے راہنمائی کرے،جو ہرقسم کی خطاولغزش سے محفوظ ہو اور وہ طریقہ (نبوت)ہے،اور وہ یہ ہے کہ خدائے متعال اپنے بعض بندوں کو راہ فکر وعقل کے علاوہ ایک اور راہ (راہ وحی )سے معارف واحکام کے ایک سلسلہ کی تعلیم دے تا کہ ان پر عمل کے ذریعہ لوگوں کی حقیقی سعادت کی طرف رہنمائی کرسکے۔
نتیجہ
مذکورہ بیان سے معلوم ہوا کہ خدائے متعال کو چاہئے کہ اپنے بعض بندوں کو غیبی تعلیم کے قوانین سے آگاہ کر کے بھیجے جو انسانی سعادت کے ضامن ہیں ۔خدا کے پیغام لانے والے انسان کو پیغمبر یا خدا کارسول کہتے ہیں ،اور خدا کی طرف سے لائے گئے پیغامات کے مجموعہ کو''دین ''کہتے ہیں ۔
یہ بھی معلوم ہواکہ خداکی طرف سے بھیجے گئے دینی معارف اور الٰہی قوانین کوصحیح طور پرتبدیلی،اور کمی بیشی کے بغیر لوگوں کے پاس پہنچنا چاہئے ۔یعنی خدا کا پیغمبروحی الہی کو حاصل کرنے میں خطا نہ کرے اوراس کی حفاظت میں بھول چوک اور لغزش سے دو چارنہ ہو اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں غلطی یا خیانت نہ کرے۔جیساکہ ہم نے بیان کیا کہ ضروری معارف اورزندگی کے قوانین کی طرف لوگوں کی ہدایت نظام خلقت کا جزو ہے اور یہ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔خلقت اپنی راہ کو طے کرنے میں ہر گزخطااور لغزش کو قبول نہیں کرتی ،مثال کے طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ نظام خلقت ،انسان کے تناسل سے ایک پتھر یا پودے کو وجود میں لائے یا گیہوں کے دانہ کو بونے کے بعد ایک حیوان پیدا ہو یا انسان کی آنکھ موجودہ حالت میں معدہ کا کا م انجام دے یا کان دل کا کام انجام دے۔
اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے انبیاء کو معصوم ہونا چاہئے ۔یعنی جس کا م کو وہ خود واجب جانتے ہو ں اسے ترک نہ کریں اور جس کام کو وہ خود گناہ جانتے ہوںانہیں انجام نہ دیں ، کیونکہ ہم (انسان)اپنے ضمیر سے جانتے ہیں کہ جو اپنی بات پر عمل نہ کرے، حقیقت میں وہ اس بات کے صحیح اور سچ ہونے کا قائل نہیں ہے ۔اس صورت میں اگر پیغمبر گناہ کا مرتکب ہو جائے ،تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گااور تبلیغ کا مسئلہ بے اثر ہوگا اور اگر بعد میں توبہ اور اظہارندامت بھی کرتا ہے تو بھی ہمارا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوگا اور ہر حالت میں تبلیغ کا مقصدفوت پر جائے گا ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احداً٭الّا من ارتضی من رسول فانّه یسلک من بین یدیه ومن خلفه رصداً٭ لیعلم ان قد ابلغوا رسٰلت ربّهم ) (جن ٢٨٢٦)
''وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ۔مگر جس رسول کو پسند کر لے تواس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کردیتا ہے ،تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے ۔''
انسان اور دوسری مخلو قات کی ہدایت میں فرق
توحید کی بحثوں سے واضح ہو تا ہے کہ اشیاء کی تخلیق خدا کی طرف سے ہے ،لہذا ان کی پرورش بھی اسی سے مربوط ہے۔واضح الفاظ میں یہ کہا جائے کہ کائنات کی ہر مخلوق ،اپنی پیدائش کے آغاز سے اپنی بقااور نقائص کو دور کرنے میں سر گرم عمل ہوتی ہے اورا اپنی کمیوں وضرورتوں کو یکے بعد دیگررفع کرتی ہے اور امکان کی حدتک اپنے آپ کو کامل اور بے نیاز کرتی ہے ۔اپنی بقاکے سفر میں ایک منظم حرکت کے تحت اپنے وجود کو جاری رکھتی ہے ،اس سفر کو منظم کرنے والا اور ہر منزل پر اسکا رہبر خدائے متعال ہے۔
اس نظریہ کے مطابق ایک قطعی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر قسم کی مخلوق ایک خاص تکوینی پرو گرام کے تحت باقی ہے اور اس میں اپنی خاص سر گرمی ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ،کائنات کے مظاہر میں سے ہر معیّن گروہ کے لئے ، اپنی بقا کے سفر میں کچھ معیّن فرائض ہیں جو خدائے متعال کی طرف سے انھیں عطا ہوتے ہیں ۔ چنانچہ قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:
( ربّنا الّذی عطی کلّ شی ئٍ خلقه ثمّ هدی ) (طہ٥٠)
''...ہمارارب وہ ہے جس نے ہرشے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اورپھر ہدایت بھی دی ہے ''
خلقت کے تمام اجزااس کلی حکم میں شامل ہیں اور ان میں سے ہر گز کوئی مستثنیٰ نہیں ہے آسمان کے ستارے اورہمارے پیروں تلے زمین اور ان میں موجود عناصر اور ابتدائی مظاہر کو ظاہر کرنے والی تر کیبیں اورنباتات وحیوانات ،سبھی کی یہی حالت ہے ۔اس عام ہدایت میں انسان کی حالت بھی دوسری مخلوقات کے مانند ہے ، سوائے یہ کہ انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان ایک فرق ہے۔
انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق
مثال کے طور پر کرئہ زمین کو لاکھوں سال پہلے خلق کیاگیا ہے ،جو اپنی تمام پوشیدہ توانائیوں کو استعمال میں لاکرا پنے دائرہو حدود میں جب تک مخالف عوامل مانع نہیں ہوتے اس وقت تک سرگرم عمل ہے اوراپنی وضعی وانتقالی حرکت کے نتیجہ میں اپنے وجودی آثار کو ظاہر کرتا ہے اور اس طرح اپنی بقا کی ضمانت حاصل کرتا ہے اور جب تک کوئی اس سے قوی مخالف عامل رکاو ٹ نہ بنے ،اسی سر گرمی کو جاری رکھے گا ،اور اپنے فرائض کو نبھانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا ۔
بادام کا درخت گٹھلی سے باہر آنے کے وقت سے کامل درخت کی صورت اختیار کرنے تک،تغذیہ ،رشدونمو وغیرہ میں ،دوسرے الفاظ میں اپنے تکامل کے سفر کی راہ میں کچھ فرائض انجام دیتا ہے کہ اگر کوئی قوی تر مخالف عامل رکاوٹ نہ بنے تواپنے فرائض کو انجام دینے میں ہرگز کوتاہی نہیں کریگا اورکوئی کوتاہی کر بھی نہیں سکتا۔ہردوسری مخلوق کی بھی یہی حالت ہے ۔لیکن انسان ،اپنی خصوصی سر گرمیوں کو اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے اور جو کام انجام دیتا ہے ،اس کا سرچشمہ اس کی فکر اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے ۔ممکن ہے انسان کبھی ایک ایسے کام کو انجام دینے سے پہلو تہی کرے ،جو سو فیصدی اس کے نفع میں ہوا ور کوئی مخالف عامل بھی رکاوٹ نہ بنے اور اس کے مقابلہ میں ایک ایسے کام کوجان بوجھ کر انجام دے جس میں سوفیصدی ضرراورنقصان ہو ،مثلا کبھی دوائی کھانے سے پرہیز کرتا ہے اورکبھی جام زہر نوش کرکے خودکشی کرتا ہے ۔
البتہ واضح ہے کہ جو مخلوق مختار پیداکی گئی ہے ہو،عام ہدایت اس کے لئے جبری نہیں ہوگی۔یعنی انبیاء ،خیر وشر اورسعادت و بدبختی کی راہ کو خدائے متعال کی طرف سے لوگوں کو بیان کرتے ہیں اوردین کے پیرئوں کو ثواب کا مژدہ سناکر پروردگار کی رحمت سے امیدوار بناتے ہیں سرکشوں اورباغیوں کو خدا کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور وہ ان میں سے ہر ایک کو اختیار کرنے میں آزادومختار ہوں گے ۔
صحیح ہے کہ انسان اپنے خیروشراور نفع ونقصان کو اجمالا عقل سے سمجھتا ہے۔لیکن یہی عقل، اکثراوقات اپنے کو گم کر کے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتی ہے ،اور کبھی غلط راستہ پر چلتی ہے لہذاخدا کی ہدایت عقل کے علاو ہ کسی اور راستہ سے بھی انجام پانی چاہئے اور وہ اس راستہ کو خطاولغزش سے با لکل محفوظ ہونا چاہئے ۔یا دوسرے الفاظ میں خدائے متعال اپنے احکام کواجمالی طور پرعقل سے لو گوں کو سمجھاتا،اور ایک دوسر ے راستہ سے اس کی تصدیق فرماتا ۔
یہ راستہ،وہی ''نبوت''کا راستہ ہے کہ خدائے متعال اپنے سعادت بخش احکام کو وحی کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو سمجھاتا ہے اور اسے مامور کر تا ہے کہ انھیں لوگوں تک پہنچائے اور انھیں امید و خوف کے ذ ریعہ شوق دلاکراور ڈراکر ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مجبور کرے۔خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے:
( انّا وحینا لیک کما وحینا الی نوحٍ و النّبیّن من بعدهرسلاً مبشّرین ومنذرین لئلا یکون للنّاس علی اللّه حجّة بعد الرّسل ) (نسائ١٦٥١٦٣)
''ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعدکے انبیاء کی طرف وحی کی تھی ...یہ سارے رسول بشارت دینے والے اورڈرانے والے اس لئے بھیجے گئے تاکہ رسولوںکے آنے کے بعد انسانوں کی حجت خداپر قایم نہ ہونے پائے ''
پیغمبر کی صفات
مذکورہ بیان سے واضح ہواکہ پیغمبر میں حسب ذیل صفات ہونی چاہئیں :
١۔اپنے فریضہ کو انجام دینے میں خطاسے محفوظ اور معصوم ہونا چاہئے اور ہر طرح کی فراموشی اور دوسری ذہنی آفتوں سے بھی محفوظ ہونا چاہئے تاکہ جو چیز اس پر وحی ہوتی ہے اس کو صحیح طورپر حاصل کر کے ،کسی لغزش وغلطی کے بغیر لوگوں تک پہنچا دے ،کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو الہی ہدایت اپنے مقصدتک نہیں پہنچ سکتی اور عام ہدایت کا قانون اپنی کلی حیثیت کو کھو کر انسان پر اثر انداز نہیں ہوسکتاہے۔
٢۔پیغمبر کو اپنے کردار وگفتار میں لغزش اور گناہ سے محفوظ ہونا چاہئے چونکہ گناہ کی صورت میں تبلیغ مو ثّر واقع نہیں ہوتی ،جس کے قول وفعل میں اختلاف ہو ،لوگ اس کے قول کو قابل قدر نہیں جانتے حتی اس کے کردار کو بھی جھوٹ کی دلیل سمجھ کر کہتے ہیں: (اگروہ سچ کہتا تووہ اپنی بات پر عمل کرتا)
ان دو مطالب کو ایک عبارت میں جمع کیا جاسکتا ہے :تبلیغ کے صحیح وموئثّرواقع ہونے کے لئے پیغمبرکا خطا اور معصیت سے معصوم ہونا ضروری ہے ،جیسا کہ قرآن مجید کی دلیل بھی بیان کی گئی ۔(۱)
٣۔پیغمبرکواخلاقی فضائل کا مالک ہونا چاہئے،جیسے:عفت،شجاعت،عدالت وغیرہ کیونکہ یہ سب پسندیدہ صفات شمار ہوتی ہیں اور جو ہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہو اور دین کی مکمل طور پر اطاعت کرتا ہو اس کا دامن کبھی اخلاقی ،برائیوں سے داغدار نہیں ہو سکتا ۔
انبیاء ،انسانوں کے درمیان
تاریخ کی رو سے مسلّم ہے کہ لوگوں کے درمیان کچھ پیغمبر تھے جنہوں نے دعوت کے ذریعہ انقلاب برپا کیا ہے ،لیکن پھر بھی ان کی زندگی کے بارے میں تاریخ زیادہ واضح نہیں ہے ۔صرف حضرت محمدمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تاریخ میں کسی طرح کا ابہام نہیں ہے ۔اورقرآن مجید،جو آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی آسمانی کتاب ہے اور اس میں آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے دین کے عالی مقاصد درج ہیں ،گزشتہ انبیاء کی دعوت کے موضوع کو بھی واضح کرتا ہے اور ان کے مقاصد کو بھی بیان کرتاہے ۔
قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ خدائے متعال کی طرف سے بہت سے انبیاء ر لوگوں کی طرف آئے ہیں اور انہوں نے متفقہ طور پر توحید اور دین کی دعوت کی ہے،چنانچہ فرماتاہے :
( وماارسلنا من قبلک من رّسول الّانوحی الیه انّه لااله الّا انا فاعبدون ) ( انبیائ٢٥)
''اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدانہیںہے ،لہذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو۔''
صاحب شریعت انبیائ
قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ خدا کے سارے نبی آسمانی کتاب کے حامل نہیںتھے اور نہ ہی مستقل شریعت لے کر آئے تھے ۔خدائے متعال فرماتا ہے:
( شرع لکم من الدّین ماوصّی به نوحاً والّذی وحینا الیک وما وصّینا به ابرهیم و موسٰی وعیسٰی ) (شوریٰ ١٣)
''اس نے تمھارے لئے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح کوکی ہے اور جس کی وحی پیغمبر!تمھاری طرف بھی کی ہے اور جس کی نصیحت ابراہیم ،موسی اور عیسی کوبھی کی ہے ...''
اس بناپر بڑے انبیاء میں سے پانچ نبی جو صاحب شریعت اور آسمانی کتابوں کے حامل تھے،حسب ذیل ہیں :
١۔حضرت نوح علیہ السلام
٢۔حضرت ابراہیم علیہ السلام
٣۔حضرت موسی (کلیم)علیہ السلام
٤۔حضرت عیسی(مسیح)علیہ السلام
٥۔حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان انبیاء میں سے ہر ایک کی شریعت اپنے گزشتہ نبی کی شریعت کو مکمل کرنے والی تھی ۔
اولوالعزم پیغمبر اور دوسرے انبیائ
ہم یہ بیان کر چکے کہ جو پیغمبر آسمانی کتاب اور مستقل شریعت لے کر آئے تھے وہ پانچ ہیںلیکن خدا کے رسول صرف یہی پانچ افراد نہیں تھے ،بلکہ ہر امت کا ایک نبی تھا اورخدا کی طرف سے لوگوں کے لئے بہت سے انبیاء بھیجے گئے ہیں ،کہ ان سے میں صرف بیس افراد کا نام قرآن مجید میں موجود ہے ،چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے :
( منهم من قصصنا علیک ومنهم من لم نقصص علیک ) ۔ (غافر٧٨)
''...جن میں سے بعض کا تذکرہ آپ سے کیا ہے اور بعض کاتذکرہ بھی نہیں کیا ہے ''
( ولکلّ امّةٍ رسول ) ۔ (یونس٤٧)
''اور ہر امت کے لئے ،ایک رسول ہے۔''
( ولکلّ قومٍ هاد ) ۔ (رعد٧)
''اور ہر قوم کے لئے ایک ہدایت کر نے والا ہے...''
جی ہاں،اولواالعزم پیغمبروں میں سے ہر ایک کے بعدجتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ،انہوں نے انسانوں کو انہی پیغمبروں کی شریعت کی طرف دعوت دی ہے اور اس طرح،بعثت ودعوت کا سلسلہ جاری رہا ،یہاں تک کہ خدائے متعال نے پیغمبراکرم حضرت محمدبن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ پیغمبروں کے سلسلہ کو ختم کرنے اورآخری احکام وکامل ترین دینی ضوابط کو پہنچانے کے لئے مبعوث فرمایا اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی آسمانی کتاب کوآخری آسمانی کتاب قرار دیا نتیجہ میں ،آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا دین قیامت تک جاری رہے گااورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی شر یعت ہمیشہ کے لئے زندہ رہے گی۔
١۔حضرت نوح علیہ السلام
سب سے پہلے پیغمبرجسے خدائے متعال نے شریعت اور آسمانی کتاب کے ساتھ عالم بشریت میں بھیجا،حضرت نوح علیہ السلام تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو توحید،یکتا پرستی کی تر غیب اورشرک وبت پرستی سے پر ہیز کرنے کی دعوت دیتے تھے۔چنانچہ قرآن مجید میں ان کے قصوں سے واضح ہے کہ طبقاتی اختلافات کو ختم کرنے اور ظلم وستم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم سخت جہاد ومبارزہ کرتے تھے اوراستدلال کے زریعہ جو اس زمانہ کے لوگو ں کے لئے نیا تھا ،اپنی تعلیمات پہنچاتے تھے ۔
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے ایک طولانی مدت تک جاہل ،ضدی اور سرکش لوگوں سے دست بگریبان ہونے کے بعدایک چھوٹے گروہ کی ہدایت کی اور خدائے متعال نے ایک طوفان کے ذریعہ کفار کو ہلاک کر کے زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرمایا۔حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کچھ پیروؤں کے ساتھ نجات پانے کے بعد دنیا میں ایک نئے دینی معاشرہ کی بنیاد ڈالی۔
یہ معزز پیغمبر ،شریعت توحید کے بانی اور خدا کے پہلے کچھ مور ہیں ،کہ جنہوں نے ظلم وستم اور سرکشی کا مقابلہ کیا اور دین حق وحقیقت کی عظیم خدمت کی لہذا خدائے متعال کی طرف سے خاص درودوسلام کے مستحق قرار پائے اور رہتی دنیا تک زندہ وپائندہ رہیں گے:
( سلٰم علی نوحٍ فی العٰلمین ) (صافات٧٩)
''ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام ''
٢۔حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا ۔اور اس عرصہ میں اگر چہ بہت سے انبیاء جیسے حضرت ہود علیہ السلام ،حضرت صالح علیہ السلام اوران کے علاوہ دوسرے انبیاء لوگوںکی خدائے متعال اورحق کی طرف رہنمائی فرماتے رہے ،لیکن پھر بھی دن بدن شر ک وبت پرستی کا بازار گرم ہوتا جارہا تھا ،یہاں تک کہ تمام عالم میں بت پرستی پھیل گئی اورخدائے متعال نے اپنی حکمت سے حضرت ابراھیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فطری انسان کے ایک کامل نمونہ تھے۔ آپ نے پاک و بے آلائش فطرت سے حقیقت کے لئے جستجو کرکے خالق کائنات کی وحدانیت کو پایا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک شرک و ظلم سے لڑتے رہے۔
جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور اہل بیت کی روایتیں بھی دلالت کرتی ہیں،کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن شہر کے شوروغل سے دور ایک غار میں گزرا۔آپ کی ملاقات صرف کبھی کبھی اپنی والدہ سے اس وقت ہوتی تھی جب وہ آپ کے لئے کھانا پانی لے کر آتی تھیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ غار سے باہرنکلے اور شہر تشریف لائے ۔اور اپنے چچا آزرکے پاس گئے ،وہ جو چیز بھی دیکھتے تھے وہ ان کے لئے نئی اور حیرت انگیز ہوتی تھی ۔ان کی پاکیزہ فطرت ہزاروں حیرت وتعجب کے عالم میں بڑی بے چینی و بے تابی کے ساتھ ان چیزوں کی خلقت کی طرف متوجہ تھی جن کا وہ مشاہدہ کر تے تھے اور وہ ان کی تخلیق کے اسرارتک پہنچنے کی جستجو میں تھے،جب انہوں نے ان بتوں کو دیکھا کہ جنہیں آزر اور دوسرے لوگوں نے تراشا تھا اوروہ ان کی پرستش کرتے تھے ۔ تو انکی حقیقت کے بارے میں سوال کیا لیکن ان بتوںکے رب ہونے کے بارے میں جو وضاحت کی جاتی تھی وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔
جب حضرت ابراہیم نے کچھ لوگوں کو ستارئہ زہرہ ،کچھ لوگوں کو چاند اور کچھ لوگوں کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے پایا ،جو کہ ایک مدت کے بعد ڈوب جاتے تھے،تو آپ نے ان کے رب ہونے کو قبول نہ کیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد خدائے واحد کی پرستش اورشرک سے اپنی بیزاری کالوگوں میں بلا خوف اعلان کر دیا اور اب وہ بت پرستی اورشرک سے مقابلہ کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔بت پرستوں کے ساتھ انتھک مقابلہ کرتے اور ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے۔
آخر کارایک بت خانہ میں داخل ہوئے اوربتوںکا توڑنا ان لوگوں میں سب سے بڑا جرم شمار ہوتا تھاآپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ۔مقدمہ کی سماعت کے بعد آپ کو آگ میں جلانے کی سزا سنادی گئی،کاروائی مکمل کر نے کے بعد آپ کوآگ میں ڈال دیا گیا ،لیکن خدائے متعال نے آپ کی حفاظت فرمائی اورآپ آگ سے صحیح وسالم باہر نکل آئے ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ مدت کے بعد اپنی جائے پیدائش ملک بابل سے سر زمین شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی اور اس علاقہ میں اپنی دعوت کو جاری رکھا ۔
زندگی کے آخری ایام میں خدائے متعال نے آپ کو دوفرزند عطا کئے۔ان میں سے ایک حضرت اسحاق تھے جو اسرائیل کے والداوردوسرے اسماعیل تھے جو مصری عرب کے باپ ہیں ۔
حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو شیرخواری کے ایام میں ہی خداکے حکم سے ان کی والدہ کے ہمراہ حجاز لے جاکر تہامہ کے پہاڑوں کے بیچ میں ایک بے آب وگیاہ اور باشندوں سے خالی سر زمین میں چھوڑ دیا ،اس طرح صحرانشین عربوں کو توحید کی دعوت دی۔اس کے بعد خانہ کعبہ کی سنگ بنیاد ڈا لی اور اعمال حج انجام دینے کا تشرع فرمایا کہ اسلام کے ظہور اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تک یہ عمل عربوں میں رائج تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کی نص کے مطابق دین فطرت کے حامل تھے۔آپ وہ پہلے شخص ہیںکہ جس نے خدا کے دین کو اسلام اور اس کے پیروئوں کو مسلمین کہا ،اوردنیا میں ادیان توحیدیعنی یہودیت ،نصرانیت اور اسلام آپ پر منتہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان تینوں ادیان کے پیشواحضرت موسی کلیم ،حضرت عیسی مسیح اور حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ سب دعوت دینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے۔
٣۔حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلام
حضرت موسی بن عمران علیہ السلام تیسرے اولوالعزم پیغمبر اور صاحب کتاب وشریعت ہیں۔آپ اسرائیل (یعقوب ) کی اولاد میں سے ہیں ۔
حضرت موسی علیہ السلام کی زندگی شوروغل سے بھری ہوئی تھی ۔آپ کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل مصر میں قبطیوںکے درمیان ذلت واسیری کی زندگی گزار رہے تھے اور فرعون(۲) کے حکم سے بچوں کے سر قلم کئے جارہے تھے۔
حضرت موسی علیہ السلام کی ماں کو خواب میں جوحکم دیاگیاتھاا س کے مطابق موسی کولکڑی کے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔پانی نے صندوق کوبہا کر فرعون کے محل کے قریب پہنچادیا ۔فرعون کے حکم سے صندوق کوپانی سے نکالا گیا ، جب صندوق کو کھولا گیا تواس میں ایک خوبصورت بچے کو پایا گیا۔
فرعون نے ملکہ کے اصرار پر بچے کو قتل نہیںکیا ،اور چونکہ وہ لا ولد تھا ،لہذا اسے اپنا بیٹا بنالیا اور دایہ کے حوالہ کیا گیا اتفاق سے وہی اس کی ماں تھی۔
حضرت موسی علیہ السلام ابتدائے جوانی تک فرعون کے دربار میں تھے۔اس کے بعد ایک قتل کے حادثہ کی وجہ سے فرعون سے ڈر کر،مصرسے بھاگ کر مداین چلے گئے اور وہاں پر حضرت شعیب پیغمبرعلیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت شعیب کی ایک بیٹی سے شادی کی ۔
کئی سال تک حضرت شعیب کی بھیڑبکریوں کو چراتے رہے۔ایک دن انھیں اپنے وطن کی یادآئی۔اپنے اہل و عیال اورسازوسامان کے ساتھ راہی مصرہوئے ۔اس سفر کے دوران جب رات کے وقت طور سینا پہنچے تو خدائے متعال کی طرف سے رسالت کے عہدہ پرفائز ہوئے اورآپ کومامور کیا گیا کہ فرعون کو دین توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو قبطیوں سے نجات دلائیں اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر قرار دیں ۔
لیکن اپنے فریضہ کو انجام دینے اور پیغام الٰہی کو پہنچانے کے بعد فرعون،جوکہ بت پرست تھااورخود کو خدا کہتا تھا ،نے آ پ کی رسالت اوردعوت کو مسترد کردیا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا ضامن نہیں ہوا۔
حضرت موسی علیہ السلام نے سالہا سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بہت سے معجزے دکھائے لیکن اس کے باوجود فرعون اور اس کی قوم ان کے ساتھ سختی اور تند مزاجی کا مظاہرہ کرتی رہی۔یہاں تک کہ حضرت موسی علیہ السلام خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں مصر سے کوچ کر کے صحرائے سینا کی طرف چلے گئے۔جب وہ بحراحمر پہنچے تو فرعون کو یہ معلوم ہوگیا اور اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا ۔
حضرت موسی علیہ السلام نے معجزہ کے ذریعہ سمندر کو شگافتنہ کیا اور اپنی قوم کے ساتھ پانی سے گزرگئے ،لیکن فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوگیا۔اس واقعہ کے بعد خدائے متعال نے حضرت موسی علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور بنی اسرائیل میں کلیمی شریعت کونافذ کیا ۔
٤۔حضرت عیسی مسیح علیہ السلام
حضرت مسیح اولواالعزم اور صاحب کتاب و صاحب شریعت پیغمبروںمیں سے چوتھے پیغمبرہیں۔آپ کی پیدائش غیر معمولی تھی ۔آپ کی والدہ حضرت مریم،ایک مقدس و پارسا دوشیزہ تھیںجو بیت المقدس میں عبادت کرنے میں مشغول تھیں کہ خدا کی طرف سے روح القدس آپ پر نازل ہوئے اورحضرت مسیح کی بشارت دی پھر ان کی آستین میں پھونک مار ی کہ جس سے وہ حاملہ ہو گئیں ۔
حضرت مسیح نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں پر لوگوں کی طرف سے لگائی جانے والی تہمتوں کا جواب گہوارہ میں دیا اور اپنی والدہ کا دفاع کیا اور اپنی نبوت اور کتاب کے بارے میں لوگوں کو خبر دی۔اس کے بعد جوانی میں لوگوں کو دعوت دینے میں مشغو ل ہوئے اور حضرت موسی کی شریعت میں تھوڑی سی تبدیلی کرکے اسے زندہ کیا ۔آپ اپنے حواریوں کو اسلام کے مبلّغ کی حیثیت سے مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے ۔
ایک مدت کے بعد جب ان کی دعوت پھیل گئی ،تو یہودی(آپ کی قوم)آپ کو قتل کرنے کے در پے ہو گئے ،لیکن خدائے متعال نے آپ کو نجات دی اور یہودیوں نے آپ کی جگہ پر کسی اور کوپکڑ کر سو لی پر چڑھادیا ۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ خدائے متعال نے قرآن مجید میں حضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ''انجیل''بیان کیا ہے ،یہ ''انجیل''ان انجیلوں کے علاوہ ہے، جو آپ کے بعدآپ کی سیرت اور دعوت کے بارے میں لکھی گئی ہیں ۔ان میں سے چارانجیلیں لوقا،مرقس،متی،اور یوحنا کی تالیف رسمی طور پر قبول کی گئی ہیں ۔
____________________
١۔جن٢٨٢٦۔
۲۔مصر میں بادشاہ کو (فرعون )کہتے تھے۔
٥۔خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٥٧٠ء میں ہجرت سے ٥٣سال پہلے حجازکے ایک شریف ونجیب ترین عرب خاندان(بنی ہاشم)میں پیدا ہوئے ۔
جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں دنیا حیرت انگیز حد تک اخلاقی گر اوٹ سے دوچارتھی اور دن بدن جہل و نادانی کے بھنور میں پھنس کر اس کی حالت بدسے بدتر ہوتی جارہی تھی اور ہر لمحہ انسانی معنویات سے دور ہوتی جارہی تھی ۔خاص کر جزیرہ نمائے عر ب ،جس کے اکثر باشندے صحرانشینںتھے اور قبیلوں کی صورت میں زندگی بسر کرتے تھے ،تمام شہری حقوق سے محروم تھے ۔وہ لوگ کچھ خرافی اور بیہودہ افکار (من جملہ اپنے ہاتھوں سے پتھر ،لکڑی اور کبھی خشک دہی کے بنائے گئے بتوں کی پرستش)میں زندگی گزارتے تھے ۔اوراپنے اسلاف کی تقلید کرنے ،لوٹ کھسوٹ اور قتل وغارت کے علاوہ کسی قسم کا فخر ومباہات نہیں رکھتے تھے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ،ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے والد گرامی عبداللہ اس دنیا سے رحلت کر گئے اور چار سال کے بعد آ پصلىاللهعليهوآلهوسلم کی والدہ کابھی انتقال ہو گیا۔ لہذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے دادا عبدالمطلب نے سنبھالی ۔تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اپنے داداسے بھی محروم ہوگئے اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ کواپنے گھر لے گئے اور اپنے ایک بیٹے کی طرح آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو پالا۔
مکہ کے عرب دوسرے عربوں کی مانند بھیڑ بکری اور اونٹ پالتے تھے اور کبھی اپنے ہمسایہ ممالک بالخصوص شام کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے ۔یہ لوگ ان پڑھ تھے اور اپنے بچوں کی تعلیم وتربیت کے لئے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ان کے درمیان زندگی گزاررہے تھے۔لیکن بچپن سے ہی کچھ پسندیدہ اوصاف کی وجہ سے معاشرے میں امتیازی حیثیت کے مالک تھے، آپصلىاللهعليهوآلهوسلم ہرگز بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے،جھوٹ نہیں بولتے تھے ،چوری اورخیانت نہیں کرتے تھے ،برے ناپسند اور نا مناسب کام انجام دینے سے پر ہیز کرتے تھے ،عقل وشعور رکھتے تھے ،اسی لئے تھوڑے ہی عر صہ میں لوگوں کے درمیان قابل توجہ محبو بیت حاصل کرلی اور''محمد امین'' کے نام سے مشہور ہوئے،چونکہ عرب اپنی امانتوں کوآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے سپرد کرتے تھے اور آپ کی امانتداری اور لیاقت کی تعریفیں کرتے تھے ۔
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم تقریبََابیس سال کے تھے کہ مکہ کی ایک دولت مند عورت (خدیجہ کبریٰ)نے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو اپنی تجارت کے کارندہ کی حیثیت سے معین کیا ۔آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی سچائی ،اچھائی اور عقل ولیاقت کی وجہ سے اس کو تجارت میں کافی منافع ملا اور فطری طور وہ پر آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی شخصیت سے متاثر ہوئی ،اورآخر کار آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ساتھ شادی کرنے کی پیش کش کی ،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے بھی اسے قبول کیا اور ان کے ساتھ شادی کی اور اس کے بعد بھی برسوں تک اپنی شریک حیات کے ساتھ تجارت میں مشغول رہے ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس برس تک لوگو ں میں عام زندگی بسر کرتے تھے اور معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے ،فرق صرف اتنا تھا کہ آپ پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے اوردسرے لوگوں کے مانندبد کرداری میں آلودہ نہیں تھے۔ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم میں ظلم ،سنگدلی اور جاہ طلبی کا شائبہ تک نہیں تھا، اس وجہ سے لوگوں میں محترم اور قابل اعتماد تھے ۔ جب عربوں نے خانہ کعبہ کی مرمت کرنا چاہی اور حجرا سود کو نصب کر نے کے بارے میں عرب قبائل کے درمیان اختلاف اور جھگڑا پیدا ہوا تو انہوں نے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کوحَکَم قرار دیا اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے حکم سے ایک عبا کو پھیلا کر حجراسودکو اس میں رکھا گیا اور قبائل کے سرداروں نے عبا کے اطراف کو پکڑ کر اٹھایااور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجراسود کو اس کی جگہ پر نصب فرمایااور اس طرح قبائل کے درمیان کشمکش ،لڑائی جھگڑا اور احتمالی خونریزی کا خاتمہ ہوا ۔
آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم بعثت سے پہلے اگرچہ خدائے یکتا کی پرستشکرتے تھے اوربت پرستی سے اجتناب کرتے تھے ،لیکن بت پرستی کے عقائدسے مقابلہ نہیں کرتے تھے اس لئے لوگ آپ سے کو ئی سروکار نہیںرکھتے تھے ۔اس زمانے میں دوسرے ادیان کے پیرو جیسے یہود و نصاری بھی عربوں میں محترمانہ طور پر زندگی گزارتے تھے اور اعراب ان کے لئے بھی کوئی مزاحمت ایجاد نہیں کرتے تھے ۔
بحیرا راہب کا قصہ
جن دنوں آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم اپنے چچاحضرت ابو طالب کے ہاں زندگی بسر کر رہے تھے اور ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے ، ان دنوںحضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے شام گئے اورآنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ۔
ایک بڑا قافلہ تھا،کافی مال تجارت کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی ،قافلہ سر زمین شام میں داخل ہو ا اورشہر بصری میں پہنچا ،ایک دَیر کے قریب پڑاو ڈالااورخیمے نصب کر کے آرام کر نے لگے ۔
ایک راہب جس کا لقب ''بحیرا'' دَیرسے باہر آیا اور قافلہ کی دعوت کی،سب نے بحیرا کی دعوت قبول کی اور دیر میں گئے ۔حضرت ابو طالب بھی آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کو سامان کے پاس بیٹھا کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بحیرا کی دعوت پر گئے۔
بحیرا نے پوچھا :کیا سب آگئے ؟
ابو طالب نے کہا :سب سے چھوٹے ایک نوجوان کے علاوہ سب لوگ آگئے ہیں ۔
بحیرانے کہا :اسے بھی لے کے آئیے ۔
آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم زیتون کے ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے ،حضرت ابو طالب نے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو بلایا اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم بھی راہب کے پاس آگئے ۔
بحیرانے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم پر ایک گہری نظر ڈالنے کے بعدکہا:میرے قریب آجاو ،میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ۔اس کے بعد آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کو ایک طرف لے گیا ۔ حضرت ابو طالب بھی ان کے پاس گئے۔
بحیرانے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم سے کہا :آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور تم کو لات وعزی کی قسم دیتاہوں کہ جواب ضرور دینا ۔(لات وعزّیٰ دوبتوں کے نام ہیںکہ جن کی مکہ کے لوگ پرستش کرتے تھے)
آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا : سب سے زیادہ میں ان دونوںبتوں سے نفرت کرتا ہوں ۔
بحیرا نے کہا :تم کو خدائے یکتا کی قسم دیتا ہوں سچ کہنا ۔
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا :میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں آپ اپنا سوال کیجئے۔
بحیرا نے پو چھا :کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو ؟
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا :تنہائی کو ۔
بحیرا نے پو چھا :کس چیز پر زیادہ نظر ڈالتے ہواور اسے دیکھنا پسند کرتے ہو۔؟
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:آسمان اور اس میں موجود ستاروں کو۔
بحیرانے پوچھا :کیا سوچ رہے ہو؟
آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے خاموشی اختیار کی لیکن بحیرا بغور اور سنجیدگی کے ساتھ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی پیشانی کو د یکھتارہا۔
بحیرانے کہا :کس وقت اور کس فکر میں سوتے ہو ؟
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:اس وقت جب آنکھیںآسمان پر جمائے ہوتا ہوں اور ستاروں کو دیکھتا ہوں،انھیں اپنی آغوش میں اورخود کو ان کے اوپر پاتا ہوں ۔
بحیرا نے کہا: کیاخواب بھی دیکھتے ہو ؟
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا : جی ہاں ،جو خوا ب میں دیکھتا ہوں ،اسے بیداری میں بھی دیکھتا ہوں۔
بحیرا نے کہا:مثلا،خواب میں کیا دیکھتے ہو ؟
آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم :نے خاموشی اختیار کی اور بحیرا بھی خاموش رہا ۔
تھوڑی دیر رکنے کے بعد بحیرانے پوچھا:کیا میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ سکتاہوں ؟
آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم اپنی جگہ سے اٹھے بغیر بولے :آئو اور دیکھ لو۔
بحیرا اپنی جگہ سے اٹھا،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے قریب آیا ،آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے شانوں سے لباس ہٹایا ،ایک سیاہ تِل نظر آیا ،ایک نظر ڈال کرزیر لب بولا :وہی ہے!
ابو طالب نے پوچھا :کون ہے ؟کیاکہتے ہو؟
بحیرا نے کہا:ایک علامت جس کی ہماری کتابوں میں خبر دی گئی ہے ۔
ابو طالب نے پوچھا :کون سی علامت؟
بحیرا نے دریافت کیا :اس جوان سے آپ کا کیا رشتہ ہے ؟
ابوطالب چونکہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے ،اس لئے بولے:یہ میرا بیٹا ہے۔
بحیرا نے کہا :نہیں ،اس جوان کا باپ مرچکا ہونا چاہئے ۔
ابو طالب نے پوچھا :تم کیسے جانتے ہو؟جی ہاں یہ جوان میرا بھتیجا ہے !
بحیرا نے ابو طالب سے کہا :سن لو ،اس جوان کا مستقبل اتنا درخشان اورحیرت انگیز ہے ،کہ جو میں نے دیکھاہے اگر اسے دوسرے دیکھ لیںگے اور اسے پہچان لیںگے تو اسے قتل کر ڈالیں گے ،اسے دشمنوں سے مخفی رکھنا اور اس کی حفاظت کر نا ۔
ابوطالب نے کہا : بتائو وہ کون ہے ؟
بحیرا نے کہا: اس کی آنکھوں میں ایک عظیم پیغمبر کی علا مت اور اس کی پشت پر اس کی واضح نشانی ہے ۔
نسطورا راہب کا قصہ
چندبرسوں کے بعد آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم حضرت خدیجہ کبریٰ کی تجارت کے کارندے کی حیثیت سے ان کا مال لیکر دوبارہ شام گئے ۔حضرت خدیجہ نے میسر ہ نامی اپنے ایک غلا م کو آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ہمراہ بھیجا اوراس سے تاکید کی کہ مکمل طور پر آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی اطاعت کرے ۔اس سفر میں بھی جب قافلہ شام کی سر زمین پر پہنچا ،تو شہر بصری کے نزدیک ایک درخت کے نیچے پڑائو ڈالا ، وہا ں قریب میں نسطورا نامی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی ،جسے میسرہ پہلے سے جانتا تھا۔
نسطورانے میسرہ سے پوچھا:درخت کے نیچے سویاہوا کون ہے ؟
میسرہ نے کہا :قریش سے ایک مرد ہے ۔
راہب نے کہا :اس درخت کے نیچے اب تک کوئی نہیں ٹھہرا ہے اور نہ ٹھہرے گا،مگر یہ کہ خدا کے پیغمبروں میں سے ہو۔
اس کے بعدپو چھا :کیا اس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟
میسرہ نے کہا : جی ہاں ،اس کی آنکھیں ہمیشہ اسی حالت میں ہوتی ہیں۔
راہب نے کہا : یہ وہی ہے اوروہ خدا کے پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر ہے ،کاش میں اس دن کو دیکھتا ،جس دن وہ دعوت پر مامور ہوں گے ۔
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت
پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں ،جنھیں خدائے متعال نے لوگوں کی ہدایت کے لئے دنیا میں بھیجاہے ۔
چودہ سو سال پہلے ،عالم بشریت ایک ایسی حالت سے گزر رہی تھی کہ جب دین اور توحید کا صرف نام باقی تھا ۔لوگ یکتاپرستی اورخداشناسی سے بالکل دورہو چکے تھے۔ معاشرے سے انسانیت کے آداب اور عدالت ختم ہوچکی تھی۔جزیزہ نما ئے عرب ، میں خانہ خدا اوردین ابراہیم کا مرکز ہو نے کے باوجود،کعبہ شریف بت خانہ میں اوردین ابراہیم بت پرستی میں تبدیل ہو چکا تھا ۔
عر بوں کی زندگی ،قبیلوں پر مشتمل تھی ، یہاں تک کہ چند شہر جوحجاز اور یمن وغیرہ میں تھے، اسی ترتیب سے چلائے جاتے تھے ۔ دنیائے عرب بد ترین حالات سے گزر رہی تھی تہذیب و تمدن کے بجائے ان میں بے حیائی ،عیاشی ،شراب نوشی اور جوا کھیلنا رائج تھا ۔لڑکیوں کو زند ہ دفن کیا جاتا تھا ۔لوگوں کی زندگی اکثر چوری ،ڈاکہ زنی ،قتل اور مال مویشوں کو لوٹ کر چلائی جاتی تھی ۔ظلم وستم اورخونریزی کو سب سے بڑا فخر سمجھا جاتا تھا ۔
خدائے متعال نے ایسے ماحول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی اصلاح اور رہبری کے لئے مبعوث فرمایا اورقرآن مجید کو آپصلىاللهعليهوآلهوسلم پر نازل کیا۔ جس میں حق شناسی کے معارف،انصاف کے نفاذ کے طریقے اور مفید نصیحتیں موجود ہیں ،اورآنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کو مامور فرمایا تاکہ آسمانی سند سے لوگوں کوانسانیت اورحق پیروی کرنے کی دعوت دیں ۔پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے پہلے بت پرستی کے ماحول میں زندگی بسر کرنے کے باوجود کبھی بتوں کی تعظیم میں سر تسلیم خم نہیں کیا اور ہمیشہ خدائے یکتا کی پرستش کرتے رہے ،کبھی مکہ کے نزدیک واقع غار حرامیں جاتے تھے اور لوگوں کے شوروغوغاسے دوراپنے پروردگارسے مناجات کرتے تھے ۔جب آنحضر ت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر شریف کے چالیس سال گزارنے کے بعدپروردگار عالم کی طرف سے مقام رسالت وپیغمبری پرمبعوث ہوئے توقرآن مجید کا پہلا سورہ (قرء باسم ربّک)آپصلىاللهعليهوآلهوسلم پرنازل ہوا اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم لوگوں کی دعوت وتبلیغ پرما مور ہوئے ۔ابتدائی مرحلہ میں جو ماموریت ذمہ د اری آپصلىاللهعليهوآلهوسلم پر تھی وہ یہ تھی کہ دعوت کو مخفی طورپر شروع کریں ۔
سب سے پہلے جو شخص آپصلىاللهعليهوآلهوسلم پر ایمان لایا وہ حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام تھے ،وہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے گھر میں زندگی بسر کرتے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی تر بیت فرماتے تھے ،حضرت علی کے بعدحضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا۔ ایک مدت تک یہ دونوں آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ساتھ نماز پڑھتے رہے جبکہ اس وقت دوسرے لوگ شرک و کفر میں زندگی بسر کررہے تھے ،کچھ دنوں کے بعد تھوڑے سے لوگ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم پر ایمان لائے ۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سال کے بعد خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اعلانیہ طور پر دعوت دیں اوراپنے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کریں۔آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اس حکم کے مطابق اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا اوران کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور یہ بشار ت دی کہ جوبھی ان میں سب سے پہلے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی دعوت کو قبول کرے گا وہی آپ کا جانشین ہوگاآپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اس اعلان کو تین بار دوہرایا لیکن ان میں سے کسی نے قبول نہیں کیا، بلکہ ہر بارصرف حضرت علی علیہ السلام اٹھے اورآنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اپیل کو قبول کیا ۔پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ۔ اور ان کو اپنا جا نشین بنانے کا وعدہ کیا۔آخر میں ان لوگوں نے کھڑے ہوکر ہنسی اڑاتے ہوئے حضرت ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہا :''اس کے بعدتمہیں اپنے فرزندکی اطاعت کرنی چاہئے''پھر وہ لوگ چلے گئے۔
اسکے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر عام دعوت کا آغازکیا،لیکن لوگوں سے شدید ،سخت،عجیب اورناقابل برداشت مقابلہ کرنا پڑا ۔مکہ کے لوگ اپنے وحشیانہ مزاج اور اپنی بت پرستی کی عادت کی وجہ سے دشمنی اورضد پر اترآئے اورآنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم اورآپ کے پیروئوں کو جسمانی اذیت پہنچانے ،مضحکہ اور توہین کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے اور ہرروز اپنی بیوقوفی اورسختی میں اضافہ کرتے تھے۔
جتنا لوگوں کی طرف سے سختی اوردبائو بڑھتاجا رہاتھا ،اتناہی آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم بھی اپنی دعوت میں صبرواستقامت،اورثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور اسلام کے پیروئوں میں تدریجاًاضافہ ہوتارہا لہذاکفار نے آ نحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولالچ دینا شروع کی کہ انہیں کافی مال ودولت دیں گے یا انھیں حاکم کے طور پر منتخب کریں گے تاکہ وہ اپنی دعوت سے دست بردار ہو جائیں یاصرف اپنے خدا کی طرف دعوت دیں اور ان کے خدائوں کو نہ چھیڑیں ۔لیکن پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجویز کو ٹھکرادیا اور اس خدا ئی فریضہ کو انجام دینے اوردعوت کو جاری رکھنے کے اپنے مستحکم عزم وارادے کا اعلان کیا ۔
کفار جب طمع و لالچ کے راستے سے ناامید ہوگئے تو انہوں نے دوبارہ اپنے دبائو میں اضافہ کیا اور مسلمانوں کو سخت جسمانی اذ یتین تکلیفیں پہنچانے لگے اور کبھی ان میں سے کچھ کو قتل کر تے تھے تاکہ انھیں اسلام سے روک سکیں ۔کفار نے قبیلئہ بنی ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب کے لحاظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے اجتناب کیا ،لیکن یہ لحاظ دوسری اذیتوں اور تکلیفوں کو روک نہ سکا۔
ایک مدت کے بعد مسلمانوں کا عرصئہ حیات اور تنگ ہو گیا اورظلم وستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا حالت یہ ہو گئی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کوحبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دیدی تاکہ کچھ دنوں تک آرام کی سانس لے لیں ۔ایک جماعت نے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفربن ابیطالب کی سر کردگی میں اپنے اہل وعیال کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی (جعفرپیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے منتخب صحابیوں میں سے تھے)۔
کفار مکہ جب مسلمانوں کی ہجرت سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنے دوتجربہ کارافراد کو کافی مقدار میں تحفہ و تحائف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا،اورانہوں نے بادشاہ سے مکہ کے مہاجرین کو واپس بھیجنے کا تقاضا کیا ،لیکن جعفربن ابیطالب نے اپنے بیانات سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر ا پا نورانی شخصیت اور اسلام کے بلند اصولوں کی حبشہ کے بادشاہ ،مسیحی پادریوں اور ملک کے حکام کے سامنے تشریح کی اور سورئہ مریم کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی ۔
حضرت جعفر بن ابیطالب کاحق پر مبنی یہ بیان ایسا دلچسپ و مو ثرتھا کہ بادشاہ اور مجلس میں موجود تمام لوگوں نے آنسوبہائے ۔نتیجہ میں بادشاہ نے کفار مکہ کے تقاضا کو مسترد کیا اور ان کے بھیجے ہوئے تحفوں کو واپس کر دیا اورحکم دیا کہ مسلمان مھاجرین کے آرام وآسائش کے تمام امکا نات فراہم کئے جائیں۔
کفار مکہ نے اس روئداد کے بعدآپس میں معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم ،جو پیغمبراسلام کے رشتہ دار تھے ،اور ان کے حامیوں کے ساتھ قطع تعلق کر کے مکمل طورپر سوشل بائیکاٹ کریں، اس سلسلہ میں انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا اور عام لوگوں سے دستخط لے کر اسے کعبہ میں رکھا ۔
بنی ہاشم،پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے باہرجانے پر مجبور ہو ئے اور شعب ابو طالب نامی کے ایک درہ میں پناہ لی او رانتہا ئی سختی اور بھوک میں زندگی بسر کرتے تھے۔
اس مدت کے دوران کسی نے شعب ابو طالب سے باہر آنے کی جرائت تک نہیں کی، دن میں شدید گرمی اور رات کو عورتوں اور بچوں کی فر یادوں سے دست وگریبان تھے۔
کفار تین سال کے بعد عہد نامہ کے محوہونے اور بہت سے قبائل کی طرف سے ملامتوں کے نتیجہ میں اپنے معاہدہ سے دست بردار ہوئے اور بنی ہاشم کا محاصرہ ختم ہوا ،لیکن انہی دنوںپیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا حامی حضرت ابو طالب اورآنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ کبری کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے لئے اور مشکل ہو گئی۔آپصلىاللهعليهوآلهوسلم میں یہ طاقت نہیں رہی کہ لوگوں کے درمیان جائیں یا خود کو کسی کے سامنے ظاہر کریں یاکسی خاص جگہ پر رہیں۔یہاں تک کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی جان کی کو ئی حفا ظت نہیں تھی ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کی طرف سفر
جس سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم شعب ابو طالب کے محاصرہ سے باہر آئے ،وہ بعثت کا تیرھواں سال تھا ۔پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہی دنوں شہرطائف کی طرف سفر کیا۔(طائف مکہ سے تقریبا سو کلو میٹر کی دوری پر ایک شہرہے)آپصلىاللهعليهوآلهوسلم صلىاللهعليهوآلهوسلم نے طائف کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی ،لیکن اس شہر کے جاہل ہر طرف سے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم پر حملہ آور ہوئے اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو برابھلا کہا ،سنگسار کیا اورآخرکار آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کوشہر سے باہر نکال دیا گیا ۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ لوٹے اور کچھ مدت تک مکہ میں رہے ،چونکہ وہاں پر جان کی کوئی حفاظت نہیں تھی،اس لئے لوگوںکے درمیان نہیں آتے تھے۔ کفار مکہ کے سردار اوربزرگ شمع رسالت کو گل کرنے کی خاطر مناسب فرصت کو دیکھتے ہوئے ،دار الندوہ ۔جو مجلس شوری کے مانند تھا ۔ میں جمع ہوئے اور ایک مخفیانہ مٹینگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا آخری منصوبہ بنایا ۔
مذکورہ منصوبہ یہ تھا کہ قبائل عرب کے ہر قبیلہ سے ایک شخص کو چن لیا جائے اور تمام منتخب افراد ایک ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ کر کے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو قتل کر ڈالیں۔ اس منصوبہ میں تمام قبائل کو شریک کرنے کا مقصود یہ تھا کہ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کا قبیلہ بنی ہاشم آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے خون کا بدلہ لینے کے لئے قیام نہ کر سکئے اور قتل کامنصوبہ بنانے والوں سے نہ لڑ سکے۔ اوراسی طرح بنی ہاشم میں سے ایک آدمی کو شر یک کر کے قبیلئہ بنی ہاشم کی زبان مکمل طور پر بند کردی ۔
اس فیصلے کے مطابق ،مختلف قبائل کے تقریبا چالیس افراد آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے قتل کے لئے منتخب ہوئے ، انہوں نے رات کے اندھیرے میں آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ،حملہ آور سحر کے وقت گھر میں داخل ہوئے تاکہ منصوبہ کوعملی جامہ پہنائیں،لیکن ارادئہ الہی ان کے ارادہ سے بلند ہے ، کہ جس سے ان کے منصوبہ پر پانی پھرگیا ۔خدائے متعال نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کئی اور کفار کے منصودبہ سے آگاہ فرمایااورحکم فرمایا کہ راتوں رات مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں ۔
پیغمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی روداد سے حضرت علی علیہ السلام کو آگاہ فرمایا اور حکم دیا کہ رات کو آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بستر پر سو جائیں اور ان سے کچھ وصیتیں کیںاور رات کے اند ھیرے میں گھر سے باہر نکلے ،راستے میں حضرت ابو بکرکودیکھا ،انھیں بھی اپنے ساتھ مدینہ لے کر گئے ۔مدینہ کے کچھ بزرگ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ آکر آپصلىاللهعليهوآلهوسلم سے ملاقات کی اور آپ پر ایمان لائے تھے اور ضمنا ًایک عہدنامہ لکھا تھا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو وہ ان کی حمایت میں ایسے ہی دفاع کریں گے جیسا وہ اپنی جان و عزت کا دفاع کرتے ہیں ۔
مدینہ کے یہودیوں کی بشارت
یہودیوں کے بہت سے قبیلوںنے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اوصاف اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی جگہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھاتھا اور اپنے وطن کو ترک کر کے حجاز آکر مدینہ اور اس کے اطراف میں پڑائو ڈالا تھا اورنبی امی کے ظہور کاانتظار کر رہے تھے۔چونکہ وہ لوگ دولت مند تھے ،اس لئے اعراب کبھی کبھی ان پر حملہ کر کے ان کے مال ودولت کو لوٹ لیتے تھے ۔
یہودی ہمیشہ مظلو میت کے عالم میں ان سے مخاطب ہو کر کہتے تھے : ''ہم تم لوگو ں کے ظلم وستم پریہاں تک صبر کریں گے کہ نبی امی مکہ سے ہجرت کرکے اس علاقہ میں آ جائیں، اس دن ہم آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم پر ایمان لاکر تم لوگوں سے انتقام لیں گے''۔
اہل مدینہ کے فورَا ایمان لانے کے اہم عوامل میں سے ایک ان ہی بشارتوں کا ان کے ذہنوں پر اثر تھا ،آخر کار وہ لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن یہودیوں نے قومی تعصب کی بنا پر ایمان لانے سے گریز کیا ۔
نبی کی بشارتوں کی طرف قرآن مجید کااشارہ
خدائے متعال اپنے کلام پاک میں کئی جگہوں پران بشارتوں کی طرف اشارہ فرماتا ، بالخصوص اہل کتاب کے ایک گروہ کے ایمان کے بارے میں فرماتا ہے۔
( الّذین یتّبعون الرّسول النّبی الامّی الّذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التّوریة والانجیل یامرهم بالمعروف و ینهٰهم عن المنکر و یحلّ لهم الطّیبٰت ویحرّم علیهم الخبٰئث ویضع عنهم اصرهم و الاغلل التّی کانت علیهم ) ۔
(اعراف١٥٧)
''جولوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہو جس کاذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوںسے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پرسے احکام کے سنگین بوجھ اور قید وبند کو اٹھادیتا ہے...''
مزید فرماتا ہے:
( ولمّا جاء هم کتب من عند اللّه مصدّق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون ) ...) (بقرہ٩)
''اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جوان کی توریت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور اسکے پہلے وہ دشمنوںکے مقابلہ میں اسی کے ذریعہ طلب فتح بھی کرتے تھے ۔''
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں ورود
اسلام کی ترقی کی زمین شہر یثرب جس کا بعد میں مدینہ نام رکھا گیا۔میں ہموارہوی اور اس کاسبب یہ تھا کہ اہل مدینہ داخلی جنگ۔جو برسوں سے اوس وخزرج نامی دوقبیلوں کے درمیان جاری تھی ۔سے تنگ آچکے تھے ،آخر کار وہ اس فکرمیں تھے کہ اپنے لئے ایک بادشاہ کا انتخاب کر کے اس قتل و غارت کو ختم کریں ۔
انہوں نے اس کام کے لئے،اپنے چند معروف افراد کو مکہ بھیجا تاکہ اس سلسلہ میں مکہ کے سرداروں سے گفتگو کریں ۔یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ میں پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو اعلانیہ طور پر شروع کیا تھا ۔
مدینہ کی معروف شخصیتیں جب مکہ پہنچ گئیں اور انہوں نے اپنے مقصدکو قریش کے سرداروں کے سامنے پیش کیا،تو قریش کے سرداروںنے اس عذرو بہانہ سے ان کے ساتھ صلاح ومشورہ کرنے سے پہلو تی کی کہ ایک مدت سے اس شہر میں محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے مقدس خدائوں کو برا بھلا کہا ہے، اور ہمارے جوانوں کو گمراہ کیا ہے اور ہمیں فکرمند کیا ہے۔
اس بات کو سن کر اہل مدینہ ہل کر رہ گئے ،کیونکہ انہوں نے مدینہ میں یہودیوں سے بارہا یہ پیشگوئی سنی تھی کہ مکہ میں نبی امی ظہور کریں گے،لہذا ان کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو اکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاکر انھیں دیکھیں اور ان کی دعوت کی کیفیت سے آگاہ ہو جائیں ۔جب وہ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خدمت میں پہنچے اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بیانات اور قرآن مجید کی آیات کوسنا تو وہ ایمان لے آئے اورآنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم سے وعدہ کیا کہ اگلے سال مدینہ کے کچھ لوگوں کے ہمراہ آکر اسلام کی ترقی کے اسباب فراہم کریں گے ۔
دوسرے سال مدینہ کے سرداروں کی ایک جماعت مکہ آئی،رات کے وقت شہر سے باہر تنہائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی بیعت کی اور مدینہ میں دین اسلام کو رائج کرنے کا عہد وپیمان کیا اور کہا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو وہ دشمنوں سے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی اس طرح حفاظت ودفاع کریں گے جیسا وہ اپنے خاندان کا دفاع کرتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ مدینہ لوٹے ،اہل مدینہ میں سے اکثر لوگوںنے اسلام قبول کیا اور اس طرح شہر مدینہ اسلام کا پہلا شہر بن گیا ۔لہذا جب انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ بہت خوشحال ہوئے اور انتہائی بے تابی کے ساتھ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے استقبال کے لئے بڑھے اور آپ کاشایان شان استقبال کیا اور انتہائی خلوص نیت سے اپنی جان ومال کو اسلام کی ترقی کے لئے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خدمت میں پیش کیا اسی لئے ان کانام''انصار'' رکھا گیا۔ خدائے متعال اپنے کلام پاک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ اور انصار کی خدمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی قدردانی کرتا ہے:
( والّذین تبو ء والدّار والایمٰن من قبلهم یحبّون من هاجر لیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجةً ممّا اوتو ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ) ۔ (حشر٩)
''اور جن لوگوں نے دارالہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اور جو کچھ انھیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں چاہے انھیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو ...''
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی جنگوںکاایک مختصرجائزہ
١۔جنگ بدر
آخر کار ٢ھ میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی جنگ سرزمین بدر میں ہوئی۔اس جنگ میں کفار کے سپاہیوں کی تعدادتقریبا ایک ہزار تھی جو جنگی سازوسامان اور اسلحہ سے مکمل طور پر لیس تھے اور مسلمانوں کے پاس ان کی نسبت ایک تہائی افراد تھے جو اچھی طرح سے مسلح بھی نہیں تھے۔لیکن خدائے متعال کی عنایتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور کفار کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
اس جنگ میں کفار کے ستر افراد مارے گئے،ان میں سے تقریبا نصف حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے سترآدمی اسیر کر لئے گئے اور باقی افراد تمام جنگی سازوسامان چھوڑ کر بھاگ گئے ۔
٢۔جنگ احد
٣ ہجری میں کفار مکہ نے ابوسفیان کی سرکردگی میں تین ہزار افراد کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا اور احد کے بیابان میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ آمناسامنا ہوا۔
پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اس جنگ میں سات سو مسلمانوں کے ہمراہ کفار کے سامنے صف آرائی کی۔جنگ کی ابتداء میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا ،لیکن کئی گھنٹوں کے بعد بعض مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے لشکر اسلام کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کفار نے ہر طرف سے مسلمانو ںپر تلواروں سے وارکیا ۔
اس جنگ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاحضرت حمزہ تقریبا ستر اصحاب پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم ،جن میں اکثر انصار تھے،کے ساتھ شہید ہوئے اورآنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے سامنے کے دانتوں میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا ۔ایک کافرنے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے شانہ مبارک پر ایک ضرب لگاکر آوازدی :''میں نے محمد کو قتل کردیا''اس کے نتیجہ میں لشکر اسلام پراگندہ ہوا ۔
صرف حضرت علی علیہ السلام چند افراد کے ہمراہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ثابت قدم رہے اورحضرت علی علیہ السلام کے علاوہ سب شہید ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے آخر تک مقابلہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا ۔
آخری وقت ،اسلام کے فراری فوجی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے ،لیکن دشمن کے لشکر نے اس قدر کامیابی کو غنیمت سمجھ کر جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور مکہ روانہ ہوے ۔
لشکر کفار چند فرسخ طے کرنے کے بعد اس بات پر غور کرنے کے بعد سخت پشیمان ہوئے کہ انہوں نے جنگ کو آخری فتح تک کیوں جاری نہ رکھا تاکہ مسلمانوں کی عورتوںاور بچوں کو اسیر کر کے ان کے اموال کو لوٹ لیتے ۔اس لئے مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کے لئے آپس میں مشورہ کررہے تھے۔لیکن انھیں یہ خبر ملی کہ لشکر اسلام جنگ کو جاری رکھنے کے لئے ان کے پیچھے آرہا ہے ۔وہ اس خبر کو سن کر مرعوب ہوئے اور پھر سے مدینہ لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ گئے ۔
حقیقت بھی یہی تھی ،کیوںکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خد اکے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کا ایک مسلح لشکر تیار کر کے حضرت علی علیہ السلام کی سر پرستی میں ان کے پیچھے روانہ کیا تھا۔
اس جنگ میں اگر چہ مسلمانو ں کو زبر دست نقصان اٹھانا پڑا لیکن حقیقت میں یہ اسلام کے نفع میں ختم ہوئی خصوصاََ اس لحاظ سے کہ دونوں طرف نے جب جنگ بندی کے معاہدہ پر اتفاق کیا تو اسی وقت طے پایا تھا کہ اگلے سال اسی وقت بدر میں پھر سے جنگ لڑیں گے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ایک گروہ کے ساتھ وعدہ کے مطابق وقت پر بدر میں حاضر ہوگئے ،لیکن کفار وہاں نہ پہنچے ۔
اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے اپنے حالات کو بہتربنایا اور جزیرہ نما ئے عرب میں مکہ اور طائف کے علاوہ تمام علاقوں میں پیش قدمی کی۔
٣۔جنگ خندق
تیسری جنگ جو عرب کفار نے پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ساتھ لڑی ،اورجو اہل مکہ کی رہبری میں آخری اور ایک زبردست جنگ تھی ،اسے ''جنگ خندق'' یا''جنگ احزاب ''کہتے ہیں ۔
جنگ احد کے بعد مکہ کے سردار ابوسفیان کی سر کردگی میں اس فکر میں تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری اور کاری ضرب لگا کر نور اسلام کو ہمیشہ کے لئے بجھادیں۔ اس کام کے لئے عرب قبائل کوابھارا اور اپنے تعاون اور مدد کے لئے دعوت دی ۔ طوا ئف کے یہو دی بھی اسلام کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے کے باوجود چوری چھپے اس آگ کو ہوادے رہے تھے اورآخر کار اپنے عہد وپیمان کو توڑ کر کفار کے ساتھ تعاون کرنے کاکھل کر معاہدہ کیا ۔
جس کے نتیجہ میں ٥ھ میں قریش ،عربوں کے مختلف قبائل اور طوائف کے یہودیوں پر مشتمل ایک بڑااور سنگین لشکر تمام جنگی سازو سامان سے لیس ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی دشمن کے اس منصوبے سے آگاہ ہو چکے تھے۔اس لئے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا ۔ایک طویل گفتگواور صلاح ومشورہ کے بعد،پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معزز صحابی سلمان فارسی کی تجویز پر شہر مدینہ کے اردگرد ایک خندق کھودی گئی اور لشکر اسلام نے شہر کے اندر پناہ لی ۔دشمن کی فوجیں جب مد ینہ پہنچیں تو انھیں مدینہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ نہیںملا ،مجبور ہو کر انہوں نے شہر مدینہ کو اپنے محاصرہ میں لے لیا اور اسی صورت میں جنگ شروع کی ۔جنگ اور محاصرہ کچھ طولانی ہوگیا ۔اسی جنگ میں عرب کا نامور شجاع اور شہسوارعمروبن عبدود،حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ۔آخر کارطوفان ،سردی، محاصرہ کے طولانی ہونے ،عربوں کی خستگی اور یہودواعراب کے درمیان اختلاف کے نتیجہ میں محاصرہ ختم ہوا اور کفار کا لشکرمدینہ سے چلا گیا ۔
٤۔جنگ خیبر
جنگ خندق کے بعد،جس کے اصلی محرک یہو دی تھے ،جنہوں نے کفارعرب کا تعاون کر کے اعلانیہ طورپر اسلام کے ساتھ اپنے معاہدہ کو توڑ دیا تھا ،پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم نے خدا کے حکم سے مدینہ میں موجودیہودی کے قبائل کی گوشمالی اور تنبیہ کرنے کے لئے ان کے ساتھ چند جنگیں لڑیں اور یہ سب جنگیں مسلمانوں کی فتحیابی پر ختم ہوئیں ۔ان میں سب سے اہم''جنگ خیبر''تھی ۔خیبر کے یہو دیوں کے قبضہ میں چند مستحکم اورمضبوط قلعے تھے اور انکے پاس جنگجوئوں کی ایک بڑی تعداد تھی ،جوجنگی سازوسامان سے لیس تھے ۔
اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام نے یہودیوں کے نامور پہلوان''مرحب ''کو قتل کر کے یہودیوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور اس کے بعدقلعہ پر حملہ کیا اور قلعہ کے صدردروازے کو اکھاڑدیا اور اسطرح اسلام کا لشکر قلعہ کے اندر داخل ہوا اورفتح وظفر کے پرچم کو قلعہ پر لہرادیا ۔اسی جنگ میں ،جو ٥ھ میں ختم ہوئی حجاز کے یہودیوں کاخاتمہ ہوا ۔
بادشاہوں اور سلاطین کو دعوت اسلام
٦ھمیں پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بادشاہوں ،سلاطین اورفرمانروائوں، جیسے:شاہ ایران،قیصر روم،سلطان مصراور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام چند خطوط تحریر فر مائے اور انھیں اسلام کی دعوت دی ۔نصرانیوں اور مجوسیوں کے ایک گروہ نے جزیہ دے کر امن سے رہنے کا وعدہ کیا اور اسطرح اسلام کے ذمہ میں آگئے ۔آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا ایک معاہدہ کیا ۔اس معاہدہ کے جملہ شرائط میں یہ شرط بھی تھی کہ مکہ میں موجودمسلمانوں کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائی جائے اور اسلام کے دشمنوں کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں مدد نہ کی جائے ۔
لیکن کفار مکہ نے کچھ مدت کے بعد اس معاہدہ کو توڑ دیا ،جس کے نتیجہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیااور ٦ھ میں دس ہزارکے ایک لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا۔ مکہ کسی جنگ،خونریزی اور مزاحمت کے بغیر فتح کیا اورخانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا ۔
عام معافی کا اعلان فرمایا ۔مکہ کے سرداروں کو۔جنہوں نے بیس سال کے عرصہ میں آپصلىاللهعليهوآلهوسلم سے کافی دشمنی کی تھی اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اورآپ کے اصحاب کے ساتھ نارواسلوک کیا تھا۔اپنے پاس بلایا اور کسی قسم کی شدت ،برے سلوک اور سختی کے بغیر نہایت مہر بانی اور لطف و کرم سے انھیں معاف فرمایا ۔
٥۔جنگ حنین
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد ،اس کے اطراف منجملہ شہر طائف کو فتح کر نے کے لئے اقدام کیا اور اس سلسلہ میں عربوں سے متعدد جنگیں لڑیں کہ ان میں سے ایک ''جنگ حنین ''ہے۔
''جنگ حنین''،پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم جنگوں میں سے ہے۔یہ جنگ فتح مکہ کے کچھ ہی دنوں بعد حنین،میں قبیلہ ھوازن سے ہوی ۔لشکر اسلام نے دوہزارسپاہوں سے ھوازن کے کئی ہزار سواروں کا مقابلہ کیا اور ان کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہوی۔
ھوازن،نے جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو بری طرح شکست دیدی،یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام ،کہ جن کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا ،جو پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کے آگے آگے لڑرہے تھے اور چند گنے چنے افرادکے علاوہ سب بھاگ گئے ۔لیکن کچھ دیر کے بعد ہی پہلے انصاراورپھر دوسرے مسلمان دوبارہ میدان کارزار کی طرف واپس لو ٹے اور ایک شدیداور سخت جنگ لڑی اور دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ۔
اس جنگ میں دشمن کے پانچ ہزار سپاہی لشکر اسلام کے ہاتھوں اسیر ہو ئے ،لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے تمام اسیروں کو آزاد کردیا ،صرف چند افراد ناراض تھے کہ آنحضرت نے ان کے حصے میں آئے افراد کو پیسے دیکر خرید لیا اور پھر انہیںآزاد کر دیا ۔
٦۔جنگ تبوک
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ٩ ہجری میں قیصر روم سے جنگ کرنے کی غرض سے تبوک پر لشکر کشی کی( تبوک شام او رحجازکی سرحدپر ایک جگہ ہے) کیونکہ افواج پھیلی تھی کہ قیصر روم نے اس جگہ پر رومیوں اور اعراب کے ایک لشکر کو تشکیل دیا ہے ۔ جنگ موتہ بھی اس کے بعد رومیوں کے ساتھ وہیں پر لڑی گئی جس کے نتیجہ میں جعفر بن ابیطالب ، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ جیسے اسلامی فوج کے سردار شہید ہوئے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ تبوک پر حملہ کیا لیکن اسلامی لشکر کے پہنچنے پر وہاں موجود افراد بھاگ گئے تھے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تین دن تبوک میں ٹھہرے ۔ اس کے اطراف کی پاک سازی کرنے کے بعد واپس مدینہ لوٹے۔
اسلام کی دوسری جنگیں
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ جنگوں کے علاوہ مدینہ منورہ میں اپنے دس سالہ قیام کے دوران تقریبا اَسّی چھوٹی بڑی جنگیں لڑی ہیں، جن میں سے ایک چوتھائی جنگوں میں آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔
آنحصرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے جن جنگوں میں شر کت فرمائی ،دوسرے کمانڈروں کے بر خلاف کہ وہ پناہ گاہ میں بیٹھ کر فرمان جاری کر تے ہیں ،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم بذات خودسپاہیوں کے شانہ بہ شانہ لڑتے تھے ،لیکن کسی کو ذاتی طور پرقتل کرنے کا آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے لئے کبھی اتفاق پیش نہیں آیا ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنوی شخصیت کاا یک جائزہ
مستند تاریخی اسناد کے مطابق،پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے ماحول میں پر ورش پائی تھی جو جہالت، فساد اور خلاقی برائیوں کے لحاظ سے بدترین ماحول تھا۔ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے ایک ایسے ہی ماحول میں کسی تعلیم وتر بیت کے بغیر اپنے بچپن اور جوانی کے ایام گزارے تھے ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر چہ ہرگز بت پرستی نہیں کی اورخلاف انسانیت کامو ں میں آلودہ نہیں ہوئے ،لیکن آپصلىاللهعليهوآلهوسلم ایسے لوگوں میں زندگی گزار رہے تھے کہ کسی بھی صورت میں آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی زندگی سے اس قسم کے روشن مستقبل کا اشارہ تک نہیں ملتا تھا،سچ یہ ہے کہ ایک غریب ونادار یتیم اورکسی سے تعلیم وتربیت حاصل نہ کرنے والے شخص سے یہ سب بر کتیں قابل یقین نہیں تھیں ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں ایک زمانہ گزارا،یہاں تک کہ انہی راتوں میں سے ایک رات کو جب آپصلىاللهعليهوآلهوسلم اپنے آرام ضمیر اورخالی ذہن کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے ،اچانک اپنے آپ کو ایک دوسری شخصیت میں پایا ۔آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی پوشیدہ باطنی شخصیت ایک آسمانی شخصیت میں تبدیل ہو گئی ،انسانی معاشرے کے ہزاروں سال پہلے کہ افکار کو خرافات سمجھا اور دنیا والوں کی روش اور دین کو اپنی حقیقت پسندانہ نگاہوں سے ظلم وستم کے روپ میں دیکھا ۔
دنیا کے ماضی اور مستقبل کو آپس میں جوڑ دیا ،سعادت بشری کی راہ کی تشخیص کردی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ اور کان نے حق وحقیقت کے علاوہ نہ کچھ دیکھا اورنہ کچھ سنا ،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی زبان کلام خدا سے پیغام آسمانی اورحکمت وموعظہ کے لئے کھل گئی، اندرونی ضمیر جو تجارت ،لین دین اور روزہ مرہ کی مصلحتوں میں سر گرم تھا ، وہ دل و جان سے دنیااور دنیاوالوں کی اصلاح اور بشر کی ہزاروں سال کی گمراہی اور ظلم وستم کو ختم کرنے پر اتر آیا اور حق وحقیقت کو زندہ کرنے کے لئے تن تنہا قیام کیا اور دنیا کی وحشتناک متحد مخالف طاقتوں کی کوئی پروانہ کی معارف الٰہیہ کوبیان کیا اور کائنات کے تمام حقائق کا سرچشمہ خالق کائنات کی وحدانیت کو سمجھا ۔
انسان کے اعلیٰ اخلاق کی بہترین تشریح فر مائی اور ان کے روابط کو کشف اور واضح کیا، جو بیان فرماتے تھے خود دوسروں سے پہلے اس کے قائل ہوتے تھے اور جس چیز کی ترغیب فر ماتے تھے ،پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے ۔
شریعت اور احکام ،جو عبادتوں اور پرستشوں کے ایک مجموعہ پر مشتمل ہیں ،وہ خدائے یکتا کی عظمت وکبر یائی کے سامنے بندگی کوایک اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں ۔اس کے علاوہ عدلیہ اور تعزیرات سے متعلق دوسرے قوانین بھی لائے ،کہ جو انسانی معاشرے کے تمام ضروری مسائل کا اطمینان بخش جواب دیتے ہیں ،وہ ایسے قوانین ہیںجو آپس میں مکمل طور پر ایک دوسرے سے مرتبط ہیں اور توحید،انسانی احترام و عالی اخلاق کی بنیاد پر استوارو پائدار ہیں ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی عبادات ومعاملات پر مشتمل قوانین کا مجموعہ،اس قدر وسیع اور جامع ہے کہ عالم بشریت میں انفرادی واجتماعی زندگی کے تمام مسائل موجود ہیں اور زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی گوناگوں ضرورتوں کی تحقیق کر کے تشخیص کا حکم دیتا ہے ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کے قوانین کو عالمی اورابدی جانتے ہیں ،یعنی آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کا اعتقاد ہے کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کا دین تمام انسانی معاشروں کی دنیوی واخروی ضرورتوں کو ہرزمانے میں پورا کرسکتا ہے ،اور لوگوں کو اپنی سعادت کے لئے اسی روش کو اختیار کرناچاہئے ۔
البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کوعبث اور مطالعہ کے بغیر نہیں فر مایا ہے بلکہ خلقت کی تحقیق اور عالم انسانیت کے مستقبل کی پیشینگوئی کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ :
اولّاً :اپنے قوانین اورانسان کی جسمی اور روحی خلقت کے درمیان مکمل توافق وہم آھنگی کو واضح کردیا۔
ثانیا : مستقبل میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور مسلمانوں کے معاشرے کو پہنچنے والے نقصانات کو مکمل طور پر مدنظر رکھنے کے بعد اپنے دین کے احکام کے ابدی ہونے کا حکم فرمایا ہے ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیشنگو ئیاں قطعی دلیلوں کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں،ان کے مطابق آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنی رحلت تک کے عمومی حالات کی تشریح فرمائی ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معارف کے اصولوں اور شرائط کوپراکندہ طور پر قرآن مجید میں لوگوں کے لئے تلاوت فرمائی ہیں کہ اس کی حیرت انگیز فصاحت وبلاغت نے عرب دنیا کے فصاحت وبلاغت کے اساتذہ اور ماہروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور دنیا کے دانشمندوں کے افکار کو متحیر کر کے رکھدیا ہے ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کارناموں کو ٢٣ سال کے عرصہ میں انجام دیا ہے کہ جن میں سے ١٣سال جسمانی اذیت ، اور کفار مکہ کی ناقابل برداشت مزاحمتوں میں گزارے اور باقی دس سال بھی جنگ ،لشکر کشی ، کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ بیرونی مقابلہ اور منافقین اور روڑے اٹکانے والوں کے ساتھ اندرونی مقا بلہ اور مسلمانوں کے امورکی باگ ڈور سنبھالنے میں اوران کے عقائد واخلاق واعمال اور ہزاروں دوسری مشکلات کی اصلاح کر نے میں گزارے ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا راستہ ایک ایسے غیر متزلزل ارادہ سے طے کیا،جو حق کی پیروی اور اسے زندہ کرنے کے لئے تھا ۔آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی حقیقت پسندانہ نظر صرف حق پر ہو تی تھی اور خلاف حق کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔اگرکسی چیز کواپنے منافع کے یا میلانات اور اپنے عمومی جذبات کے موافق پاتے تھے تو ان میں سے جس کو حق جانتے اسے قبول فرماتے اور اسے مسترد نہیں کرتے تھے اورجس کو باطل سمجھتے تھے اسے مسترد کر دیتے اور ہرگزقبول نہیں کرتے تھے ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی معنوی شخصیت
اگرہم انصاف سے مذکورہ مطالب پر تھوڑاسا غور وخوص کریں گے ،توکسی شک وشبہہ کے بغیر یہ قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان حالات اور ماحول میں ایسی شخصیت کا پیدا ہونا معجزہ اور خدائے متعال کی خاص تائید کے علاوہ کچھ نہیں تھا ۔
اس لحاظ سے ،خدائے متعال اپنے کلام پاک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے ،یتیمی اور سابقہ مفلسی کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہے ،اور ان کو عطا کی گئی شخصیت کوایک آسمانی معجزہ شمار کرتا ہے اوراسی سے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی دعوت کی حقانیت کا استدلال کرتا ہے ،چنانچہ فرماتا ہے :
( الم یجدک یتیما فآوی ٭و وجدک ضالّا فهدیٰ ٭ و وجدک عائلاً فاغنی ) (ضحی٨٦)
''کیا اس نے تم کو یتیم پاکر پناہ نہیں دی ہے ؟اور کیا تم کوگم گشتہ پاکر منزل تک نہیں پہنچایا ہے؟اور تم کو تنگ دست پاکر غنی نہیں بنایا ہے؟''
( وماکنت تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطّه بیمینک ) ۔
(عنکبوت٤٨)
''اور اے پیغمبر!آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے تھے اورنہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے ...''
( وان کنتم فی ریب ممّا نزّلناعلی عبدنا فاتو بسورةٍ من مثله ) ۔ (بقرہ٢٣)
''اگر تمھیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تواس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آئو. ..''
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت
تنہااصل جس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے اپنے دین کی بنیاد رکھی اور اسے دنیاوالوں کے لئے سعادت کاسبب قرار دیا،وہ تو حید کی اصل ہے ۔
توحید کی اصل کے مطابق،جوخالق کائنات پرستش کا سزاوارہے وہ خدائے یکتاہے ،اور خدائے متعال کے علاوہ کسی اور کے لئے سر تعظیم خم نہیں کیاجاسکتا۔
اس بناپر ،انسانی معاشرہ میں جوروش عام ہونی چاہئے ،وہ یہ ہے کہ سب آپس میں متحد اور بھائی بھائی ہوں اور کوئی اپنے لئے خدا کے سواکسی کو بلا قید وشرط حاکم مطلق قرار نہ دے، چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :
( قل یااهل الکتاب تعالوا الی کلمةٍ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الااللّه ولا نشرک به شیئا ولا یتّخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون اللّه ) ۔ (آل عمران٦٤)
''اے پیغمبر !آپ کہدیں کہ اہل کتاب !آئوایک منصفانہ کلمہ پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں ،کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں ...''
اس آسمانی حکم کے مطابق ،آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیرت میں سبھی کو برابر وبرادر قرار دیتے تھے اوراحکام وحدودالہیٰ کے نفاذ میں ہرگز امتیازی سلوک اور استثنا کے قائل نہیں تھے ،اس طرح اپنے اور پرائے ،طاقت ور اور کمزور،امیر وغریب اور مرداورعورت میں فر ق نہیں کرتے تھے اور ہرایک کے حق کو دین کے احکام وقوانین کے مطابق اس تک پہنچاتے تھے ۔
کسی کو کسی دوسرے پرحکم فرمائی اور فرمانروائی اور زبردستی کرنے کاحق نہیں تھا۔لوگ قانون کے حدود کے اندر زیادہ سے زیادہ آزادی رکھتے تھے ۔(البتہ قانون کے مقابلہ میں آزادی نہ صرف اسلام میں بلکہ دنیا کے اجتماعی قوانین میں بھی کو ئی معنی نہیں رکھتی ہے)
آزادی اور اجتماعی عدالت کی اسی روش کے بارے میں خدائے متعال اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے فر ماتا ہے :
( الّذین یتّبعون الرّسول النبیّ الامیّ الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التوریٰة والانجیل یامرهم بالمعروف وینهٰهم عن المنکر و یحلّ لهم الطیبت ویحرّم علیهم الخبٰئث ویضع عنهم اصرهم والاغلل الّتی کانت علیهم فالّذین امنوا به وعزّروه ونصروه واتّبعوا النّور الّذی انزل معه اولئک هم المفلحون٭قل یا ایّها النّاس انّی رسول اللّه الیکم جمیعا ) ۔ (اعراف١٥٨١٥٧)
''جو لوگ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں کہ،جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوںکو حرام قرار دیتا ہے اور ان پرسے احکام کے سنگین بوجھ اور قید وبند کو اٹھا دیتا ہے ،پس جولوگ اس پر ایمان لائے،اس کا احترام کیا ،اس کی امداد کی اوراس نور کا اتباع کیا جواس کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی درحقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہے ٠ پیغمبر !کہدو اے لوگو!میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں ...''
یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے لئے کسی قسم کا امتیاز نہیں برتتے تھے اور ہر گز وہ شخص جو پہلے سے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کونہیں جانتاتھا ، اس میں اور دوسروں میں امتیاز نہیں برتا جاتا تھا ۔
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم اپنے گھر کاکام خودانجام دیتے تھے ،ہر ایک کو ذاتی طور پرشرف یابی بخشتے تھے، حاجتمندوں کی باتوں کوخود سنتے تھے ،تخت اور صدر محفل کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے ۔را ستہ چلتے وقت جاہ وحشم اور سر کاری تکلفات سے نہیں چلتے تھے ۔
اگر کوئی مال آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ہاتھ میں آتا تو اپنے ضروری مخارج کے علاوہ باقی مال کو فقرا میں تقسیم کرتے تھے اور کبھی اپنی ضرورت کی اشیا ء کو بھی حاجتمندوں میں تقسیم کر کے خود بھوکے رہتے تھے اور ہمیشہ فقیرانہ زندگی گزارتے تھے اور فقرا ء کے ساتھ ہم نشیں ہوتے تھے ،لوگوں کے حقوق کی دادرسی میں کبھی غفلت اور لاپر وائی نہیں کرتے تھے ،لیکن اپنے ذاتی حقوق میں زیادہ تر عفو وبخشش سے کام لیتے تھے ۔
جب فتح مکہ کے بعد قریش کے سرداروں کو آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا ،توآپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے کسی قسم کی تندی اور سختی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ سبھی کو عفو کیا ،جبکہ ہجرت سے پہلے انہوں نے مستقل آپصلىاللهعليهوآلهوسلم پرظلم کئے تھے اور ہجرت کے بعد بھی فتنے برپا کر کے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ساتھ خونین جنگیں لڑی تھیں ۔آپصلىاللهعليهوآلهوسلم اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اہل بیت پر خدا کا درودو سلام ہو۔
بخوبی جان لیناچاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور توحید کے نشر کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رکھتے تھے ،اور اچھے اخلاق ،خندہ پیشانی اور واضح ترین استد لال وبرہان سے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اسی روش پر عمل کرنے کی نصیحت فر ماتے تھے ،چنانچہ خدائے متعال آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کواس طرح حکم فر ماتا ہے:
( قل هذه سبیلی ادعوا الی اللّه علی بصیرة انا و من اتّبعنی ) ۔ (یوسف١٠٨)
''آپ کہدیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے''
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم اس امر کی طرف انتہائی توجہ رکھتے تھے کہ اسلامی معاشرہ میں ہر فرد (اگر چہ غیر مسلمان اور اسلام کے ذمہ دار میں ہو )اپنا حق حاصل کرے اور الہی قوانین کے نفاذ میں کسی قسم کا استثنا پید اہونے نہ پائے اور حق و عدل کے سامنے سب مساوی ہوں ،کوئی کسی پر (تقوی کے علاوہ )کسی قسم کا امتیاز نہ جتلائے اورمال ودولت یاحسب ونسب اور عام قدرت کے بل بوتے پر کسی پر ترجیح حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے،فخر نہ جتائے اور معاشرے کے مالدار لوگ کمزوروں اورمحتاجوں پر زبر دستی نہ کریں اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کریں ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے ،اور اٹھنے ،بیٹھنے اور راستہ چلنے میں ہر گز تکلفات سے کام نہیں لیتے تھے ۔اپنے گھریلو کام بھی انجام دیتے تھے ،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے پاس محافظ ونگہبان نہیں تھے ۔لوگوں کے درمیان عام شخص جیسے لگتے تھے ،جب لوگوں کے ہمراہ چلتے تھے تو کبھی آگے نہیں بڑھتے تھے، جب کسی محفل میں داخل ہوتے تو نزدیک ترین خالی جگہ پر بیٹھ جاتے،اصحاب کو نصیحت فرماتے تھے کہ دائرے کی صورت میں بیٹھیں تاکہ محفل صدرنشین کی حالت پیدانہ کرے،جس کو دیکھتے ، چاہے عورت ہو یا بچہ سب کو سلام کرتے تھے ۔ایک دن آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کاایک صحابی آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے سامنے خاک پر گرکر سجدہ کرنا چاہتا تھا توآپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا:کیا کر رہے ہو؟یہ قیصروکسری کی روش ہے اور میری شان پیغمبری اور بندگی ہے،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنے صحابیوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ حاجتمندوں کی حاجتوں اور کمزوروں کی شکا یتوں کو مجھ تک ضرور پہنچائیں اوراس سلسلہ میں کوتاہی نہ کریں۔کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نصیحت لوگوںکو کی وہ غلاموں اور عورتوں کے بارے میں تھی ۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چند نکات
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نیک اخلاق میں دوست ودشمن میں معروف ومشہور تھے۔ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا کہ،ظالم دشمنوںاورنادان دوستوں کی بد اخلاقی اورآزار و بے ادبی وجسمانی اذیتوںکے باوجو د آپ کی تیوری پر بل نہ آتے تھے اورناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔سلام کرنے میں عورتوں بچوں اور ماتحتوں پر سبقت کرتے تھے ۔جب آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو خدا کی طرف سے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رہبری کرنے کی ذمہ داری ملی ،توآپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فریضہ کی انجام دہی میں ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کی اور اپنی انتھک کوششوں کی بنا پر کبھی آرام سے نہیں بیٹھے ۔ہجرت سے تیرہ سال پہلے مکہ میں ،مشرکین عرب کی طرف سے ناقابل برداشت مشکلات اوراذیتوں کے باوجودعبادت ودین خدا کی تبلیغ میں مسلسل مشغول رہتے تھے۔ہجرت کے بعددس سال کے دوران بھی دین کے دشمنوں کی طرف سے روزبروز مشکلات اور یہودیوں اور مسلمان نمامنا فقوں کی طرف سے روڑے ا ٹکا ئے جاتے رہے۔
معارف دین اور قوانین اسلام کوحیرت انگیز وسعت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا دشمنان اسلام سے ٨٠ سے زیادہ جنگیں لڑیں ۔
اس کے علاوہ اسلامی معاشرے کی باگ ڈور ۔جو ان دنوں تمام جزیرئہ نما عرب پر پھیلا ہوا تھا۔آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ہا تھوں میں تھی ، یہاں تک کہ لوگوں کی چھوٹی سے چھوٹی شکایتوں اور ضرورتوں کو بھی کسی رکاوٹ کے بغیر خود بر طرف فرماتے تھے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور شہامت کے بارے میں اتناہی کافی ہے کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اس وقت تن تنہا حق کی دعوت کا پرچم بلند کیا ،جبکہ دنیابھر میں ظلم وزبردستی اورحق کشی کے علاوہ حکومت نہیں کی جا سکتی تھی آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے وقت کے ظالموں سے بے انتہا جسمانی اذیتیں اور تکلفیں اٹھائیں ،لیکن یہ سب چیزیں آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے عزم وارادے میں سستی اور کمزوری پیدا نہ کرسکیں اورآپ نے کسی جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائی ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پا کیزہ نفس کے مالک تھے ،فقیرانہ لباس پہنتے تھے اور سادہ زندگی گزار تے تھے،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اورنوکروںوغلاموں کے درمیاں کوئی فرق نظرنہیں آتا تھا ،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے پاس کافی مال ومنال آتاتھالیکن اسے مسلمان فقراء میں تقسیم کرتے تھے ،تھوڑی مقدار میں اپنی اور اپنے اہل وعیال کی زندگی کے لئے لیتے تھے۔بعض اوقات کئی دنوں تک آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا اورپکاہوا کھانانصیب نہیں ہوتا تھا ۔زندگی میں صفائی خاص کرعطر کو بہت پسند فرماتے تھے ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی حالت نہیں بدلی ،جو تواضع و فروتنی آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی ابتدائی زندگی میں تھی وہی آخر تک رہی اور اس گراں قدر حیثیت کے مالک ہونے کے باوجود،ہر گز اپنے لئے ایسے امتیاز کے قائل نہ ہوئے جس سے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی اجتماعی قدر ومنزلت دکھائی دیتی ۔آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کبھی تخت پر نہیں بیٹھے ، محفل کی صدرنشین کو کبھی اپنے لئے مخصو ص نہ کیا ،راستہ چلتے وقت کبھی دوسروں سے آگے نہیں بڑھے اور کبھی حکمراں اور فرمانرواکا قیافیہ اختیار نہیں کیا ۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ کسی عام محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے ،تو اگر کوئی اجنبی شخص آپصلىاللهعليهوآلهوسلم سے ملا قات کے لئے آجا تا تھاتو وہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو نہیں پہچان پا تا تھا اوروہاں پر موجود لوگوںسے مخاطب ہو کر کہتا تھا :آپ میں کون شخص پیغمبر خداصلىاللهعليهوآلهوسلم ہے ؟پھر لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے تھے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی اور کبھی بیہودہ کلام نہیں کیا،کبھی قہقہہ لگا کر نہیں ہنسے اور ،کوئی ہلکا اور بے فائدہ کام انجام نہ دیا ۔غور وخوض کو پسند فرماتے تھے ،ہردردمند کی بات اور ہرایک کا اعتراض سنتے تھے ،پھر جواب دیتے تھے ،کبھی کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے ،آزاد تفکر میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے ،لیکن اشتباہ کرنے والے کو اشتباہ کو واضح کر کے اس کے اندورونی زخم پر مرہم لگاتے تھے ۔
پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان اور انتہائی نرم دل تھے ،ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے تھے ،لیکن بد کاروں اور مجرموں کو سزا دینے میں نرمی نہیں کرتے تھے اورسزا کوجاری کرتے وقت اپنے اور پرایے اور بیگانہ وآشنا میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے ۔
ایک انصاری کے گھر میں چوری ہوئی تھی ،اس سلسلہ میں ایک یہودی اور ایک مسلمان ملزم ٹھہرائے گئے ۔انصار کی ایک بڑی جماعت آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے پاس آئی اوردبائوڈالا کہ مسلمانوں خاص کر انصارکی آبرو بچانے کے لئے ،صرف یہودی کو سزادی جائے ۔کیونکہ انصار کے ساتھ یہودیوں کی کھلم کھلادشمنی تھی ۔لیکن آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے حق کو ان کی مرضی کے برخلاف ثابت کیا ،یہودی کی آشکارا طور پر حمایت کی اور مسلمان کو سزا سنادی ۔
جنگ بدر کی پکڑ دھکڑ کے دوران مسلمانوں کی صفوں کو منظم کرتے ہوئے جب آنحضرت ایک سپاہی کے پاس پہنچے جو تھوڑ اسا آگے تھا ،تو آپ نے اپنے عصا سے اس سپاہی کے پیٹ پر رکھ کر تھوڑاساڈھکیلاتاکہ ا پیچھے ہٹے اور صف سیدھی ہو جائے ۔سپاہی نے کہا: یارسول اللہ ! خدا کی قسم میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔میں آپصلىاللهعليهوآلهوسلم سے قصاص لوں گا۔آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنے عصا کو اس کے ہاتھ میں دیدیا ،اور اپنے شکم سے لباس ہٹادیا اور فر مایا آئو قصاص لے لو ۔سپاہی نے بڑھ کر آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے شکم مبارک کو چوما اور کہا :''میں جانتا ہوں کہ آج قتل کیا جائوں گا ،میں اس طرح آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بدن مقدس کا بوسہ لینا چاہتا تھا(۱) ''اسکے بعد اس سپاہی نے دشمن پر حملہ کیااور تلوار چلائی یہاں تک کہ شہید ہوگیا ۔
مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت
عالم بشریت ،کائنات کے دوسرے ان تمام اجزاء کے مانند تغیر وتبدل کی حالت میں ہے کہ جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔اور لوگوں کی بناوٹ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان میں مختلف سلیقے وجود میں آئے ہیں کہ جن کے نتیجہ میں لوگ ،فہم وادراک کی تیزی وکندی ،حفظ اورافکار کی فراموشی میں مختلف ہیں ۔
اس لحاظ سے ،عقائد اوراسی طرح رسو مات اور ایک معاشرہ میں جاری قوانین کی ایک پائدار بنیاد کی حفاظت کے لئے اگر باایمان وقابل اعتماد نگہبان ومحافظ نہ ہوں ،تووہ تھوڑی ہی مدت کے بعد تغیر وتبدل اور انحراف کا شکار ہو کر نابود ہو جائیں گے ۔مشاہدہ اور تجربہ ہمارے لئے اس مسئلہ کو واضح ترین صورت میں ثابت کرتا ہے ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عالمی اورابدی دین کو در پیش خطرے سے بچانے کے لئے پائدارو محکم سند اور با صلا حیت محافظ کے طورپرکتاب خدا اور اپنے اہل بیت علیہم السلام کو لوگوں کے کے سامنے پیش کیا .چنانچہ شیعہ اور سنی راویوں نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار ہا فرمایا :''میں اپنے بعد،
خدا کی کتاب اور اہل بیت کو تم لوگوں میں چھوڑ رہا ہوں ،یہ دونوںکبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے ،جب تک تم لوگ ان سے متمسک رہو گے،گمراہ نہیں ہوگے ۔''(۲)
پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور جانشینی کا مسئلہ
وہ آخری شہر ،جس کا فتح ہو نا اسلام کے جزیرئہ نما عرب پر تسلط جمانے کا سبب بنا،شہر ''مکہ'' تھا،کہ جہاں پر حرم خدا اور کعبہ ہے ۔یہ شہر ٨ھ میں اسلامی لشکر کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس کے فوراہی بعد شہر طائف بھی فتح ہوا ۔
١٠ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ حج انجام دینے کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔حج کے اعمال اور لوگوں تک ضروری تعلیمات پہنچانے کے بعد مدینہ روانہ ہوئے ۔راستہ میں ''غدیر خم ''نامی ایک جگہ پر قافلہ کو آگے بڑھنے سے روکنے کاحکم فرمایا اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ایک لاکھ بیس ہزار حاجیوں کے درمیان حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا اور تمام لوگوں میں حضرت علی کی ولایت اور جانشینی کا اعلان فرمایا ۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام سے اسلامی معاشرہ میں والی کا مسئلہ۔کہ جو اسلامی معاشرہ میں مسلمانوں کے امورپر ولایت رکھتا ہے اور کتاب وسنت اور دینی معارف اور قوانین کی حفاظت کرتاہے۔حل ہوا اور آیئہ شریفہ:( یا ایّها الرّسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک وان لم تفعل فما بلّغت رسالته ) ۔ (مائدہ ٦٧)کا حکم نافذ ہوا ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مد ینہ لو ٹے،ستّردن کے بعد،تقریبا ٢٨ماہ صفر ١١ھ کو رحلت فرمائی ۔
____________________
١۔طبری ،تاریخ ،ج ٢،ص١٤٩
۲۔(انی تارک فیکم الثقلین !کتاب اللّه وعترتی اهل بیتی !ما ان تمسکتم بهمالن تضلوابعدی ابداوانهمالن یفترقا حتی یرداعلی الحوض ۔ (غایة المرام،ص٢١٢الغدیر،ج١،ص٥٥)
قرآن مجید، نبوت کی سند
سب سے بڑی دلیل کہ جس کو پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے سند نبوت کے طور پر پیش کیا ہے نیز معارف اسلام یعنی اصول و فروع کے لئے ماخذ و مصدر ہے کہ جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ کتاب آسمانی یعنی قرآن مجید ہے ۔
قرآن مجید ،خدائے متعال کے کلام اور خطاب کا ایک مجموعہ ہے ،جو مقام کبریائی کی عزت وعظمت کے مصدر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے ذریعہ راہ سعادت کی نشاندہی کی گئی ۔
قرآن مجید عالم بشریت کو ایسے علمی وعملی احکام و قوانین کی نشاندہی کرتا ہے کہ جن پر عمل کر کے انسان دنیا وآخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے ۔
قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ،حجت اورایک ایسی سند وثبوت ہے جو دشمن کو ہر جہت سے عاجز اور کمزور بنا دیتا ہے اور ہر قسم کے عذر، اعتراض،نزاع اورلڑ ا ئی جھگڑے کے راستہ کو اس کے لئے بند کردیتاہے اور اپنے مقاصد کوواضح ترین صورت میں ثابت کرتا ہے ۔
قرآن مجید اپنے مقاصد میں لوگوں کو آنکھیں بند کر کے تقلید کر نے کی دعوت دینے کے بجائے اس کے ساتھ عام اور خدادادمنطق کی زبان میں بات کرتا ہے اورکچھ معلومات کی یاد دہانی کرتا ہے ،جنھیں انسان خواہ نخواہ اپنی فطرت سے درک کرتا ہے ،اوریاد دہانی کراتاہے کہ انسان کبھی ان کو قبول کرنے اور اعتراف کرنے سے پہلو تہی نہیں کرسکتا ہے۔خدائے متعال فرماتا ہے :
(إ( نّه لقول فصل٭وماهو بالهزل ) (طارق١٤١٣)
''بیشک یہ قول فیصل ہے اور مذاق نہیں ہے ۔''
قرآن مجید ایک مطلب کو بیان کرتا ہے ،جہاں تک اس کی دلالت کی شعاعیں پھیلتی ہیں،ہمیشہ اورسبھی کے لئے زندہ وپایندہ ہے ،نہ لوگوں کی معمولی باتوں کے مانند بعض جہات سے فہم وتفکر کے ذریعہ اس پر احاطہ کیا جاسکتا ہے اور بعض لحاظ سے غفلت اور لاپر وائی کا اس میں امکان ہو،بلکہ یہ ایسے خدائے متعال کا کلام ہے جو ہرظاہروبا طن اور مصلحت ومفسدہ سے آگاہ ہے ۔
اس لحاظ سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی حقیقت پسندانہ آنکھوں کو کھول دے اور ہمیشہ ان دوآیئہ شریفہ کو مد نظر رکھے ،خدا کے کلام کو زندہ اور پائندہ جانے ۔اورجو دوسروں نے سمجھ کر بیان کیا ہے ،اس پر اکتفانہ کرے ،آزادفکر کے راستے کواپنے اوپر بند نہ کرے، کیونکہ یہ انسانیت کا تنہا خصوصی سر مایہ ہے اور قرآن مجید اس پر عمل کرنے کی بہت تاکید کر تا ہے ۔قرآن مجید ہمیشہ اورسبھی کے لئے قول فیصل اور ایک زندہ حجت ہے اوریہ کتاب کسی خاص گروہ کے فہم تک محدود ومنحصرنہیں ہو سکتی ہے ،خدائے متعال فرماتا ہے :
( ولا یکونوا کالّذ ین اوتوا الکتٰب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم ) ۔ (حدید ١٦)
''اوروہ(مسلمان)ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں ،جنھیں کتاب دی گئی توایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہوگئے ''
قرآن مجید لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کی طرف پلٹیں ،حق کو قبول کریں ،یعنی پہلے اپنے آپ کو بلا قید وشرط حق کو قبول کرنے پرآمادہ کریں اور جب دیکھیں کہ یہ حق ہے اور ان کی دنیوی واخروی سعادت ومنافع اسی میں ہے ،تو شیطانی وسوسوں اور ہواوہوس کی آواز کی طرف کان دھرے بغیر اسے قبول کریں ۔
اس کے بعد،اسلامی معارف کو اپنے زندہ شعور کے سپرد کریں ،اگر دیکھیںکہ یہ حق ہے اور انھیں قبول کر کے ان پر عمل کرنے میں ان کے لئے حقیقی مصلحت وآسودگی ہے تو ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور البتہ اس صورت میں انسانی معاشرے میں عام ہونے والی زندگی کی روش اور دین،ایسے ضوابط اور احکام ہوںگے جنھیں انسان اپنے فطری میلانات کے تحت چاہتا ہے ۔
آخر ایک یکسان روش ہوگی جس کے تمام اجزاء ومواد انسان کی خصوصی بناوٹ سے مکمل ہم آہنگ ہوں گے اورتضادوتناقض سے مکمل طورپر دور ہوںگے،نہ ایک ایسی متضاد روش جو کہیں پر معنویات سے وجود میں آتی ہو اور کہیں پر مادیات سے اور کہیں عقل سلیم کے موافق ہو اور بعض مواقع پر ہواہوس کے تابع ہو ۔خدائے متعال قرآن مجید کی توصیف میں فرماتا ہے :
(۔۔.( یهدی الی الحق والی طریق مستقیم ) (احقاف ٣٠)
''(یہ کتاب)حق وانصاف اورسیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرنے والی ہے ''
نیز فرماتا ہے :
( انّ هذاالقرآن یهدی للّتی هی اقوم ) ۔ (اسرائ٩)
''بیشک یہ قرآن اس راستہ کی طرف ہدایت کر تا ہے جو بالکل سیدھا ہے ...''
ایک دوسری آیت میں اسلام کی اس توانائی کے سبب کو اسلام کے انسان کی خلقت کے مطابق ہونے کو بتاتاہے کیونکہ بالکل واضح ہے کہ جوروش وراستہ انسان کی فطری خواہشوں اورحقیقی ضرورتوں کو پورا کرے، وہ انسان کو بہترین صورت میں کامیاب وخوش بخت بناسکتا ہے:
( فاقم وجهک للدّین حنیفا فطرت اللّه الّتی فطر النّاس علیها لا تبدیل لخلق اللّه ذلک الدّین القیّم ) ۔ (روم٣٠)
''آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الٰہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا اورخلقت الہیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔یقینا یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے ''
نیزفرماتا ہے :
(۔..( کتٰب انزلنه الیک لتخرج النّاس من الظّلمات الی النّور ) ۔ (ابراہیم ١)
''یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خداسے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے...''
قرآن مجید ،لوگوں کو ایک ایسے راستہ کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو خود بھی روشن ہواورمنزل مقصودکو بھی واضح طور پر دکھائے ،یہ راستہ قطعا وہی راستہ ہوگاجو انسان کی فطری خواہشات،جواسکی واقعی ضرورتیں ہیں ..کو پورا کرسکے اورعقل سلیم کی نظرسے موافق ہونا چاہئے اوریہ وہی دین فطرت ہے جسے ''اسلام ''کہتے ہیں۔
لیکن جس روش کی بنیادمعاشرہ کی ہواوہوس اور شہوانی خواہشات کے لئے یا معاشرے کے بااثر افراد کے ذریعہ رکھی گئی ہو ،اسی طرح جو روش اسلاف کی اندھی تقلید پربنی ہو، اسی طرح جو راہ وروش ایک پسماندہ اورناتواں ملت نے ایک توانا اورقدرتمند ملت سے حاصل کر کے عقل و منطق سے اس کی تحقیق کئے بغیر جو کچھ اس سے حاصل کیا ہے، اسے آنکھیں بند کرکے قبول کر کے خود کواسکے مشابہ بنائے ،ایسی روشیں تاریکی میں ڈوبنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور حقیقت میں یہ ایک ایسے راستہ پر چلنے کے مترادف ہے کہ جہاں منزل مقصودتک پہنچنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے ،چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :
( او من کان میّتا فاحیینه وجعلنا له نوراً یمشی به فی النّاس کمن مثله فی الظّلمات لیس بخارج منها ) ... ) (انعام١٢٢)
''کیاجوشخص مردہ تھا پھرہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور قراردیا جس کے سہارے وہ لوگوںکے درمیان چلتا ہے اسکی مثال اسکی جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکل بھی نہیں سکتاہو...''
قرآن مجید کی اہمیت
قرآن مجید ایک آسمانی کتاب ہے جو عالمی وابدی دین اسلام کی پشت پناہ ہے ۔اس میں معارف اسلامی کے کلیات دلکش انداز میں بیان ہوئے ہیں ،اس لحاظ سے اس کی قدر وقیمت دین خدا کی قدروقیمت کے مساوی ہے ،وہ دین جس سے انسان کی حقیقی سعادت و خوشبختی وابستہ ہے ،وہ ہرچیز سے زیادہ قیمتی،اہم اوربلندہے بلکہ قدروقیمت میں کوئی چیز اس سے قابل موازنہ نہیں ہے ۔اسکے علاوہ قرآن مجید خدائے متعال کا کلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لافانی معجزہ ہے ۔
قرآن مجید کا معجز ہ
یقینا عربی زبان ،ایک قوی اور وسیع زبان ہے ،جو انسان کے باطنی مقاصد کو واضح ترین اور دقیق ترین صورت میں بیان کر سکتی ہے اور یہ اس خصوصیت میں مکمل ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔
تاریخ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عصر جاہلیت (قبل از اسلام )کے اعراب اکثر خانہ بدوش اور تہذیب وتمدن سے بے بہرہ اورزندگی کے بیشتر حقوق سے بالکل محروم تھے ۔لیکن وہ قدرت بیان اورکلام کی فصاحت وبلاغت میں ایک بلندمقام رکھتے تھے ،چنانچہ تاریخ کے صفحات میں ان کا حریف پیدانہیں کیا جاسکتا ۔
ادبیات عرب کے میدان میں ، فصیح کلام کی بہت قدروقیمت تھی اورادیبانہ اور فصیح کلام کا کافی احترام کیا جاتا تھا .اعراب جس طرح بتوں اوراپنے خدائوں کو خانہ کعبہ میں نصب کرتے تھے ،اسی طرح صف اول کے ادیبوں اورشعراء کے دلکش اشعار کو بھی کعبہ کی دیوارپر لٹکا تے تھے ۔اس کے باوجود کہ وہ ایک وسیع زبان کو ان تمام علا متوں اور دقیق قواعد وضوابط اور کم ترین غلطی اور اشتباہ سے استعمال کرتے تھے اور کلام کی فصاحت وبلاغت میں کمال دکھاتے تھے ،جب ابتدائی ایام میں پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی چند آیتیں نازل ہوئیں ،تواعراب اور اس قوم کے ادیبوں اور سخنوروں میں ہلچل مچ گئی اورقرآن مجید کا دلکش اورپرُ معنی بیان کا دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ دل والوں کواپنافریفتہ بناکر رکھدیا اور وہ ہرفصیح کلام کو بھول گئے اور نامورشعراء جو اپنے اشعار کعبہ کی دیوار پر لٹکائے تھے ، انہیں اتاردیا۔
یہ خدائی کلام ،اپنی ابدی زیبائی و دلکشی سے ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا اور اپنی شیرین بیانی سے شیرین زبانوں پر تالا لگادیتا تھا ۔لیکن دوسری جانب مشرکوں اور بت پرستوں کے لئے انتہائی تلخ وناگوار تھا ،کیونکہ خدا کا کلام اپنے موثر بیان اور قطعی حجت سے دین توحید کو برہان واستدلال بخشتا تھا اورشرک وبت پرست کی روش کی سرزنش کر تا تھا ۔ جن بتوں کو لوگ خدا کہتے تھے ان کے سامنے نیازمندی کاہاتھ پھیلاتے تھے ، ان کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے ، قرآن ان کی مذمت کرتا اورانھیں پتھر اور لکڑی کے بے جان وبے فائدہ مجسمے سے تعبیر کر تاتھا ،وحشی اعراب جنہوں نے غروروتکبر میں غرق ہو کر اپنی زندگی کی بنیاد خونخواری اور ڈاکہ زنی پر ڈالی تھی ...کو حق پرستی کے دین اورعدالت وانسانیت کے احترام کی طرف دعوت دیتا تھا ،یہی وجہ تھی کہ اعراب جنگ و لڑائی کے راستہ سے سامنے آگئے اوراس شمع ہدایت کو خاموش کرنے کے لئے ہر ممکنہ کوشش کر تے رہے لیکن اپنی بے جاکوششوں میں ناامیدی و نا کامی کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔اوائل بعثت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولید نامی ایک ادیب اور فصاحت وبلاغت کے ماہر کے پاس لے گئے ۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورئہ''حم سجدہ''کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی ۔ولید اپنے تکبر وغرورکے باوجود بڑی سنجیدگی سے سن رہاتھا ،یہاں تک کہ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اس آیہء شریفہ کی تلاوت فرمائی :
( فان اعرضوافقل انذر تکم صٰعقة مثل صٰعقة عاد وثمود )
(فصلت١٣)
''پھر اگر یہ اعراض کریں تو کہدیجئے کہ ہم نے تم کو ویسی ہی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد وثمود پر نازل ہوئی تھی ۔''
جوں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ شریفہ کی تلاوت کی ،ولید کی حالت بگڑ گئی ،اس کابدن کاپننے لگا،اس کے ہوش اڑ گئے ،محفل درہم برہم ہوگئی ،اور لوگ متفرق ہو گئے۔
اس کے بعد،کچھ لوگ ولید کے پاس آئے اور اس سے شکوہ کیا اور کہا کہ تم نے ہمیں محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم کے سامنے رسواکر کے رکھدیا !اس نے جواب میں کہا :خدا کی قسم ہر گز نہیں !تم لوگ جانتے ہو کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں اور کوئی لالچ بھی نہیں رکھتا ہوں اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں سخن شناس ہوں ،جو باتیں میں نے محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم سے سنیں ان میں لوگوں کی باتوں کی شباہت نہیں پائی جاتی ،یہ دلفریب اور دلکش کلام تھا ،نہ اسے شعر کہہ سکتے ہیں اور نہ نثر ،با معنی اور عمیق کلام ہے ۔ اگر میں اس کلام کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کرنے پر مجبورہی ہوںتو مجھے تین دن کی مہلت دیں تا کہ میں اس پر غور کرسکوں ۔جب تین دن گزرنے کے بعد اس کے پاس گئے تو ولید نے کہا :محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم کا کلام سحر وجادو ہے جو دلوں کو اپنا فریفتہ بنا لیتا ہے۔
مشرکین ولید کی راہنمائی پر قرآن مجید کو سحر وجادو کا نام دیکر اس کو سننے سے پرہیز کرتے تھے اور لوگوں کوبھی اسے سننے سے منع کرتے تھے ،بعض اوقات جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدالحرام میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے ،تو کفا رشور مچا تے اور تالیاں بجاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن نہ سکیں۔
اس کے باوجود کہ وہ لوگ قرآن مجید کے فصیح اوردلکش بیان کے عاشق ہوئے تھے ،اکثر و بیشتر آرام سے نہیں بیٹھتے تھے اور رات کی تاریکی سے استفادہ کرکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دیوار کے پیچھے جمع ہوکر قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے تھے ،پھر سر گوشی میں ایک دوسرے سے کہتے تھے :اس کلام کو مخلوق کا کلام نہیں کہا جاسکتا ہے!خدائے متعال اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:
( نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوی اذ یقول الظٰلمون ان تتّبعون الا رجلا مسحوراً ) (اسراء ٤٧)
''ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کرسنتے ہیں تو کیاسنتے ہیں اورجب یہ باہم رازداری کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے بھی جانتے ہیں، یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں تم لوگ ایک جادو زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو۔''
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ،بعض اوقات کعبہ کے نزدیک لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی طرف دعوت دیتے تھے ،عرب کے سخنور جب آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے نزدیک سے گزرتے تھے تو جھک کر گزرتے تھے۔تاکہ دیکھے اور پہچانے نہ جائیں ،چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے:
( الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوامنه ) ۔ (ہود ٥)
''ترجمہ کا خلاصہ :وہ اپنے آپ کو پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم سے چھپانے کے لئے جھک جاتے ہیں ۔''
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمتیں کفار ومشرکین نے نہ صرف قرآن مجید کو سحر وجادو کہا ،بلکہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دعوت کو ہی جادو کہتے تھے ۔جب بھی آپصلىاللهعليهوآلهوسلم لوگوں کو راہ خدا کی دعوت دیتے تھے اور انھیں کچھ حقائق کی یاد دہانی کراتے تھے یاکوئی وعظ ونصیحت فرماتے تھے تو کفار کہتے تھے :''جادوکر رہاہے ''جبکہ تمام حالات میں ،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم ان کے لئے ایسے مسائل کوواضح فرماتے تھے ،کہ وہ خداداد فطرت اور انسانی شعور سے ان کی حقیقت کو درک کرتے تھے اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم انہیں سیدھا اور واضح راستہ دکھاتے تھے کہ انسانی معاشرے کی سعادت وکامیابی کو جادو نہیں کہا جاسکتا ہے۔
کیا یہ کہنا جادو ہے ؟کہ''اپنے ہاتھوں سے پتھر ولکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش نہ کرو اور اپنے فرزندوں کو انکی قر بانی نہ کرو اور خرافات کی پیروی نہ کرو ''اور کیا پسندیدہ اخلاق ،جیسے سچائی ،صحیح ،خیر خواہی ،انسان دوستی ،صلح وصفا،انصاف ، عدالت اور انسانی حقوق کے احترام کو جادو کہا جاسکتا ہے؟خدائے متعال اپنے کلام پاک میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :
(۔۔.( ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولنّ الّذین کفروا انّ هذالّا سحر مبین ) (ہود٧)
ترجمہ کاخلاصہ :''جب آپ کفار سے کہتے ہیں کہ :موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائو گے تو کہتے ہیںکہ جادو کرتا ہے''۔
قرآن مجید کی مشرکین کو مناظرہ کی دعوت
کفارومشرکین کہ جن کے دلوں میں بت پرستی نے جڑپکڑ لی تھی ،اسلام کی دعوت کو قبول کرنے اور حق وحقیقت کے سامنے ہتھیا ر ڈالنے کے لئے ہر گز تیار نہیں تھے لہذاپیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تر دید کرتے ہوئے کہتے تھے :''یہ جھوٹا ہے اور جس قرآن کوخدا سے نسبت دیتا ہے ،یہ ا س کا اپنا کلام ہے''
اس تہمت کو دور کرنے کے لئے قرآن مجید نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عربوں کے میدان فصاحت وبلاغت کے ہراول دستے کو مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے ان سے چاہا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کا شک و شبہہ صحیح ہے اور وہ سچ کہتے ہیں توقرآن مجید کے کلام کے مانند کلام لے آئیں اور اس طرح اسلام کی دعوت کے بے بنیاد ہونے کو ثابت کریں چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :
( ام یقولون َتقَّوله بل لا یو منون ٭فلیاّ توا بحدیث مثله ان کانوا صادقین ) (طور٣٤٣٣)
''یا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن گڑ ھ لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگر یہ اپنی بات وںمیں سچے ہیں تو یہ بھی ایساہی کوئی کام لے آئیں ۔''
( ام یقولون افترٰیه قل فتوا بسورةٍ مثله وادعوا من استطعتم من دون اللّه ان کنتم صٰدقین ) (یونس ٣٨)
''کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے گڑھ لیا ہے تو کہدیجئے کہ تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آئو اورخدا کے علاوہ جسے چاہو اپنی مدد کے لئے بلا لو اگر تم الزام میں سچے ہو ۔''
کفار ومشرکین عرب ،جو سخنوری کے استاد اور ملک فصاحت و بلاغت کے فرمانرواتھے ،سخنوری میں اس تکبر وغرورکے باوجود اس دعوت کو قبول کرنے سے پہلو تہی کرتے ہوئے مقابلہ سے چشم پوشی کی اور کلام کے مقابلہ کوخونین مقا بلہ میں تبدیل کرنے پر مجبورہوئے یعنی ان کے لئے رسوائی اور مقابلہ کی نسبت قتل ہونا زیادہ آسان تھا ۔
عرب سخنور قرآن مجید کا جواب لانے سے عاجز ہوئے ،نہ صرف نزول قرآن کے زمانے میں زندگی گزارنے والے ،بلکہ جو نزول قرآن کے زمانے کے بعد پیداہوئے وہ بھی اس کا کوئی جواب نہ لا سکے اور مقابلے کے بعد شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے ۔انسان کی فطرت ہمیشہ اس چیز کی طرف مائل ہوئی ہے کہ اس سے کوئی شا ہکار یاہنر ظاہر ہو جائے اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے ،اگرچہ یہ کارنامہ مکہ بازی اور رسی کھینچنے کے مانند معاشرہ میں براہ راست اثربھی نہ رکھتا ہو ،پھر بھی لوگوں کی ایک جماعت اس کی جیسی مثال یااس سے بہترمثال پیش کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بھی گھات میں کچھ لوگ ہمیشہ رہے ہیں کہ اگر اس آسمانی کتاب سے مقابلہ کرنے کی فرصت مل جائے تو اس سے گریز نہ کریں گے۔
یہ لوگ مقابلہ سے عاجز آچکے تھے اور سحرو جادو کو بہانہ بناکر یہ نہیں کہہ سکے کہ قرآن مجید جادو ہے ،کیونکہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو خاصیت کے مطابق حق کو باطل اور باطل کو حق ظاہر کرتا ہے ،جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کے روپ میں پیش کرتا ہے اور اگر قرآن مجید اپنے زیبالحن اور فصیح نظم سے دلوں کو جذب کرتا ہے تو یہ اس کی فطری خاصیت کی زیبائی ہے اور علم جادو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے .اگر لفظ کے ذریعہ کچھ مقاصد کی طرف دعوت دیتا ہے اور کچھ معارف کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ انسانی شعور اور خداداد فطرت سے ان کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور لوگوں کو کچھ رفتار وکردار کا جیسے :حق شناسی ،نیک نیتی ،عدل وانصاف اور انسان دوستی کو قبول کرنے پر مجبور کرے تو ان کی تعریف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ۔
چونکہ قرآن مجید،حقیقت کو بیان کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے ،اس لئے یہ لوگ عاجز ہو کر یہ بھی نہ کہہ سکے ہیں کہ قرآن مجید کلام بشر سے مافوق ہے اس لئے کہ زیبائی، دلکشی ،بلا غت اور کشش میں بے نظیر ہے اور یہ اس کے کلام خدا ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی ہے ۔
دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ہر ایک صفت یامہارت ،جیسے جرئت ،شجاعت، پڑھنا اور لکھنا وغیرہ جو قابل ترقی ہے ، لا محالہ تاریخ بشریت میں ان میں سے ایک غیر معمولی ذہنیت والا مقابلہ میں جیت کر اول آتا ہے ،کیا حرج ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی بول چال کے اس مقابلہ میں کامیاب قرار پا کر فصاحت وبلاغت میں اول آئیں ،اس صورت میں آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کا کلام باوجود اس کے کہ کلام بشر ہے نا قابل منا قشہ ہو گا۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر سخن وروں نے یہ بات نہیں کہی اور نہ ہی قرآن مجید کے حریفوں میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکا اور ثابت کر سکا ،کیونکہ ہر صفت یا مہا ر ت جو کسی غیر معمولی ہنر مند کے ذریعہ تر قی کے کمال تک پہنچتی ہے ،کچھ بھی آخر کار یہ ایک ایسا امر ہے جو انسان کی قابلیت اور استعداد سے وجود میں آتا ہے اور فطرت بشر کا نتیجہ ہے ،لہذا یہ کام دوسروں کے لئے ممکن ہے کہ اس غیر معمولی ذہین شخص کے نقش قدم پر چل کر ضروری سعی و کوشش کے ذریعہ اسی غیر معمولی ذہین انسان کی طرح ایک کارنامہ انجام دیں اگرچہ کسی بھی جہت سے اس سے بہتر نہ ہو۔
اس حالت میں مذکورہ غیر معمولی شخص ،جو راستہ کھولنے والا پہلا شخص ہے ،صرف پیشوااور پیش رو ہو سکتا ہے ،مثلا سخاوت میں حاتم طائی سے بلند کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے ،لیکن اس کے جیسا کام انجام دیا جاسکتا ہے ،خوشنویسی میں میر کے برابر اور نقاشی میں مانی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ،لیکن مناسب کوشش اور جستجو کے نتیجہ میں میر کے نہج پر ایک کلمہ لکھا جاسکتا ہے یا مانی کے اسلوب پر نقاشی کا ایک چھوٹاسا نمونہ بنایا جاسکتا ہے۔
اس عام قانون کی بناپر،اگر قرآن مجید فصیح و بلیغ ترین انسانی کلام (نہ کلام خدا) ہوتا تو دوسروں کے لئے خاص کر دنیا کے نامور سخن وروں کے لئے ممکن تھا کہ اسی اسلوب کا تجربہ کر کے ، ایک کتاب یا کم ازکم قرآن مجید کے سوروں کے مانند ایک سورہ کو بنا تے ۔
قرآن مجید نے مقابلہ کے مرحلہ میں لوگوں سے اپنے جیسے کلام کا تقاضا کیا ہے نہ کہ اس سے بہترکا:
( فلیا توا بحدیث مثله ) (طور٣٤)
( فاتوا بسورة مثله ) (یونس ٣٨)
( فاتوا بعشرسور مثله مفتریٰت ) (ہود١٣)
( لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ) (اسراء ٨٨)
قرآن مجید کی تعلیمات
قرآن مجید ٢٣سال کے عرصہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دوران تدریجا نازل ہو ااور انسانی معاشرہ کی ضرورتوں کا حل پیش کیا ۔
قرآن مجید ،ایک ایسی کتا ب ہے کہ خود اس کے بیانات کے مطابق لوگوں کی سعادت کی طرف رہنمائی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ۔صحیح اعتقاد،پسندیدہ اخلاق اور شائستہ عمل،جو انسان کے انفرادی واجتماعی سعادت کی بنیادیں ہیں ،کی فصیح زبان میں تعلیم دیتا ہے :
۔( ونزّلنا علیک الکتٰب تبٰیََاناً لکلّ شی ئ ) ۔ (نحل٨٩)
''اورہم نے آپ پرکتاب نازل کیا ہے جس میں ہرشے کی وضاحت موجود ہے ''
قرآ ن مجید نے اسلامی معارف کو خلاصہ کے طور پر بیان کیا ہے ۔ان معارف کی تفصیلات خاص کر فقہی مسائل کی وضاحت کے لئے ،لوگوں کو خانہ نبوت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی طرف ہدایت کرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے :
( وانزلنا الیک الذّکر لتبیّن للنّاس مانزّل الیهم ) ۔ (نحل ٤٤)
''اور آپ کی طرف بھی ذکر کو (قرآن)نازل کیا ہے تاکہ ان کے لئے ان احکام کو واضح کردیں جو ان کی طرف نازل کئے گئے ہیں...''
( وماانزلناعلیک الکتب الّا لتبیّن لهم الذی اختلفوا فیه ) ۔
(نحل٦٤)
''اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ آپ ان مسائل کی وضاحت کردیں جن میں یہ اختلاف کئے ہوئے ہیں ''
جان لیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خدا کی تفسیر اوردین کے معارف کی وضاحت کے لئے اپنے اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو اپنے کلام کے مانند قرار دیتے ہوئے فرمایا :
''قرآن مجید اور میرے اہل بیت قیامت کے دن تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوںگے اور جوبھی شخص قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہتا ہے ،اسے میرے اہل بیت کے دامن کو پکڑنا چاہئے۔''(۱)
قرآن مجید کی نظر میں علم وجہل
قرآن مجید میں علم ودانش کی جو تعریف اور غور و حوض کی جو تشویق کی گئی ہے ،وہ کسی اور آسمانی کتاب میں پائی نہیں جاتی ۔اسی طرح جہل ونادانی کی جو سرزنش کی گئی ہے وہ بھی قرآن مجید کے خصوصیات میں سے ہے ۔قرآن مجید نے علم ودانش کو زندگی اورجہل ونادانی کو موت سے تعبیر کیا ہے۔اور اسلام سے قبل فساد سے بھرے ماحول کو (جاہلیت) کا ماحول کہا ہے چنانچہ فرماتا ہے :
( هل یستوی الّذین یعلمون والّذین لا یعلمون )
(زمر٩)
''کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ؟''
(اومن کان میتا فاحیینہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظّلمات لیس بخارج منہا۔ (انعام ١٢٢)
'' جوشخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اوراس کے لئے ایک نور قراردیاجس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہوسکتی ہے جوتاریکیوں میں ہواوران سے نکل بھی نہ سکتا ہو ''۔
۔( فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور ) (حج ٤٦)
''...در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں کے اندر پائے جاتے ہیں ''
( لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون ) ۔..) ( اعراف١٧٩)
''...ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اورآنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں اور کان ہیں سنتے نہیں ہیں ۔یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں ...''
( ومایستوی الاعمی والبصیر٭ولا الظلمات ولا النور٭ولا الظل ولاالحرور ٭ ومایستوی الاحیاء ولا الاموات ) . (فاطر٢٢١٩)
''اور اندھے اور بینا برابر نہیں ہوسکتے اور تاریکیاں اور نوردونوں برابر نہیں ہوسکتے اور سایہ اوردھوپ دونوں بربر نہیں ہو سکتے اورزندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے...''
خدائے متعال اپنے کلام پاک کی بہت سی آیتوں میں ،انسان کوغوروفکر،اورتدبر کی ترغیب اور تشویق فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمانوں ،زمین اور ان میں موجود گوناگون مخلوق کی خلقت کے بارے میں غورو فکر کریں ، بالخصوص انسان کی خلقت کے بارے میں غور و فکر سے کام لیںگزشتہ ملتوں اور امتوں کی تاریخ ،آثار ،رسو مات ،عادات اور طور طریقوں،جو حقیقت میں مختلف علوم وفنون انسانی ہیں ،مطالعہ کی تاکید کرتا ہے اور ان مطالعات کے ذریعہ اپنی حقیقی سعادت حاصل کریں۔اور جان لینا چاہئے کہ فنی نظریات اور علمی مسائل کی چھان بین کرنا اس دنیا کی چند روزہ محدود زندگی کی فلاح وبہبود کے لئے نہیں ہے بلکہ علمی مطالعات کی بنیاد پر جاودانی حیات کی سعادت وآسائش حاصل کر نے ہونا چاہئے ۔
خالق کائنات کے بارے میں قرآن مجیدکی تعلیم
(...( افی اللّه شکّ فاطر السّموات والارض ) ۔ (ابراہیم ١٠)
''کیا تمھیں اﷲکے بارے میں شک ہے جو زمین وآسمان کا پیدا کرنے والاہے....؟''
وضاحت
دن کے اجالے میں تمام چیزیں آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو، گھر ، شہر، بیابان، پہاڑ، جنگل اور دریا کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب رات کااندھیرا چھاجاتا ہے تو تمام وہ چیزیں جو روشن و نمایاں تھیں ، اپنی روشنی کو کھو دیتی ہیں، ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ روشنی اپنی نہیں تھی بلکہ سورج سے مربوط تھی کہ وہ ایک قسم کے رابطہ کی وجہ سے انھیں روشن کئے ہوئے تھا۔ سورج بذات خود روشن ہے اور اپنے نور سے زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کو روشن اورنمایان کرتاہے۔ اگر ان اشیاء کی روشنی اپنی ہوتی تو ہرگز اسے کھو نہیں دیتیں۔
انسان اور دیگر تمام زندہ حیوانات اپنی آنکھوں، کانوں او ردیگر حواس سے اشیاء کو درک کرتے ہیں اور ہاتھ، پاؤں اور تمام اندرونی و بیرونی اعضاء سے سرگرمی انجام دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک مدت کے بعد حس و حرکت کو کھو کرکسی قسم کی سرگرمی انجام نہیں دے پاتے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ وہ مرجاتے ہیں۔
ہم اس چیز کامشاہدہ کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ ان جانداروں سے ظاہر ہونے والا شعور ، ارادہ اورتحرک ، ان کے جسم و بدن سے نہیںہے، بلکہ ان کی روح وجان سے ہے کہ جس کے نکل جانے کے بعد اپنی زندگی اورتحرک کو کھودیتے ہیں۔
اگر دیکھنے او رسننے کا تعلق مثلا صرف آنکھ او رکان سے ہوتا، تو جب تک یہ دو نوں عضو موجود ہوتے دیکھنا اور سننا بھی جاری رہنا چاہئے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
اسی طرح یہ عظیم کا ئنات کہ، جس کے اجزاء میں سے ہم بھی ایک جزو اور ایک وجود ہیں ہرگز شک و شبہ نہیں کرسکتے، کہ یہ کائنات اور ناقابل انکار خلقت ، اگر خود سے ہوتی، تو ہرگز اسے کھونہ دیتی، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اجزاء یکے بعد دیگرے اپنے وجود کو کھود یتے ہیں اورہمیشہ تغییر و تبدل کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ایک حالت کو کھوکرد وسری صورت اختیار کرتے ہیں۔
لہذاہمیں قطعی فیصلہ کرنا چاہئے کہ تمام مخلوقات کی خلقت اوروجود کا سرچشمہ کوئی دوسری چیز ہے جوان کا خالق اور پروردگار ہے اور جوں ہی خلقت کا رابطہ اس ذات سے ٹوٹ جاتاہے تو وہ نیستی و نابودی کے دریا میں غرق ہو جاتی ہے۔
قرآن مجید کا احترام
معارف و احکام کا خزانہ اسلام کی آسمانی کتاب ''قرآن مجید'' ہے، جسے خدائے متعال نے وحی کے ذریعہ اپنے پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم پرنازل فرمایاہے۔
قرآن مجید دنیا کے مسلمانوں کی مادی و معنوی زندگی کا نہایت گرانقدر پشتپناہ ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے امت کو بارہا اس کتاب کی اسی عنوان سے تاکیدکیاور مکر ر طور پر (خاص کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں ) لوگوں سے فرمایا ہے:
''میں اپنے بعد دوگراں بہا چیزیں تم لوگوں میں چھوڑ رہا ہوں جو قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی ، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہوگے، ہر گز گمراہ نہیں ہوگے، ان میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری عترت (اہل بیت) ہیں، جو قرآن مجید کو بیان کرنے والے ہیں''۔
قرآن مجید کے تقدّس اور احترام کے لئے اتناہی کافی ہے کہ یہ :
١۔ کلام خداہے۔
٢۔پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی قطعی ا ور زندہ سند ہے۔
٣۔ اسلام کے بنیادی قانون کا حامل ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں:'' قرآن مجید سے جدانہ ہونا، کیونکہ اس میں آپ کے اسلاف مستقیل میں آپ کے آنے والوںکے حالات موجود ہیں اور آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے حکومت کرتاہے۔''
راہ خدا میں جہاد او رفداکاری کے متعلق قرآن کا دستور
اجتماعی طریقے، ایک پھل دار درخت کے مانند ہیں، جسے شگوفہ دینے، پھلنے اور پھولنے کے لئے ایک مناسب زمیں میں لگا ناچاہئے، پھر اس کی آبیاری کرنی چاہئے تاکہ زمین میں اسکی جڑیں مضبوط ومستحکم ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ نشو و نما پائے اور اس میں مناسب موسم میں ، شکوفے نکلیں اورپھل آئیں۔
اسلام کایہ درخت سوفیصدی اجتماعی دین ہے،اس کے مکمل موثرہونے کے لئے مندرجہ ذیل مراحل کا طے کرنا ضروری ہے:
١۔ لوگ اسے قبول کریں۔
٢۔ تربیت کے ذریعہ ، اس کی حفاظت کی جائے تاکہ اپنی زندگی کو جاری رکھ سکے۔
٣۔ اس کے قوانین کی عملی مخالفت کی روک تھام کی جائے، اور حوادث کے گزند سے ان کی حفاظت کی جائے تا کہ اپنے آثار و فوائد کو انسانی معاشرہ میں پھیلاسکیں۔
بحث کا خاتمہ
بحث کے اختتام پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے صرف فصاحت و بلاغت کی دلکشی سے ہی دوسروں کو عاجز نہیں کیا ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی عاجز کیا ہے، کہ اس میں انسان کی تمام ضرورتوں کا حقیقی حل موجود ہے اور غیبی خبروں کے اعتبار سے بھی کہ جن کی اس نے پیشنگوئی کی ہے اور کچھ حقائق بیان بھی کئے ہیں اور دیگر جہات سے بھی جو اس آسمانی کتاب میں پائے جاتے ہیں، قرآن مجید چلینج کرتے ہوئے اعلان کرتاہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کرسکتے ہو۔
____________________
ا۔حقاق الحق،ج٩،ص٣٠٩۔٣٧٥۔
٣۔ معاد یا قیامت
''معاد'' ، دین مقدس اسلام کے تین اصولوں میں سے ایک اصول ہے اور اس مقدس دین کی ضروریات میں سے ہے۔
قرآن محید کی سیکڑوں آیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ہزاروں روایتیں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ خدائے متعال اپنے تمام بندوں کو موت کے بعد ایک معین دن کو پھرسے زندہ کرے گا اور ان کا اعمال کا حساب لے گا۔ پھر نیک کام انجام دینے والوں کو ابدی نعمت و لذت سے نوازے گا او ربدکرداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاکر ابدی عذاب میں مبتلا کرے گا۔
خدائے متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تمام گذ شتہ پیغمبروں نے، معاد اور روز قیامت کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کرائی ہے۔
دوسرے آسمانی ادیان بھی دین اسلام کے مانند، معاد کو ثابت کرتے ہیں، اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے توسط سے ہزاروں سال پر انی قبروں کی کھدائی سے ایسے آثار و علائم ہاتھ آرہے ہیں، جن سے معلوم ہوتاہے کہ پہلا اور ما قبل تاریخ کے بشر بھی انسان کے لئے موت کے بعد ایک قسم کی زندگی کا قائل تھا، اور یہاں سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے انسان اپنی سادہ سوچ سے بھی نیک انسانوں کے لئے جزا اور بد کاروں کے لئے سزا کا قائل ہے اور اس کے لئے ایک معین دن کو جانتے ہیں، چونکہ ایسادن اس دنیا میں موجود نہیں ہے ، اس لئے اس کا دوسری دنیا میں ہونا ضروری ہے ۔
ادیان و ملل کی نظر میں معاد
تمام وہ مذاہب، جو خد اکی پرستش کی دعوت دیتے ہیںاور انسان کونیک کام انجام دینے کا حکم اور بد کاری سے روکتے ہیں،وہ موت کے بعد معاد اور دوسری زندگی کے قائل ہیں، کیونکہ وہ ہرگز معین نہیں کرتے ہیں کہ نیک کا م کی اس وقت قدر وقیمت ہوگی جب نیکی کی جزا ہوگی اور چونکہ یہ جزا اس دنیا میں دیکھی نہیں جاسکتی ہے، اس لئے مرنے کے بعد دوسری دنیا او رایک دوسری زندگی میں اس کا ہونا ضروری ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس دن کو کہ جسے قیامت کا دن کہا ہے، پوری وضاحت سے ثابت کیا ہے اور اس کی ناقابل انکار حالت میں تعارف کراتاہے۔ اس پر اعتقاد کودین کے تین اصولوں میں سے ایک شمارکرتاہے اور قرآن مجید میں اسی مطلب کو سابقہ پیغمبروں کی دعوت سے نقل کرتاہے۔
اس کے علاوہ ، آثار قدیمہ کے کشف ہوئے بہت سے مقبروں سے کچھ ایسے آثار و علامتیں پائی گئی ہیں، جواس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ قدیم انسان موت کے بعد دوسری زندگی پر ایما ن رکھتا تھا او راپنے عقائد کے مطابق کچھ فرائض انجام دیتا تھا تاکہ لوگ اس دنیا میں آرام و آسائش حاصل کریں۔
قرآن مجیدکی نظر میں معاد
قرآن مجید نے سیکڑوں آیات میں معاد سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبہہ کی نفی کی ہے بصیرت کی افزائش اور عدم امکان کودور کرنے کے لئے اور اشیاء کی اولین خلقت اور خدا کی قدرت مطلقہ کے بارے میں بہت سے مواقع پر لوگوں کو یادد ہانی کراتے ہوئے فرماتاہے :
( اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین٭ و ضرب لنا مثلاونسی خلقه قال من یحی العظام و هی رمیم٭ قل یحییها الذی انشأها اوّل مرّة و هو بکل خلقٍ علیم ) (یٰسین٧٧۔٧٩)
''تو کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیداکیاہے اور وہ یکبارگی ہمارا کھلا ہوادشمن ہوگیاہے اور ہمارے لئے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرسکتا ہے؟ آپ کہدیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پید اکیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے ''
اور کبھی جاڑے میں مردہ ہوجانے والی زمین کو بہارمیں زندہ کر کے لوگوںکے انکار کو خدا کی قدرت کی طر ف متوجہ کیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے:
( ومن آیاته انک تری الارض خٰشعة فاذا انزلنا علیها الماء اهتّزّت وربت انّ الذی احیاهالمح الموتی انه علی کل شی ء قدیر ) (فصلت٣٩)
''اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف اور مردہ دیکھ رہے ہواور پھر جب ہم نے پانی برسادیا توزمین لہلہا نے لگی اور اس میں نشو و نما پیدا ہوگئی، بیشک جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کا زندہ کرنے والا بھی ہے اور یقینا وہ ہر شے پر قادر ہے ''
اور کبھی عقلی استدلال سے سامنے آکر انسان کی خدا داد فطرت کو اس حقیقت کے اعتراف پر ابھاراہے، چنانچہ فرماتا ہے:
( و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلاً ذلک ظنّ الذین کفروا فویل للّذین کفروا من النّار٭ ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصٰلحت کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجّار ) (ص٢٧۔٢٨)
''اورہم نے آسمان اور زمین او ران کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے (کیونکہ اگر مقصد یہی ہوتا کہ مثلاََ انسان پیدا ہوتا اور چند دن گھومنے کے بعد سوتا اور مرجاتا اور اس طرح دوسرا انسان آتا اور اس سلسلہ کی تکرار ہوتی تو کائنات کی خلقت بیہودہ اورایک کھلونے سے زیادہ نہ ہوتی ، جبکہ بیہودہ کا م خدا سے کبھی انجام نہیں پاتاہے) یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے اور کافروں کے لئے جہنم میں ویل کی منزل ہے کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد بر پا کرنے والوں جیسا قرار دیدیں یا صاحبان تقوی کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دیدیں ۔ (کیونکہ اس دنیا میں اچھا اور برا کام انجام دینے والے اپنے اعمال کی مکمل جزا نہیں پاسکتے، اگر دوسری دنیا نہ ہوتی، کہ جہاں ان دونوں گروہوں کو ان کی رفتار و کردار کے مطابق واقعی سزاملتی تووہ دونوں گروہ خدا کے نزدیک یکسان ہوتے اور یہ عدل الہی کے خلاف ہے)۔
موت سے قیامت تک
بدن مرتا ہے نہ کہ روح
اسلام کی نظر میں ، انسان ،روح وبدن سے تشکیل پائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔انسان کاجسم بھی بذات خود مادہ اورمادہ سے مر بوط قوانین کی تر کیبات میں سے ایک ہے ،یعنی اس کے لئے حجم اور وزن ہے۔اس کی زندگی ایک زمان و مکان میں ہے ،سردی ،گرمی وغیرہ سے متا ثر ہوتا ہے اور تدریجاََ بوڑھا او ر کمزور ہو تا ہے اور ایک دن خدائے متعال کے حکم سے پیدا ہوا تھا ،آخرکار ایک دن تجز یہ ہو کر نا بود ہو جا تا ہے۔
لیکن روح،مادی نہیں ہے اور مادہ کی مذکورہ خاصیتوں میں سے کوئی ایک اس میں نہیں پائی جاتی ہے،بلکہ علم ،احساس،فکر اور ارادہ کی صفت کے علاوہ دوسری معنوی صفات جیسے: محبت ،کینہ ،خوشی غم ،اور امید وغیرہ اس سے مخصوص ہیں ۔اور چونکہ روح میں مادہ کی مذکورہ خصوصتیں نہیں پائی جاتیں۔ لہذا معنوی خاصیتیں بھی مادی خاصیتوں سے الگ ہیں ،بلکہ دل ودماغ اور بدن کے دوسرے تمام اجزاء اپنی بے شمارسر گرمیوں میں روح اور معنوی صفات کے تابع ہو تے ہیں ،اور بدن کے اجزاء میں سے کسی ایک کوفرمانروا کا مرکز قرارنہیں د یا جاسکتا ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( ولقد خلقنا الا نسٰن من سلٰلةٍ من طین٭ ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ٭ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظٰما فکسونا العظٰم لحماً ثم انشأنه خلقا آخر... ) (مؤمنون١٤١٢)
''اور ہم نے انسا ن کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے ٠پھر نطفہ کو علقہ بنایا ہے اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے ،پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنادیا ہے ...''
اسلام کی نظر میں موت کے معنی
مذکورہ اصل کے مطابق اسلام کی نظر میں موت کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان نابود ہوتا ہے ،بلکہ یہ ہے کہ انسان کی روح لافانی ہے ،بدن سے اسکا رابطہ منقطع ہوجا تا ہے ، نتیجہ میں بدن نابود ہو جاتا ہے اور روح بدن کے بغیر اپنی زندگی کو جاری رکھتی ہے ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( وقالوأَ اذ ا ضللنافی الارض أَئِ نّا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون ٭قل یتوّٰفکم ملک الموت الذی وُکِّل بکم ) ...) (سجدہ١١١٠)
''اور کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں گم ہو گئے (مر گئے)تو کیا نئی خلقت میں پھر ظاہر کئے جائیں گے ۔بات یہ ہے کہ یہ اپنے پرور دگارکی ملا قات کے منکر ہیں ۔آپ کہدیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک پہنچائے گا جوتم پر تعینات کیا گیا ہے۔''
برزخ
اسلام کا نظریہ ہے کہ انسان،مرنے کے بعد ایک خاص طریقے سے زندہ رہتا ہے۔ اگر اس نے نیکی کی ہو تواسے نعمت وسعادت ملتی ہے اور اگربراتھا تو عذاب میں ہو گا ،اور جب قیامت برپا ہو گی تو اسے عام حساب و کتاب کے لئے حاضر کیا جائے گا۔ جہاں پر انسان مرنے کے بعد قیا مت تک زندگی کرتا ہے اسے''عالم برزخ''کہتے ہیں ۔اس سلسلہ میں خدائے متعال فر ماتا ہے:
(...( ومن ورآئهم برزخ الی یوم یبعثون ) (مؤ منون ١٠٠)
''...اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیا مت کے دن تک قائم رہنے والا ہے ''
( ولا تحسبنَّ الذین قتلوا فی سبیل اللّه امواتا بل احیاء عند ربهم یرز قون ) (آل عمران ١٦٩)
''اور خبر دار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کومردہ خیال نہ کر نا وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں ۔''
قیامت یقینی ہے
ہر انسان (بلااستشنا) اپنی خداداد فطرت سے، اچھائی اوربرائی کام میں فرق کو محسوس کرتا ہے اور نیک کام کو (اگرچہ اس پر عمل نہ کرتا ہو)اچھا اور لازم العمل جانتا ہے اور برے کام کو(اگر چہ اس میں پھنسا بھی ہو)برااورلازم الاجتناب جانتا ہے ۔اس میں کسی قسم کا شک و شبہہ نہیںہے کہ اچھائی اور برائی ،نیکی اور بدی ان دو نوں صفتوں میں موجود سزا اور جزاکی جہت سے ہے اور اس میں کوئی شک و شبہہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسادن نہیں ہے جس میں اچھے اور برے انسانوں کوان کی اچھائی اور برائی کی سزا اور جزا دی جائے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے نیک انسان اپنی زندگی انتہائی تلخی اور سختی میں گزارتے ہیں اور بہت سے برے انسان جو گناہ اورظلم وستم میں آلودہ ہیں لیکن پھر بھی خوشی اورآرام وآسائش میں زندگی گزارتے ہیں ۔
اس بناپر ،کہ اگر انسان کے لئے اپنے مستقبل میں اور اس دنیا کے علاو دوسری دنیا میں ایک ایسا دن نہ ہو کہ جس میں اس کے نیک اور برے اعمال کا حسا ب کر کے اسے مناسب سزا و جزا دی جائے ،یہ نظریہ (نیک کام اچھا اور واجب الاطاعت ہے اور برا کام برا اور واجب الاجتناب ہے)انسان کی فطرت میں قرار پایا ہے ۔
یہ تصور نہیں کیا جانا چاہئے کہ نیک کام کرنے والوں کی جزاجسے انسان اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ معاشرہ کے انتظامات بر قرار ہوتے ہیں اور نیک لوگ زندگی کی سعادت حا صل کرتے ہیں اور نتیجہ میں اس منافع کا ایک حصہ خودنیکی کرنے والے کو ملتا ہے اوراسی طرح بدکار اپنے نا مناسب کردار سے،معاشرہ کو درہم برہم کردیتا ہے اوراسکا نا مناسب کام آخرکار خود اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے،کیونکہ یہ تصور اگر چہ سماج کے پسماندہ اور مفلس طبقہ کے لوگو ں میں کسی حدتک پایا جاتاہے .لیکن جو لوگ اپنی قدرت کے عروج پر پہنچے ہیں اور معاشرہ کا انتظام وخلل ان کی خوشبختی اور کامیابی میں موشر نہیں ہے،بلکہ معاشرہ میں جس قدرافراتفری اورفساد ہو اور لوگوں کے حالات بدتر ہوںوہ زیادہ خوشحال اور کامیاب ہوتے ہیں اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان افراد کی فطرت نیک کام کو نیک اوربرے کا م کو برا جانے!یہ بھی تصورنہیں کرنا چاہئے کہ یہ لوگ اگر چہ اپنی چند روزہ زندگی میں کامیاب رہے ہوں، لیکن کسی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ کے لئے عام طور پر آنے والی نسلوں کی نظروں میں ننگ و عار سمجھاجائے گا، کیونکہ ان کے نام کا ننگ وعار کی صورت میں ظاہر ہو نا اور لوگوں کا ان کے بارے میں خیال رکھنا اس وقت ہوگا، جب وہ مرچکے ہوں گے اور اس ننگ و عار کا ان کی اس دنیا میں گئے خوشحال او رلذت اندوز زندگی پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔
اس صورت میں کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ انسان نیک کام کو اچھا جان کر اسے انجام دے اور برے کام کو براجان کراس سے پرہیز کرے،اور اس طرح مذکورہ نظریہ کا قائل ہو۔ اگر معاد کا وجود نہ ہو تو یہ اعتقاد قطعا ایک خرافائی اعتقاد ہوگا۔
لہذا ہمیں خالق کائنات کی طرف سے ہماری فطرت میں ودیعت کئے گئے اس مقدس اورمستحکم اعتقاد سے یہ سمجھنا چاہئے کہ معاد کا ہوناضروری ہے اور انسان کے لئے ضرور ایک دن ایسا آئے گا، جس دن اسے خالق کائنات کے حضور اس کی رفتار و کردار کے حساب و کتاب کے لئے پیش کیا جائے گا جہاں پر اسے نیک کاموں کی جزااو ربرے کاموں کی سزادی جائے گی۔
٤۔عدل
خدائے متعال،عادل اوردادرس ہے ،کیونکہ''عدل''صفات کمالیہ میں سے ایک ہے ،اور خدائے متعال تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے ۔اس کے علاوہ خدائے متعال اپنے کلام پاک میں عدل کی بار بارتعریف ا ور ظلم وستم کی مذمّت کرتا ہے ،اور لوگوں کو عدل کا حکم دیتاہے اورظلم سے روکتا ہے ۔یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جس چیز کوبرا سمجھتاہو وہ خود اس میں پائی جاتی ہواور جس چیز کو نیک اور خوبصورت سمجھتا ہو وہ اس میں موجود نہ ہو ! سورہ ٔ نساء میں فرماتا ہے :
( انّ اللّه لا یظلم مثقال ذرَّة ) ...) (نسائ٤٠)
'' خدائے متعال ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا''
نیزسورئہ کہف میں فرماتاہے :
(...( ولا یظلم ربّک احد ) (کہف٤٩)
'' تیرا پر وردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے ''
اسی طرح سورئہ نساء میں فرماتا ہے :
( ما اصابَکَ من حسنة فمن اللّٰه و ما اصابَکَٔ من سیّئة فمِن نَّفسک ) ...) (نسائ٧٩)
''تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے ۔''
سورئہ سجدہ میں فرماتا ہے :
( الّذی احسن کل شی ء خلقه ) ...) (سجدہ١)
''اس نے ہرچیز کو حسن کے ساتھ بنایاہے۔''
اس بناپر،ہر مخلوق اپنی جگہ پر انتہائی حسن کے ساتھ خلق کی گئی ہے ۔بعض مخلو قات میں جو بدصو رتی ،نا مناسب یا عیب ونقص پایا جا تا ہے ،وہ موازنہ اور نسبت کی وجہ سے پیش آتا ہے ۔مثلا سانپ اور بچھو کا وجود ہماری نسبت بد اور نا مناسب ہے اور کانٹے کو جب پھول سے موازنہ کیا جاتاہے تو کانٹازیبا نہیںہو تا،لیکن یہ سب اپنی جگہ پر حیرت انگیز مخلوق اور سرا پا خو بصورت ہیں ۔دوسرے الفاظ میں ،یہ کہا جائے کہ تمام اشیاء اپنے وجوداور وجود کی بقا میں جس جس چیز کی محتاج ہین اور ان میں سے جو عیب پایاجاتا ہے ،وہ انھیں خود رفع نہیں کر سکتیں اور وہ اتفاقی طور پر اور خودبخودبھی رفع نہیں ہوسکتا۔بلکہ یہ سب عالم مشہود سے مافوق ایک مقام کی طرف سے فراہم کئے جاتے ہیں ۔
وہی ہے جو ہر حاجت اور عیب کو دور کر تا ہے ،البتہ خودہرحاجت وعیب سے پاک و منز ہ ہے ورنہ دوسرے مبداء کی ضرورت پڑے گی جواس کے عیب و نقص کودور کرے اور اس صورت میں وہ خود بھی عالم کے ضرورت مندوں میں سے ایک قرار پائے گا ۔
وہی ہے ،جو اپنی لامتنا ہی قدرت اور علم سے کائنات کی ہر مخلوق کو وجود بخشتا ہے کائنات اور کائنات میں موجود ہ ہر شی کو تکامل کی شاہراہ پر ناقابل استثناء قوانین کے ذریعہ مقصد اور کمال کی منز ل کی طرف راہنمائی کر تا ہے اس بیان سے یہ نتیجہ نکلتے ہیں :
١۔خدائے متعال کائنات میں ،مطلق سلطنت کا مالک ہے اور ہر مخلوق جووجود میں آتی ہے اورہرواقعہ جو رونما ہوتا ہے ،ان کاسرچشمہ اس کا حکم وفرمان ہے۔چنانچہ فرماتا ہے :
(...( له الملک و له الحمد ) ...) (تغابن١)
''مطلق سلطنت اوربادشاہی اسی سے مخصوص ہے اور حقیقت میں ہر ستائش کا وہی سزاوار ہے کیونکہ نیکی اور اچھائی اسکی خلقت سے پیدا ہوئی ہے ''
(...( اِنِ الحکم الاّ للّٰه ) ...) (یوسف٤٠)
''حقیقت میں ہر حکم خدائے متعال کی طرف سے ہے''
٢۔خدائے متعال عادل ہے ،کیونکہ عدالت حکم میں یا اس کے جاری ہونے کی صورت میں یہ ہے کہ اس میں استثنا اور امتیاز نہیں ہے ۔ یعنی جو مواقع حکم سے مربوط ہیںوہ ،یکساں ثابت ہوں اور جو مواقع قا بل نفاذہیں وہ یکساں نافذکئے جائیں ۔چنانچہ معلوم ہوا کہ کائنات اور اس میں موجود چیزوں کا نظم و نسق کچھ ناقابل استثنا قوانین کے سایہ میں ہیں۔جن کا مجموعہ قانون علیت ومعلو لیت ہے ۔ چل رہا ہے ۔مثلا آگ کچھ خاص شرائط کے ساتھ ،ایک جلنے والی چیز کو جلائے گی ، خواہ یہ کالا کوئلہ ہو یا ہیرا ،خشک لکڑی ہو یا ایک ضرورت مند مفلس کا لباس ۔
اس کے علاوہ جس نے عدالت کو نظرانداز کیا،وہ اپنی کچھ ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے ظلم و ستم کو انجام دیتا ہے ۔خواہ یہ ضرورت مادی ہو جیسے کوئی شخص دوسرے کے مال کو لوٹ لیتا ہے اور اپنے انبار میں اضافہ کرتا ہے ،یا معنوی ضرورت ہو جیسے کوئی شخص دوسروں کے حقوق پر تجاوز کر کے یا قدرت اثرورسوخ اور تسلّط کا اظہار کر کے لذت محسوس کرتا ہے ۔
چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ،خالق کائنات کی ذات اقدس کے بارے میں کسی قسم کی حاجت قابل تصور نہیں ہے اورجو بھی حکم اس کے منبع جلال سے جاری ہوتا ہے،اگر ایک تکوینی حکم ہے تو وہ عام مصلحتوں کو پورا کرنے کے لئے ہے کہ خلقت کے لئے جس کی مراعات ضروری ہے اور اگر ایک تشریعی حکم ہے تو وہ اس کے بندو ں کی سعادت اور خوشبختی کے لئے ہے اور اس کا نفع انہی کو ملتا ہے۔خدائے متعا ل ا پنے کلام پاک میں فر ماتا ہے :
( انّ اللّه لایظلم مثقال ذرةٍ ) ...) (نسائ٤٠)
''خدائے متعال ذرہ برابرظلم نہیں کرتاہے ''
(...( وما اللّه یرید ظلماً للعباد ) (غافر٣١)
''خدائے متعال اپنے بندوںپر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے ۔''
٥۔امامت اور امت کی رہبری
اسلامی معاشرہ کے دینی اور دینوی امور کی سرپرستی کو''امامت'' کہتے ہیں۔امامت دین اسلام کے مقدس اصولوں میں سے ایک مسلم اصول ہے ۔جن آیات میں خدائے متعال نے اپنے دین کی تشکیل کوبیان کیا ہے ، ان میں اس مطلب کی بھی وضاحت کی ہے ۔
''امامت''کا مقصد لوگوں کی دنیا میں دین کی رہبری کرنا ہے اور پیشوا شخص کو ''امام''کہتے ہیں۔
شیعوں کاعقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خدائے متعال کی طرف سے ایک امام معین ہو نا چاہئے تاکہ وہ معارف اور دینی احکام کا محافظ ونگہبان ہو اور حق کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرے ۔
جب ایک ملک میں ایک حکومت تشکیل پاتی ہے اور وہ لوگوں کے عمو می کام کا نطم و نسق ہے ، تو و ہ کام خودبخود انجام نہیں پاتا ،بلکہ اگر کچھ شائستہ افراد اور ماہر لوگ اس کی حفاظت کی کوشش نہ کریں تونظام باقی ہی نہ رہے اور لوگوں کو اپنے فوائد سے بہرہ مند بھی نہ کرسکے۔۔انسانی معاشرہ میں جو بھی ادارہ وجود میں آتا ہے ،جیسے ثقافتی اور مختلف اقتصادی ادارے ،وہ بھی یہی حکم رکھتے ہیں اور ہر گز قابل وشائستہ مدیروں سے بے نیاز نہیں ہیں ورنہ بہت ہی کم مدت میں نابود ہو جائیں ۔یہ ایک واضح حقیقت ہے ،جسے سادہ لوح انسان بھی سمجھتا ہے اور بہت سے تجربوں اورآزمائشوں سے بھی اس کے صحیح ہونے کی گواہی ملتی ہے ۔
بیشک دین اسلام کا نظام بھی یہی حکم رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں جرأت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کاسب سے بڑانظام ہے اور وہ اپنی بقااور حفاظت میں بھی مدیروں کا محتاج ہے اور ہمیشہ شائستہ افراد کو چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے قوانین اور معارف کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے دقیق ضوابط اور قوانین کواسلامی معاشرہ میں نافذ کریں اور ان کی رعایت اور حفاظت میں کسی قسم کی غفلت ولا پر وائی نہ کریں ۔
دوسرے اعتبار سے، یہ کہ ہم نے نبوت کی دلیل میں ذکر کیا ہے ،کہ خلقت کے مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کی سیدھے راستہ پر ہدایت کرنا ہے ۔جس طرح خدائے متعال نے اپنی تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے اور ان کی ترقی کے وسائل کو ان کے اختیار میں دیدیا ہے ، اس طرح اس کے لٔے ضروری ہے کہ انسان کے صحیح عقاۓد ،پسندیدہ اخلاق اور نیک کامو ںکی ضرورتوں کو پور کرنے کے لئے انبیاء کو بھیجے تا کہ وہ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔
اسی دلیل کی بنا پر ، خدائے مہربان کو چاہئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ لیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دین کی حفاظت اور لوگوں کی ہدایت کے لئے امام اور پیشوا معین کر ے اور لوگوں کوان کی مرضی پر نہ چھوڑے ،جو اکثراوقات ہواوہوس سے مغلوب ہوتی ہے ۔جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ضرورتوں اور انسان کی انفرادی و اجتماعی بیماریوںکے علاج سے آگاہ کیا اور ان کو ہر طرح کے سہو ونسان سے محفوظ رکھا ،اسی طرح ضروری ہے کہ امام اور ایک دینی پیشواکو بھی علم وعصمت عطا کرے ۔اس عقلی دلیل سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں کی ہدایت ،دین کے تحفظ او راسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کیلئے خدا کی طرف سے امام معین ہو ۔
امام کی ضرورت پر ایک نقلی دلیل
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے کہ امت اسلامیہ کے لئے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد بعض پیشوا اورامام ہیں جو آپ کے جانشین ہوں گے ۔ایک معروف روایت ،جسے شیعہ وسنی راویوں نے نقل کیا ہے ،آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :
''امام بارہ افراد ہوںگے اور سب کے سب قریش سے ہوںگے ''۔(۱)
ایک اور مشہورروایت میں آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے جابر انصاری سے فرمایا:
''امام بارہ افراد ہیں''(۲)
اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کرکے ان کے نام بتائے اور جابر سے فرمایا:
''تم اماموں میں سے پانچویں امام کو درک کروگے ، ان کو میراسلام کہنا ''(۳)
اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیرالمؤ منین علی علیہ السلام کو (خصوصاً)اپنے جانشین کے طور پر تعیین فرمایا ہے،آپ نے بھی اپنے بعدوالے امام کا تعارف کرایا ،اسی طرح ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا تعارف کرایا ۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے تاریخ بشریت کا آغاز ہوا اور انسانیت کے خاندان میں اجتماعی زندگی بڑھتی گئی ،تو دنیا کے اطراف واکناف میں ،چھوٹے یا بڑے ،ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ معاشرے وجود میں آتے گئے ،لیکن حا کم اور سرپرست کے بغیرکوئی معاشرہ زیادہ دنوں تک باقی نہ رہ سکا ۔جہاں پر بھی کوئی معاشرہ تشکیل پایا اس میں ایک حاکم اور سر پرست قہر و غلبہ یاانتخاب کے ذریعہ ہوا کرتا تھا ، یہاں تک کہ چھوٹے اور چند افراد پر مشتمل خاندانوں میں بھی یہی طریقہ رائج تھا ۔بیشک یہاںپرانسان اپنی خداداد فطرت سے سمجھتا ہے کہ ہر معاشرہ کے لئے ایک سر پرست کی ضرورت ہے۔ خدائے متعال فرماتا ہے :
( فاقم وجهک لِلدّیِن حنیفاً فطرت اللّه الّتی فطر النّاس علیها لا تبدیل لخلق اللّه ذلک الدِّینِ القیِّم ) (روم ٣٠)
''آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اورخلقت الہٰی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔یقینا یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے''
پروردگار عالم ،اس آیہ شریفہ میں اپنے دین کو دین فطرت سے تعبیر کرتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ اس مقدس دین کے احکام ان چیزوں کے مطابق ہیں کہ جن کو انسان اپنی خالص فطرت سے سمجھتاہے ۔
خدائے متعال ،اس آیہ شریفہ میں ،انسان کے تمام فطری ادراکات اور اس کی خالص فطرت کے فیصلوں کو معتبر قرار دیتا ہے اور ان کی تائید کرتاہے ان فطری فیصلوں میں سے ایک معاشرہ کی سرپرستی اور اسکی باگ ڈور سنبھالنا ہے۔
ولایت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان
خدائے متعال اپنے پیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی توصیف میں فرماتا ہے :
( لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیزعلیه ما عنتّم حریص علیکم بالمئومنین رؤف رّحیم ) (توبہ١٢٨)
''یقیناتمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جوتمھیںمیں سے ہے اوراس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مو منین کے حال پر شفیق اور مہر بان ہے''
اس بات پر ہرگز یقین نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہ پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم جو قرآن مجید کی نص کے مطابق اپنی امت پر تمام لوگوں سے زیادہ ہمدردومہر بان تھا،وہ احکام الہیٰ میں سے ایک حکم کے بارے میں اپنی پوری عمر خاموش رہے،اور اس کے بیان سے چشم پوشی کرے جو اسلامی معاشرہ میں بلا شک و شبہ پہلے درجہ کی اہمیت کا حاصل ہو اور عقل سلیم اور فطرت کے مطابق ہو۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بہتر جانتے تھے کہ اسلام کا تشکیل پایا ہوا یہ وسیع نظام (جو دنیا کے وسیع ترین نظاموں میں سے ہے )صرف دس بیس سال تک کے لئے نہیں ہے کہ اس کی سرپرستی کو آپ خود کریں ،بلکہ یہ نظام عالم بشریت کو ہمیشہ چلا نے والا ہے ۔
چنا نچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد ہزاروں سال تک کے حالات کے بارے میں دور اندیشی فرماتے تھے ،اور اس سلسلہ میں ضروری احکام جاری فرماتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ دین،ایک اجتماعی نظام ہے اور کوئی بھی اجتماعی نظام حاکم اور سر پرست کے بغیر ایک گھنٹہ کے لئے بھی زندہ باقی نہیں رہ سکتا ۔
اس بنا پر ،سر پرستی ضروری ہے تاکہ دین کے معارف اور قوانین کی حفاظت کی جائے اور معاشرہ کے نظام کو چلا یا جاسکے اور لوگوں کی دنیاوآخرت کی سعادت کی طرف رہنمائی ورہبری کی جائے ۔لہذا کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے بعد آنے والے کل کوبھول جائیں یا اس کے بارے میں کوئی دلچسپی نہ رکھیں؟
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جنگ یاحج کے لئے صرف کچھ دنوں کے لئے مدینہ سے باہرتشریف لے جاتے تھے ،تو لوگوں کے امور کو چلانے کے لئے کسی نہ کسی کو اپنا جانشین مقرر فرماتے تھے اوراسی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے شہروں کے لئے گورنرمقرر فرماتے تھے اور جنگ پر روانہ ہونے والے فوجی لشکر یاگروہ کے لئے کمانڈر اورامیر مقرر فرماتے تھے اور کبھی اس حد تک فرماتے تھے کہ:''تم لوگوں کا امیر فلاں شخص ہے اگر وہ ماراگیا تو فلاں شخص ہوگا ''۔پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی اس روش کے باوجود کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنے سفر آخرت کے موقع پراپنی جگہ پر کسی کو معےّن نہیں کیا ہوگا ؟
مختصر یہ کہ جو بھی شخص گہری نگاہ سے اسلام کے بلند مقاصد اور ان کولانے والے عظیم الشان پیغمبر کے مقصد پر نظر ڈالے ،توکسی شک وشبہہ کے بغیر تصدیق کرے گا کہ مسلمانوں کے لئے ولایت وامامت کا مسئلہ حل شدہ اور واضح ہو چکا ہے ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ جانشین کا تقرر
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعدمسلمانوں کے امور کی سرپرستی اور مسئلہ ولایت کے سلسلہ میں صرف سر بستہ بیانات پرہی اکتفانہیں فرمایا بلکہ پہلے ہی دن سے توحید ونبوت کی دعوت کے ساتھ ساتھ مسئلہ ولایت کو بھی واضح طور پر بیان فرمایا اور دین ودنیا کے تمام امور میں حضرت علی علیہ السلام کی سرپرستی اور جانشینی کو تمام مسلمانوں میں اعلان فرمایا۔
جیسا کہ بیان ہوا،اس روایت کے مطابق جسے شیعہ وسنی راویوں نے نقل کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے دن اعلانیہ دعوت دینے پر مامور ہوئے۔توآپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اورانھیں ایک جگہ پر جمع کیا اوراس محفل میں حضرت علی علیہ السلام کے وزیر، وصی اور خلّیفہ ہونے کوآشکار طور پر ثابت اور مستحکم فر مایا اوراسی طرح اپنی زندگی کے آخری ایام میں غدیرخم کے مقام پر ایک لاکھ بیس ہزار کے ایک عظیم مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑکر بلند کرکے فرمایا :
''من کنت مولاه فهذاعلی مولاه''
''جس جس کا میں مولا ہوں،اس کے یہ علی بھی مولا ہیں ''
امامت کی ضرورت پر ایک دلیل
چنانچہ نبوت کی بحث میں واضح ہوا کہ خالق کائنات کااپنی مخلوق پر عنایت وتوجہ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی معین مقصد (جو کمال کے درجہ تک پہنچنا ہے) کی طرف رہنمائی کرے مثال کے طورپر پھل دار درخت کی رشد،نمو،کونپلیں کھلنے اور پھل دینے کی طرف راہنمائی کی جائے اور اسکی زندگی کا طریقہ ایک پرندہ کی زندگی کے طریقہ سے جدا ہے ۔اس طرح ایک پرندہ بھی اپنی زندگی خاص راستہ کو طے کرتا ہے اور اپنے خاص مقصد کے پیچھے جاتاہے ،نہ کہ درخت کے راستہ اور مقصد کے پیچھے،اسی طرح ہر مخلوق کی اپنی منزل مقصود تک پہنچنے اور مناسب راستہ کو طے کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف راہنمائی نہیں کی جاتی اور معلوم ہے کہ انسان بھی خدا کی ایک مخلوق ہونے کے ناطے ہدایت کے اس کلی قانون میں شامل ہے ۔
واضح ہوا کہ انسان کی زندگی کی سعادت چونکہ خود اس کے اختیار اور ارادہ سے حاصل ہوتی ہے ،لہذا ہدایت الٰہی اور،دعوت وتبلیغ بھی انبیاء اور دین کو بھیجنے کے ذریعہ ہونی چاہئے تاکہ خدائے متعال پر انسان کی کوئی حجت باقی نہ رہے ۔ذیل کی آیت اسی معنیٰ پر دلالت کرتی ہے:
( رسلاً مّبشِّرین ومنذرین لئلاّیکون للناس علی اللّه حجةً بعد الرُّسّل ) ۔۔.) (نسائ١٦٥)
''یہ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اس لئے بھیجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے''
جو دلیل پیغمبروںکے بھیجنے اور دین کی دعوت کی برقراری کا تقاضا کرتی ہے وہی دلیل اس چیز کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ،اپنی عصمت سے دین کی حفاظت اورلوگوں کی رہبری کرنے والے پیغمبرکی رحلت کے بعد ، خدائے متعال کو چاہئے کہ اوصاف کمالی میں (وحی ونبوت کے علاوہ )آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے مانند ایک شخص کو آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کاجانشین مقرر فرمائے تاکہ وہ دین کے معارف اوراحکام کی کسی انحراف کے بغیر حفاظت کرے اور لوگوں کی رہنمائی کرے ،ورنہ عام ہدایت کا نظام درہم برہم ہو جا ئے گا اور خدائے متعال پر لوگوں کی حجت تمام ہوجائے گی ۔
امام کی ضرورت
عقل میں چوںکہ خطا ولغزش پائی جاتی ہے لہذا وہ لوگوںکو خدا کے پیغمبروں سے بے نیاز نہیں کر سکتی ،اسی طرح امت میں علمائے دین کی موجودگی اورانکی دینی تبلیغات ،لوگوں کو امام کے وجود سے مستغنی نہیں کر سکتے ،کیونکہ، جیسا کہ واضح ہوا کہ بحث اس میں نہیں ہے کہ لوگ دین کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں ،بلکہ بحث اس چیز میں ہے کہ خدا کا دین کسی قسم کی تحریف وتبدیلی یانابودی کے بغیر لوگوں تک پہنچ سکے ۔معلوم ہے کہ علمائے امت کتنے بھی صالح اور متّقی ہوں ،لیکن خطاو گناہ سے محفوظ و معصوم نہیں ہیں اور بعض معارف اوردینی قوانین کا ان سے پائمال ہونا یا تبدیل ہونا،اگرچہ عمدا ًنہ ہو ،محال نہیںہے ۔اس کی بہترین دلیل اسلام میں گوناگون مذاہب اوراختلافات کا وجود میں آنا ہے ۔
لہذا،ہر حالت میں امام کا وجود لازم اور ضروری ہے تاکہ دین خدا کے معارف اور اس کے حقیقی قوانین اس کے پاس محفوظ رہیں اور جب بھی لوگوں میں استعداد پیدا ہو جائے وہ ان کی رہنمائی سے استفادہ کر سکیں ۔
امام کی عصمت
مذکورہ بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ امام کو بھی پیغمبر کے مانند خطاومعصیت سے محفوظ ہونا چاہئے ،کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو دین کی دعوت ناقص رہے گی اور الہٰی ہدایت اپنا اثر کھودے گی ۔
امام کے اخلاقی فضائل
امام میں شجاعت ،شہامت ،عفت ،سخاوت اور عدالت جیسی اخلاقی فضیلتیں موجود ہونی چاہئیں ،کیونکہ جو معصیت سے محفوظ ہے وہی تمام دینی قوانیں پر عمل کرتا ہے اور پسندیدہ اخلاق دین کی ضروریات میں سے ہیں اس لئے اس کو اخلاقی فضائل میں تمام لوگوں سے افضل ہونا چاہئے ،کیونکہ کسی کا اپنے سے برتر وبالاتر کی رہبری کرنا بے معنی اور عدل الہٰی کے منافی ہے ۔
امام کا علم
چونکہ امام دین کا حامل اور تمام لوگوں کا پیشوا ہوتاہے ،لہذا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی دنیا وآخرت اور انسان کی سعادت سے متعلق تمام مسائل کا علم رکھتا ہو ،کیونکہ عقل کے مطابق جاہل کا پیشوا بننا جائز نہیں ہے اور عام الہٰی ہدایت کی روسے بھی یہ بے معنی ہے ۔
____________________
١۔احمد بن حنبل،مسند،ج٥،ص٩٢۔
٢۔ینابیع المودہ ،باب ٧٧،ص٥٠٣۔
٣۔ینابیع المودہ،باب ٩٤،ص٥٥٣و٥٥٤۔
ائمہ ھدیٰ علیہم السلام
ائمہ ھدیٰ علیہم السلام ،جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے جانشین اوردین ودنیا کے پیشوا ہیں ،بارہ ہیں ۔اس سلسلہ میں شیعہ وسنی دونوں نے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے بے شمار روایتیں نقل کی ہیں اور ان ائمہ میں سے ہر ایک نے اپنے بعد آنے والے امام کو معین فرمایا ہے۔
ائمہ علیہم السلام کے اسمائے گرامی
١۔حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیہ السلام
٢۔حضرت امام حسن مجتبٰی علیہ السلام
٣۔حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام
٤۔حضرت امام سجادزین العابدین علیہ السلام
٥۔حضرت امام محمد باقرعلیہ السلام
٦۔حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
٧۔حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام
٨۔حضرت امام علی رضاعلیہ السلام
٩۔حضرت امام محمد تقی علیہ السلام
١٠۔حضرت امام علی نقی علیہ السلام
١١۔حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
١٢۔حضرت امام عصر ،حجتہ بن الحسن ،عجل اللہ تعالی فر جہ الشریف
ائمۂ اطہار علیہم السلام کی عام سیر ت
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بارہ امام ٢٥٠سال تک لوگوں کے درمیان تھے۔لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے دن سے ہی ان کے مخا لفین پیدا ہوئے اور ہر ممکن وسیلہ سے،خلافت کے عہدے کو غصب کرکے دین کے فطری راستہ کو منحرف کردیا اس کے علاوہ مذکورہ مخالفین کاگروہ ہر احتمالی خطرے کے مقابلہ میں اپنی حیثیت کو مستحکم کرنے اوراپنی حکومت کی حفاظت میں ،اہل بیت پیغمبر اسلام کے نور کو ہر وسیلہ سے بجھانے کے در پے تھے ،ہر بہانہ سے ان پر دبائوڈالتے،جسمانی اذیتیں پہنچاتے ،حتیٰ یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوششیںبھی کرتے تھے ۔اسی سبب سے ائمہ ھدی ،علیہم السلام عام اصلاحات کے سلسلہ میں کچھ نہیں کر سکتے تھے ، یا اسلامی معاشرہ میں اسلام کے معارف و قوانین اور سیرت پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیع پیمانے پر پھیلانے سے قاصر تھے ۔
یہاں تک کہ امیرالمئو منین حضرت علی علیہ السلام بھی اپنی ظاہری خلافت کے پانچ سال کے دوران ،اندورونی اختلافات اور طلحہ ،زبیر ،عائشہ اورمعاویہ جیسے دعویداروں اوردیگر بانفوذ صحابیوں کی رخنہ اندازیوں کی وجہ سے ان سے خونین جنگیں لڑتے رہے اوراپنے عالی مقاصداور اصلاحات تک دلخواہ صورت میں نہ پہنچ سکے ۔
یہی وجہ ہے کہ ائمہ ھدیٰ خدا کی طرف سے اپنی مسئولیت اورذمہ داری کے مطابق معاشرہ میں عمومی تعلیم وتربیت ،خاص افراد کی تعلیم وتربیت اور معاشرہ کی عمومی اصلاحات،جیسے(حتی الامکان) امربالمعروف اورنہی عن المنکر کرنے پر اکتفا کی۔یعنی دین کے معارف وقوانین کو کھلم کھلا طور پر معاشرہ میں بیان کرنے اورزمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیکر معاشرہ کو دین کی اعلی مصلحتوں کے مطابق چلانے کے بجائے بااستعداد اورخاص افراد کی تربیت پر اکتفا کرتے تھے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لئے ممکن ہی نہیں تھا ۔وہ لوگوں کی خاطر وقت کی حکومتوں کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے قیام کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح دین کو نابود ہونے سے بچالیں اورخدا کا نورانی دین ، تدر یجی طور پر خاموشی کے ساتھ نورافشانی کر تا رہے اور آگے بڑھتا رہے اور ایک دن پھر سے پہلی حالت پیدا کرکے دنیا کواپنے نورسے منور کردے ۔
ائمہ ھدیٰ علیہم السلام میں سے ہر ایک کی زندگی کے حالات اور امامت کے زمانے میں ان کی روش کی تحقیقات سے یہ حقیقت مکمل طور پر واضح ہوجاتی ہے ۔
پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام
عرف اورلغت میں ''اہل بیت '' اور مرد کا خاندان، مرد کے گھر کے چھوٹے معاشرے کے افرادکو کہا جاتا ہے،جن میں بیوی ،بیٹے،بیٹیاںاور نوکر شامل ہوتے ہیں جو مجموعی طورپر صاحب خانہ کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں ۔
بعض اوقات''اہل بیت''کے معنی کوعمومیت دے کراس لفظ کو اپنے قریبی رشتہ داروں جیسے باپ ،ماں ،بھائی،بہن ،چچا ،پھپوپھی ،ماموں ،خالہ اور ان کی اولاد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ۔
لیکن قرآن مجید اور احادیث میں لفط کلمہ''اہل بیت''سے مذکورہ دو عرفی و لغوی معنی میں سے کوئی بھی معنیٰ مراد نہیں ہے ۔کیونکہ شیعہ و سنی سے منقول متواتر احادیث کے مطابق ''اہل بیت''ایک ایساعطیہ ہے جو حضرت پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ،حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا،حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام سے مخصوص ہے۔اس بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ اور دوسرے رشتہ دار،اگر چہ عرف و لغت کے لحاظ سے اہل بیت شمار ہوتے ہیں، لیکن اس اصطلاح کے اعتبارسے اہل بیت نہیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا،جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ معّززو محترم بیوی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہاکی والدئہ گرامی تھیں اہل بیت میں شمار نہیں ہوتیں اور اسی طرح آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے صلبی بیٹے حضرت ابراہیم بھی ''اہل بیت''کے اس زمرے میں شامل نہیں ہیں ۔
لیکن ان روایتوں اور دیگر احادیث کی روسے بارہ اماموںمیں سے دوسرے نو امام ،جو فرزندامام حسین علیہ السلام کی اولاد اورآپ کی نسل میں ہیں ،اہل بیت میں ہیں ۔اس بنا ء پر اہل بیت چودہ معصومین علیہم السلام ہیں اور معمولا ''اہل بیت پیغمبر''وہ تیرہ افراد ہیں جوپیغمبر کے بعدآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی عترت کے طور پر مشہور ہیں ۔
پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اہل بیت علیہم السلام،اسلام میں بہت سے فضائل ومناقب اور نا قابل موازنہ مقامات کے مالک ہیں ،کہ ان میں سے درج ذیل دو مقام سب سے اہم ہیں :
١۔آیۂ شریفہ (...( انّما یرید اللّه لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت ویطهِّرکم تطهیراً ) (احزاب ٣٣)
کی روسے مقام عصمت وطہارت پر فائز تھے ،اس مقام کا تقاضایہ ہے کہ وہ ہرگزگناہ کے مرتکب نہیں ہوسکتے۔
٢۔حدیث ثقلین،جو متواترحدیث ہے اور اس سے پہلے اسکی طرف اشارہ کیا گیا،کی روسے،عترت ہمیشہ قرآن مجید کے ہمراہ ہیں اور ان میں کبھی جدائی پیدا نہیں ہو سکتی یعنی وہ قرآن مجیدکے معنی اوردین مبین اسلام کے مقاصدکو سمجھنے میں کبھی خطاولغزش سے دوچار نہیں ہوسکتے۔ان دو مقامات کالازمہ یہ ہے کہ اسلام میں اہل بیت علیہم السلام کا قول وفعل حجت ہے (جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے)
اہل بیت علیہم السلام کی عام سیرت
اہل بیت علیہم السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم وتربیت کے مکمل نمونہ ہیں اور ان کی سیرت بالکل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔
البتہ ٢٥٠سال کا عرصہ ( ١١ھ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے، ٢٦٠ھ یعنی حضرت حجت عج کی غیبت تک ) ائمہ ھدی علیہم السلام نے لوگوں کے ساتھ گزاررا،اس مدت میں ان کی زندگی مختلف حالات اور مراحل سے گزری کہ جن میں ائمہ اطہارکی زندگی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئی،لیکن وہ اصلی مقصد،یعنی اصول دین وفروع د ین کوانحرافات اور تبدیل ہونے سے بچایا اور حتی الامکان لوگوں کی تعلیم وتربیت سے دست بردارنہیںہوئے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ٢٣سال کی تبلیغ کے دوران ، زندگی کے تین مراحل طے کئے ۔ابتدائی تین سال کے دوران مخفیانہ تبلیغ انجام دیتے تھے ،اس کے بعد دس سال تک کھلم کھلا تبلیغ میں مشغول رہے ،لیکن اس مدت کے دوران خود آپصلىاللهعليهوآلهوسلم اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے پیرو انتہائی دبائواور نہایت جسمانی اذیتوں میں زندگی گزارتے تھے اور ہرقسم کی عملی آزادی سے محروم تھے جو معاشرہ کی اصلاح میں اثر انداز ہوتی ہے ،اور اسکے بعد والے دس سال (جو ہجرت کے بعد میں ہیں)،آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے ماحول میں تھے کہ جس کا مقصد حق وحقیقت کو زندہ کرنا تھا،اور اسلام دن بہ دن فاتحانہ طورپر آگے بڑھ رہا تھا اور ہر لمحہ لوگوں کے لئے علم و کمال کا ایک نیا باب کھل رہا تھا ۔
البتہ واضح ہے کہ ان تین مختلف مراحل کے مختلف تقاضے تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو۔جس کا مقصد حق وحقیقت کو زندہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گوناگوں صورتوں میں ظاہر کرتے ہیں۔
ائمہ ھدیٰ کے زمانہ میں جو مختلف اور گونا گوں حالات رونما ہوئے ،وہ تقریباً پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کی ہجرت سے پہلے تبلیغی زمانہ سے شباہت رکھتے ہیں ۔ کبھی ائمہ اطہار کے لئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے پہلے تین سال کی طرح کسی بھی صورت میں اظہار حق ممکن نہیں تھا اور(وقت کے)امام بڑی احتیاط سے اپنا فریضہ انجام دیتے تھے،چنانچہ چوتھے امام کے زمانہ میں اور چھٹے امام کی آخری عمرمیں یہی حالت تھی ۔کبھی ہجرت سے پہلے دس سال کے مانند ،کہ جس مین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اعلانیہ طور پر دعوت دیتے تھے اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم ہر طرف سے اپنے پیروئوں پر کفار کی اذ یتوں کی وجہ سے پریشان تھے،امام بھی معارف دین کی تعلیم اوراحکام کی اشاعت میں مشغول ہو جاتے تھے،لیکن وقت کے حکام انھیں جسمانی اذیت وتکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے اور ان کے لئے ہردن کوئی نہ کوئی مشکل ایجاد کرتے تھے۔
البتہ ،پیغمبر اکرم کی ہجرت کے بعد والے ماحول کے مانند جو زمانہ کسی حدتک ہے وہ امیرالمئومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے پانچ سال کا زمانہ ، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہااور امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا تھوڑاسا زمانہ اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کامختصراور چند روزہ زمانہ تھا ،کہ جس میں حق وحقیقت اورکھلم کھلا طور پر ظاہر ہو رہی تھی اور صاف و شفاف آئینہ کی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جیسے حالات پیش کئے جارہے تھے ۔
خلاصہ یہ کہ ائمہ اطہار علیہم السلام ، مذکورہ مواقع کے علاوہ وقت کے حکمرانوں اور فرمانروائوں کی آشکارا طور پر بنیادی مخالفت نہیں کرسکتے تھے،اس لئے اپنی رفتار وگفتارمیں تقیہ کا طریقہ اپنا نے پر مجبور تھے تاکہ وقت کے حکام کے ہاتھ کوئی بہانہ نہ آسکے ،اسکے باوجود ان کے دشمن گونا گوں بہانے بناکر ان کے نور کو خاموش کرنے اور ان کے آثار کو مٹانے میں کوئی دقیقہ فرو گزار نہیں کرتے تھے ۔
وقت کے حکّام کے ساتھ ائمہ اطہار کے اختلافات کا اصلی سبب
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد اسلامی معا شرہ میں تشکیل پانے والی مختلف حکو متیں ،کہ جو اسلامی حکومت کا لیبل لگائے ہوئے تھیں ، وہ سب کی سب اہل بیت علیہم السلام سے بنیادی مخالفت رکھتی تھیں اور اس ختم نہ ہونے والی دشمنی کی ایک ایسی جڑتھی جو کبھی خشک نہیں ہوتی تھی ۔یہ سچ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور منا قب بیان فرمائے تھے کہ ان میں سے اہم ترین فضیلت معارف قرآن اور ان کا حلال و حرام کا جاننا تھا،جس کی وجہ سے ان کے مقام کا احترام اور تعظیم کرنا تمام امت پرواجب تھا ،لیکن امت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت اور تاکید کا حق ادا نہ کیا ۔
بیشک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلے دن دعوت دی تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی اورحضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اوراپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی غدیر خم میں اور دوسرے مقامات پر آپ کی جانشینی کا علان کیا ۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں نے دوسروں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین منتخب کیا اور اہل بیت علیہم السلام کو ان کے مسلم حق سے محروم کردیا ،لہذا وقت کے حکام اہل بیت کو ہمیشہ اپنا خطر ناک رقیب سمجھتے رہے اور ان سے خائف رہتے تھے ،اور ان کا خاتمہ کرنے کے لئے گونا گوںامکانات اور وسائل سے استفادہ کرتے تھے ۔
لیکن اہل بیت علیہم السلام اور اسلامی حکومتوں کے درمیان اختلا فات کا سب سے بڑا سبب کچھ اور تھا اگر چہ حکومت اسلامی مسلۂ خلافت کے فروعات میں سے تھی۔
اہل بیت اطہار علیہم السلام امت اسلامیہ کے لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اطاعت کو ضروری سمجھتے تھے اور اسلامی حکومت کو اسلام کے آسمانی احکام کی رعایت ،تحفظ اورنفاذ کے لئے ذمہ دار سمجھتے تھے ،لیکن جو اسلامی حکو متیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشکیل پائیں ،جیسا کہ ان کی کار کردگی سے ظاہر ہے ،وہ اسلامی احکام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی رعایت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اطاعت کرنے کی پابند نہیں تھیں ۔
خدائے متعال اپنے کلام پاک میں کئی جگہوں پر،پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسی طرح امت کو آسمانی احکام میں تبدیلی ایجاد کرنے سے منع فرماتا ہے یہاں تک کہ دینی احکام اور قوانین میں چھوٹی سے چھوٹی خلاف ورزی کی تنبیہ فرماتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی ناقابل تغییر احکام وقوانین کی روشنی میں ،لوگوں کے درمیان ایک ایسی سیرت اختیار ہوئے تھے کہ دینی قوانین کو نافذ کرنے میں زمان ومکان اوراشخاص کے لحاظ سے کسی قسم کا فرق نہیں کرتے تھے۔آسمانی احکام کی رعایت کرنا ہر ایک کے لئے یہاں تک کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے واجب تھا اور یہ احکام ہرایک کے حق میں لازم الاجرا تھے اورشریعت ہر حال میں اورہر جگہ پر زندہ اور نافذ تھی ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مساوات و عدالت کے نتیجہ میں لوگوں سے ہرقسم کے امتیاز وفرق کو ہٹایا تھا ۔خود آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم جو خدا کے حکم سے واجب الاطاعت حاکم و فرمانروا تھے ،اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تمام لوگوں کی نسبت اپنے لئے کسی قسم کے امتیاز کے قائل نہیں تھے ،عیش وعشرت سے پر ہیز فرماتے تھے ،اپنی حکومتی حیثیت میں کسی قسم کے تکلف سے کام نہیں لیتے تھے ،اپنی حیثیت کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے تھے اور جاہ وحشم کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے اور آخر کار دوسروں سے ایک معمولی اورظاہری امتیاز سے بھی پہچانے نہیں جاتے تھے ۔
لوگوں کے مختلف طبقات میں سے کوئی طبقہ امتیاز کے بل بوتے پر دوسروں پرفضیلت نہیں جتلاتا تھا ،عورت ومرد،اونچے اور نچلے طبقہ کے لوگ ،غنی و فقیر،قوی وکمزور ،شہری ودیہاتی اور غلام وآزاد سب ایک صف میں تھے اور کوئی بھی اپنے دینی فرائض سے زیادہ کا پابند نہ تھا اور معاشرہ کے قوی لوگوں کے سامنے جھکنے اور ظالموں کے سامنے حقیر ہونے سے معاشرہ کا ہر فرد محفوظ تھا۔
تھوڑا غورو فکر کرنے سے ہمارے لئے واضح ہو جاتا ہے ( مخصوصاًپیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے آج تک جو ہم نے اندازہ کیا ہے) کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی سیرت سے صرف یہ مقصد تھا کہ اسلام کے آسمانی احکام لوگوں میں عادلانہ اور مساوی طورپر نافذ ہو جائیں اور اسلام کے قوانین انحراف اورتبدیل ہو نے سے محفوظ رہیں ،لیکن اسلامی حکومتوں نے اپنی سیرت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مطابق وہم آہنگ نہیں کیا اور روش کو بدل دیا جس کے نتیجہ میں :
١۔اسلامی معاشرہ میں نہایت کم وقت کے اندر شدید ترین صورت میں طبقاتی اختلافات رونما ہوئے اور مسلمان طاقتور اور کمزور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور اس طرح ایک گروہ کی جان و مال اور عزت دوسرے گروہ کے ہوا وہوس کا کھلونا بن گئی ۔
٢۔اسلامی حکو متیں اسلامی قوانین میں تدریجی طور پر تبدیلیاں پیدا کرنے لگیں اور کبھی اسلامی معاشرہ کی رعایت کے نام پر اور کبھی حکومت اور حکومت کی سیاسی حیثیت کے تحفظ کے عنوان سے دینی احکام پر عمل کرنے اوراسلامی قوانین کے نفاذ سے پہلوتہی کی گئی ۔
یہ طریقہ دن بدن وسیع تر ہوتا گیا ۔یہاں تک کہ اسلامی حکومت کے نام پر چلنے والے ادارے اسلامی قوانین کی رعایت اور انہیں نافذ کرنے میں کسی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے تھے۔معلوم ہے جب عام قوانین وضوابط کو نافذ کرنے والے افراد ہی مخلص نہ ہوں گے توان قوانین کاکیاحشر ہوگا!
خلاصہ اور نتیجہ
مذ کورہ گفتگوسے معلوم ہواکہ اہل بیت علیہم السلام کی معاصراسلامی حکو متیں وقت کی مصلحتوں کے پیش نظر اسلامی قوانین میں تصرف کرتی تھیں اور ان ہی تصرفات کی وجہ سے ان کی سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بالکل مختلف ہوتی تھی۔لیکن اہل بیت علیہم السلام قرآن مجید کے حکم کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے احکام کو ہمیشہ کے لئے ضروری جانتے تھے۔
انہی اختلا فات اور تضاد کے سبب وقت کی طا قتورحکو متوں نے اہل بیت علیہم السلام کا خا تمہ کر نے کے لئے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور ان کے نور کو بجھانے کے لئے ہر ممکن وسیلہ سے استفادہ کرتے تھے ۔
اہل بیت اطہار علیہم السلام بھی اپنی الہیٰ ذمہ داری کے مطابق ،اپنے سخت اور منحوس دشمنوں کی طرف سے فراوان مشکلات سے دو چارہونے کے باوجود ،دین کے حقائق کی تبلیغ کر رہے تھے اور صالح افراد کو تعلیم دینے اور ان کی تربیت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے ۔
اس مطلب کو سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ ہم تاریخ کی طرف رجوع کر یں اور حضرت علی علیہ السلام کی پانچ سالہ حکو مت میں شیعوں کی اکثریت کو ملا حظہ کریں،کیونکہ تھوڑا غور کرنے سے ہم سمجھ لیں گے کہ،یہ اکثریت حضرت کی اسی٢٥سالہ گوشہ نشینی کے دوران وجود میں آئی ۔اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر پر گروہ درگروہ آنے والے شیعہ تھے جو خاموشی کے ساتھ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے تر بیت یافتہ تھے ،یہ حقائق کے ایسے خوشہ چین تھے کہ حضرت امام موسی ابن جعفر علیہ السلام حتی زندان کے ایک تاریک گوشہ میں بھی ان کی اشاعت فرماتے تھے ۔
آخر کاراہل بیت علیہم السلام کی مسلسل تعلیم وتربیت کے نتیجہ میں ، شیعہ جو پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت ایک معمولی تعداد میں تھے ،ائمہ اطہار علیہم السلام کے آخری زمانے میں ایک بڑی تعداد میں تبدیل ہوئے ۔
اہل بیت علیہم السلام کے کردار میں ایک استشنائی نکتہ
جیسا کہ بیان کیا گیا ،پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام نے اپنی زندگی کا زمانہ مظلو میت اور محکو میت میں گزارا اور اپنی ذمہ داریوں کو تقیہ کے ماحول اور انتہائی سخت حالات میں انجام دیا ۔ان میں سے چار معصومین کی زندگی بہت کم مدت کے لئے نسبتاًآزادانہ اور بلا تقیہ نظر آتی ہے۔ لہذا ہم ان چار شخصیتوں،یعنی حضرت علی ، حضرت فاطمہ اور حسنین علیہمااسلام کی تاریخ زندگی اور کردار کا اجمالی جائزہ پیش کرتے ہیں ۔
اہل بیت علیہم السلام کے فضائل
شیعہ اورسنی راویوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اہل بیت کے مناقب میں ہزاروں احادیث نقل کی ہیں ہم یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل میں سے تین کو بیان کرتے ہیں کہ جن کے پہلے خود آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم ہیں :
١۔ ٦ ہجری میں ،شہر نجران کے نصرانیوں نے اپنے چند بزرگوں اورد انشوروں کو چن کر ایک وفد کی صورت میں مدینہ بھیجا ۔اس وفد نے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ اور کٹ جحتی کی ،لیکن مغلوب ہوئے ، اور خدائے متعال کی طرف سے آیۂ مباہلہ نازل ہوئی :
( فمَن حاجَّک فیه من بعد ماجا ء ک من العلم فقل تعالَوا ندع ابنا ء نا وابنا ء کم ونساء نا ونساء کم وانفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللّه علی الکاذبین ) (آل عمران ٦١)
''پیغمبر!علم کے آجانے کے بعدجو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہدیجئے کہ آئو ہم لوگ اپنے اپنے فرزند ،اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خداکی بارگاہ میں دعاکریں اور جھوٹوں پرخدا کی لعنت قراردیں ۔''
اس آیہ شریفہ کے حکم کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے وفد کو مباہلہ کی دعوت دیدی ، اس طرح سے کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم ،عورتوں اور فرزندوں کے ساتھ حاضر ہو کر جھوٹوں پر لعنت کریں تاکہ خدائے متعال ان کے لئے عذاب نازل کرے۔
نجران کے وفد نے مباہلہ کی تجویز کو قبول کیا ، اور دوسرے ہی دن مباہلہ کا وقت مقرر کیاگیا ۔ دوسرے دن مسلمانوں کی بڑی تعداداور نجران کاوفد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا منتظر تھاکہ دیکھیں ،آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور کن لوگوں کو مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لا رہے ہیں ۔
انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لارہے ہیں کہ آپ کی آغوش میں حسین علیہ السلام ہیں اور حسن علیہ السلام ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے پیچھے آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے علی علیہ السلام ہیں اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم ان سے فرمارہے ہیںکہ جب میں دعاکروں توتم لوگ آمین کہنا ۔
اس نورانی وفد، جن کے وجود سے حق وحقیقت نمایاں تھی ،جو خدا کی پناہ گاہ کے سواکسی پناہ گاہ پر بھروسہ کئے ہوئے نہیں تھے ،نے نجران کے وفد کو لرزہ بر اندام کردیا ،ان کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا:
''خدا کی قسم !میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بارگاہ الہیٰ میں دعا کریں گے تو روئے زمین پر تمام نصاریٰ نابود ہو جا ئیں گے''اسکے بعد وہ پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورمباہلہ سے دست بردار ہونے کی عذرخواہی کی ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : لہذا اسلام لائو۔
انہوں نے کہا :اسلام لانے سے بھی معذورہیں ۔
آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا : تو پھر ہم تم لوگوں سے جنگ کریں گے۔
انہوں نے کہا:مسلمانوں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے ،لیکن سالانہ جزیہ دیں گے اوراسلام کی پناہ میں زندگی کریں گے اسطرح اختلاف ختم ہوا ۔
مباہلہ میں پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی ،حضرت فاطمہ زہرااور حسنین کے آنے سے واضح ہوا کہ آیہ شریفہ(ابنا ئنا ونسائنا وانفسنا )، پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم ،علی ،فاطمہ،اورحسن وحسین علیہم السلام کے علاوہ کوئی اورنہ تھا ۔دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا ئے کہ جوپیغمبر نے''اپنے نفس'' فرمایا اس سے مقصودخودآپصلىاللهعليهوآلهوسلم اور علی تھے ،اوریہ جو فرمایا''اپنی عورتیں ''اس سے مقصود فاطمہ تھیں اوریہ جوفرمایا''اپنے فرزند'' اس سے مقصود''حسنین''تھے ۔
یہاں پر اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام بمنزلۂ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ۔اوریہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام چار افراد تھے ،کیونکہ شخص کے ہر اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ جن کاتعارف وہ خود کلمہ ''انفس ،نسائنا وابنائنا'' (ہمارے نفس، ہماری عورتیں ،اور ہمارے بچوں) سے کرائے ہیں .اگر اہل بیت میں ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا توپیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوبھی مباہلہ کے لئے ہمراہ ضرورلے آتے ۔
اس سے ان چار ہستیوں کی عصمت ثابت ہوتی ہے،کیونکہ خدائے متعال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کی عصمت وطہارت کی گو اہی دے رہا ہے :
(...( انّما یرید اللّه لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً ) (احزاب٣٣)
''بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت ! تم سے ہر برائی کودور رکھے اور تم کو ا س طرح پاک وپاکیزہ رکھے جو پاک وپاکیزہ رکھنے کا حق ہے ۔''
٢۔جیسا کہ عامہ وخاصہ (سنی وشیعہ )نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاہے :
''مِثْلُ اَهْلُ بَیْتِیْ کَمِثْلِ سَفِیْنةُ نُوْحَ مَنْ رَکَبَهَا نَجٰی وَمَنْ تَخَّلّف عَنها غَرَق''
''میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے ،جواس میں سوار ہوااس نے نجات پائی اور جس نے اس سے رو گردانی کی وہ غرق ہو گیا۔''
٣۔پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک اور متواترہ روایت میں ،جسے عامہ وخاصہ نے نقل کیا ہے،فرمایا ہے :
''انی تارک فیکم الثقلین :کتاب اللّه وعترتی اهل بیتی لن یفتر قا حتی یردا علیَّ الحوض ما ان تمسَّکُتم بِهما لن تضِلُّوابعدی''
میں تمہارے درمیان دوگراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں ،جو کبھی ایک دسرے سے جدا نہیں ہو ں گی ،یہ دو چیزیں خدا کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں جب تک ان دو نوں سے متمسّک رہو گے ،گمراہ نہیں ہو گے۔
ائمہ علیہم السلام کی تقرری
حضرت علی علیہ السلام کی امامت (جیسا کہ معلوم ہوا)خدا کی طرف سے اور پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص سے تھی،اور اسی طرح دوسرے ائمہ علیہم السلام جو حضرت علی کے بعد تھے ،ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا خدا کے حکم سے لوگوں میں تعارف کیاہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام پہلے امام اورمسلمانوں کے پہلے پیشوا تھے ،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنی شہادت کے وقت اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کا تعارف کرایا اور امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی شہادت کے موقع پر اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا اوراسی طرح بارہویں امام تک سلسلہ رہا ۔
ہرامام سے اپنے بعد والے امام کے بارے میں نص کے علاوہ ،پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی (عامہ وخاصہ سے نقل کی گئی بہت سی حدیثوں کے مطابق )اماموں کے بارہ ہونے کے بارے میں یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں ان کے ناموں کے ساتھ تعارف کرایا ہے ۔
ائمہ معصو مین علیہم السلام کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ
حضرت امام علی علیہ السلام
(مسلمانوں کے پہلے امام )
حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیہ السلام پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم وتربیت کے پہلے کامل نمونہ تھے ۔
علی علیہ السلام نے بچپن سے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پرورش پائی تھی ،اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحہ تک ایک سایہ کے مانند ساتھ ساتھ رہے اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی شمع وجود کے گرد پروانہ کی طرح پرواز کرتے رہے ۔جب آخری بارآپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے ،یہ وہ لمحہ تھا جب آپ نے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے جسد مطہر کوآغوش میں لے کر سپرد خاک کیا۔
حضرت علی علیہ السلام ایک عالمی شخصیت ہیں ۔دعوی کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جتنی گفتگو اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہوئی ہے ،اتنی کسی بڑے سے بڑے عالمی شخصیت کے بارے میں نہیں ہوئی ہے ۔شیعہ وسنی اور مسلم وغیر مسلم دانشوروں اور مصنفوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ایک ہزارسے زائد کتا بیں تالیف کی ہیں ۔آپ کے بارے میں دوست ودشمن بے شمار تحقیق اور کھوج کے باوجود آپ کے ایمان میں کسی قسم کا کمزور نقطہ پیدانہیں کر سکے یاآپ کی شجاعت،عفت،معرفت،عدالت اور دوسرے تمام پسندیدہ اخلاق کے بارے میں شمّہ برابر نقص نہیں نکال سکے ،کیونکہ آپ ایک ایسے شخص تھے ،جوفضیلت وکمال کے علاوہ کسی چیز کو نہیں پہچانتے تھے اوراسی طرح آپ میں فضیلت وکمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی ۔
تاریخ گواہ ہے کہ ،پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے آج تک جتنے حکّام نے اسلامی معاشرہ میں حکومت کی ان میں صرف حضرت علی علیہ السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلامی معاشر ہ پر اپنی حکومت کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر پوری طرح عمل کیا اور آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی روش سے ذرہ برابر منحرف نہیں ہوئے اوراسلامی قوانین اورشریعت کو کسی قسم کے دخل وتصرف کے بغیر اسی طرح نافذ کیا ،جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں نافذ ہوئے تھے ۔
دوسرے خلیفہ کی وفات کے بعد نئے خلیفہ کو معین کرنے کے لئے خلیفہ دوم کی وصیت کے مطابق جو چھ رکنی کمیٹی بنا ئی گئی تھی ، اس میں کافی گفتگو کے بعد خلافت کا مسئلہ علی اور عثمان کے درمیان تذبذب میں پڑاعلی کو خلافت کی پیشکش کی گئی ،لیکن اس شرط پرکہ ''لوگوں میں خلیفہ اول اور دوم کی سیرت پر عمل کریں''حضرت علی نے ان شرائط کوٹھکراتے ہوئے فرمایا:''میں اپنے علم سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔''
اس کے بعدوہی شرائط عثمان کے سامنے رکھی گئیں ،انہوں نے قبول کیا اور خلافت حاصل کی ،اگر چہ خلافت ہاتھ میں آنے کے بعددوسری سیرت پر عمل کیا ۔
علی علیہ السلام نے راہ حق میں جن جاں نثاریوں،فداکاریوں اورعفو وبخشش کا مظاہرہ کیا ہے ان میں آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بے نظیر تھے ۔اس حقیقت سے ہرگزانکار نہیں کیاجاسکتا ،کہ اگراسلام کا یہ جاں نثار اور سورمانہ ہوتا ،توکفارو مشرکین ہجرت کی رات کو،اس کے بعد بدرواحد،خندق وخیبر وحنین کی جنگوں میں نبوت کی شمع کوآسانی کے ساتھ بجھا کر حق کے پر چم کو سر نگوں کر دیتے۔
علی علیہ السلام نے جس دن سماجی زندگی میں قدم رکھا ،اسی لمحہ سے انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے ،پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ،آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد ، یہاں تک کہ اپنی با عظمت خلافت کے دنوں میں فقیروں اور پسماندہ ترین افراد جیسی زندگی بسر کرتے تھے ،خوراک ،لباس اور مکان کے لحاظ سے معاشرہ کے غریب ترین افراد میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں تھا اور آپ فرماتے تھے ۔
''ایک معاشرے کے حاکم کواس طرح زندگی بسر کرنی چاہئے کہ ضرورت مندوں اور پریشان حال افراد کے لئے تسلی کاسبب بنے نہ ان کے لئے حسرت اور حوصلہ شکنی کا باعث ہو۔''(۱)
علی علیہ السلام اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے محنت و مزدوری کرتے تھے، خاص کر کھیتی باڑی سے دلچسپی رکھتے تھے ،درخت لگا تے تھے اور نہر کھو دتے تھے ،لیکن جو کچھ اس سے کماتے تھے یا جنگوں میں جومال غنیمت حاصل کرتے تھے ،اسے فقرا اورحاجتمندوں میں تقسیم کرد یتے تھے ۔جن زمینوں کو آباد کرتے تھے انھیں یا وقف کرتے تھے یا ان کو بیج کر پیسے حاجتمندوں کو دیتے تھے ۔اپنی خلافت کے دوران ایک سال حکم دیا کہ آپ کے اوقاف کی آمدنی کو پہلے آپ کے پاس لایا جائے پھرخرچ کیا جائے۔جب مذکورہ آمدنی جمع کی گئی تو یہ سونے کے ٢٤ ہزاردینار تھے ۔
علی علیہ السلام نے اتنی جنگوں میں شرکت کی لیکن کبھی کسی ایسے دشمن سے مقابلہ نہ کیا جسے موت کے گھاٹ نہ اتار دیا ہو ۔آپ نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھائی اور فرماتے تھے :
''اگر تمام عرب میرے مقابلہ میں آ جائیں اور مجھ سے لڑیں تو بھی میں شکست نہیں کھا ئوں گا اور مجھے کوئی پروا نہیں ہے ۔''
علی علیہ السلام ایسی شجاعت وبہادری کے مالک تھے کہ دنیا کے بہادروں کی تاریخ آپ کی مثال پیش نہ کرسکی ،اس کے باوجود آپ انتہائی مہر بان،ہمدرد،جوانمرد اور فیاض تھے۔ جنگوں میں عورتوں ،بچوںاور کمزوروں کو قتل نہیں کرتے تھے اور ان کو اسیر نہیں بناتے تھے بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔
جنگ صفین میں معاویہ کے لشکرنے سبقت حاصل کر کے نہرفرات پر قبضہ کرلیا اور آپ کے لشکر پر پانی بند کر دیا ،حضرت علی علیہ السلام نے ایک خونین جنگ کے بعدنہر سے دشمن کا قبضہ ہٹا دیا،اس کے بعد حکم دیا کہ دشمن کے لئے پانی کاراستہ کھلا رکھیں ۔
خلافت کے دوران کسی رکاوٹ اوردربان کے بغیر ہر ایک سے ملاقات کر تے تھے اورتنہااورپیدل راستہ چلتے تھے ،.گلی کوچوں میں گشت زنی کرتے تھے اور لوگوں کو تقوی کی رعایت کرنے کی نصیحت فرماتے تھے اور لوگوں کو ایک دوسروں پرظلم کرنے سے منع کرتے تھے ،بے چاروں اوربیوہ عورتوں کی مہر بانی اور فروتنی سے مدد فرماتے تھے ۔یتیموں اورلاوارثوں کو اپنے گھر میں پالتے تھے ،ان کی زندگی کی ضرورتوں کو ذاتی طور پر پورا کرتے تھے اوران کی تربیت بھی کرتے تھے ۔
حضرت علی علیہ السلام علم کو بے حد اہمیت دیتے تھے اورمعارف کی اشاعت کے میں خاص توجہ دیتے تھے ،اور فرماتے تھے:
''نادانی کے مانند کوئی درد نہیں ہے''(۲)
جمل کی خونین جنگ میں آپ اپنے لشکر کی صف آرائی میں مشغول تھے ،ایک عرب نے سامنے آ کر''توحید''کے معنی پوچھے۔لوگ ہر طرف سے عرب پر ٹوٹ پڑے اور اس سے کہاگیا ایسے سوالات کا یہی وقت ہے؟!حضرت نے لوگوں کو اعرابی سے ہٹاکر فرمایا :
''ہم لوگوں سے ان ہی حقائق کو زندہ کرنے کے لئے لڑ رہے ہیں ''(۳)
اس کے بعد اعرابی کواپنے پاس بلایا ،اپنے لشکرکی صف آ رائی کرتے ہوئے اعرابی کو ایک دلکش بیان سے مسئلہ کی وضاحت فرمائی ۔
اس قسم کے واقعات حضرت علی علیہ السلام کے دینی نظم وضبط اور ایک حیرت انگیزخدائی طاقت کی حکایت کرتے ہیں ۔جنگ صفین کے بارے میں مزید نقل کیا گیا ہے کہ ،جب دو لشکر دو تلاطم دریائوں کے مانند آپس میں لڑرہے تھے اور ہر طرف خون کادریا بہہ رہاتھا۔ توحضرت اپنے ایک سپاہی کے پاس پہنچے،اس سے پینے کے لئے پانی مانگا۔
سپاہی نے لکڑی کا ایک پیالہ نکالااوراس میں پانی بھر کے پیش کیا ،حضرت نے اس پیالہ میں ایک شگاف مشاہدہ کیا اور فرمایا :''ایسے برتن میں پانی پینااسلام میں مکروہ ہے۔''
سپاہی نے عرض کی :اس حالت میں کہ جب ہم ہزاروںتیروں اور تلواروںکے حملہ کی زد میں ہیں اس قسم کی دقت کرنے کا موقعہ نہیں ہے !
اس سپاہی کو آپ نے جوجواب دیا،اس کا خلاصہ یہ ہے:''ہم ان ہی دینی احکام و قوانین کو نافذکر نے کے لئے لڑ رہے ہیں اور احکام چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں''
اس کے بعد حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاکر سامنے کیا اورسپاہی نے پیالہ میں بھرا پانی آپ کے ہاتھوں میں ڈال دیا ۔
حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے بعدایسے پہلے شخص ہیں کہ جنہون نے علمی حقائق کو فلسفی طرز تفکر ،یعنی آزاداستدلال میں بیان فرمایااور بہت علمی اصطلا حیں وضع کیں اور قرآن مجید کی غلط قرأت اورتحریف سے حفاظت کے لئے عربی زبان کے قو ا ئد ''علم نحو'' وضع کئے اور ان کو مرتب کیا ۔
آپ کی تقریروں ،خطوط اوردیگرفصیح بیانات میں ،معارف الہی،علمی،اخلاقی ،سیاسی یہاں تک کہ ریاضی کے مسائل میں جوباریک بنیی پائی جاتی ہے ، یقینا وہ حیرت انگیزہیں۔
امام علی علیہ السلام کے فضائل کا خلاصہ
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو چھ سال کی عمر میں حضرت ابوطالب کے یہاں سے اپنے گھر لے آئے اور ان کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔حضرت علی علیہ السلام اسی دن سے ایک سایہ کے مانند پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اورآنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم سے آخری بار اس وقت جدا ہوئے ،جب آپ نے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے جسد مطہر کوسپرد خاک کیا۔
حضرت علی علیہ السلام پہلے کامل نمونہ ہیں جو پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کی تعلیم وتربیت کے مکتب میں پروان چڑھے ۔آپ پہلے شخص ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ ہی سب سے آخر میں حضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم سے جدا ہوئے ۔
بعثت کے پورے زمانہ میں جو خدمات حضرت علی علیہ السلام نے خدا کے دین کے لئے انجام دیئے ،دوست ودشمن گواہ ہیں کہ وہ خدمات کوئی اورانجام نہیں دے سکا ہے ۔
حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کی سب سے اہم جنگوں میں شرکت فرمائی اور جنگ کے تمام خونین میدانوں میں مسلمانوں کے اندربے مثال بہادری اور کامیابی کا راز آپ ہی تھے ۔چنانچہ بڑے بڑے صحابی جنگوں میں بار ہا بھاگ جاتے تھے ،لیکن آپ نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی اور کوئی حریف آپ کی تلوار کی وار سے بچ نہ سکا ۔اس بے نظیر شجاعت ،جوضرب المثل بن چکی تھی ،کے باوجودآپ ہمدرداورمہر بان تھے ،کبھی اپنے زخمی دشمن کوقتل نہیں کرتے تھے اور جنگ سے بھاگنے والوں کاپیچھا نہیں کرتے تھے ۔
حضرت علی علیہ السلام ،اپنی تقریروں،کلمات قصار اور اپنے گوہربار بیانات،جویاد گار کے طورپر مسلمانوں کے پاس موجود ہیں ،کے اعتبار سے مسلمانوں میں قرآن مجید کے بلند مقاصد کے بارے میں معروف ترین شخص ہیں ۔آپ نے اسلام کے اعتقادی و علمی معارف کو کما حّقہ حاصل کر کے حدیث شریف:
''انا مدینةالعلم وعلی بابها'' (۴)
کوثابت کردیا اوراس علم کوعملی جا مہ پہنایا ۔ حضرت علی علیہ السلام کا دینداری، عفت نفس اورزھدوتقویٰ میں کوئی نظیر نہیں تھا۔آپ اپنے معاش کے لئے روزانہ محنت ومشقت کرتے تھے ، بالخصوص زراعت کو بہت پسند کرتے تھے ۔بنجر زمینوں کوآباد کرتے تھے ،نہریں کھودتے تھے ،درخت لگاتے تھے،جس جگہ کو آباد کرتے اسے مسلمانوںکے لئے وقف کر دیتے تھے یا اس کو بیچ کر پیسے فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے اورخود نہایت زھدوقناعت کے ساتھ فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ جس دن شہید ہوئے ۔باوجوداس کے کہ تمام اسلامی ممالک کے فرمانروا تھے ۔آپ کی پونجی صرف سات سودرہم تھی جنھیں آپ اپنے گھر کے لئے ایک خدمت گار پرصرف کرنا چاہتے تھے۔
حضرت علی علیہ السلام کی عدالت ایسی تھی کہ خداکے احکام کے نفاذاور لوگوں کے حقوق کو زندہ کرنے میں ہرگز کسی طرح کے استثناء کے قائل نہیں تھے ۔آپ ذاتی طور پرگلی کوچوں میں گشت لگاتے تھے اور لوگوں کو اسلامی قوانین کی رعایت کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔
حضرت امیرالمؤ منین کا طریقہ
چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے مسائل میں ولی ہونا،آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص کے مطابق خدائے متعال کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کے لئے مخصوص تھا ،لیکن اسے انتخابی خلافت میں تبدیل کیا گیا اور اس طرح خلافت کی کرسی پر دوسرے لوگوں نے قبضہ جمایا ۔
حضرت علی علیہ السلام اورآنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خاص صحابیوں جیسے سلمان فارسی ،ابوذرغفاری اورمقداد اسدی نے لوگوں سے ایک اعتراض کیا لیکن انھیں مثبت جواب نہیں ملا۔
حضرت علی علیہ السلام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرکے ایک مدت تک اپنے گھر میں قرآن مجیدجمع کرنے میں مصروف رہے ۔اس کے بعد کچھ خاص صحابیوںاور چنددیگرافراد کی تعلیم وتربیت میں مشغول ہوئے ۔
حضرت علی علیہ السلام کا ماضی درخشان اور بے مثال تھا ۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے وزیر اور اسلامی فتوحات کی کلید تھے .علم ودانش میں ، فیصلہ دینے میں ، سخن وری اور دیگرتمام معنوی فضائل میں آپ تمام مسلمانوں پر برتری رکھتے تھے ۔اس کے باوجودخلیفہ اول کے زمانے میں اجتماعی مسائل اور عمومی کام میں آپ سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کیاگیا ،اس لئے آپ صرف خدا کی عبادت اور چند اصحاب کی علمی وعملی تربیت میں مشغول رہتے تھے اورایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے ۔
خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی کسی کام کوآپ کے حوالہ نہیں کیا جاتا تھا ،لیکن کسی حدتک آپ سے رجوع کرتے تھے اور اہم مسائل میں آپ کے نظریات سے استفادہ کیا جاتا اور آپ سے مشورہ لیا جاتاتھا ۔چنانچہ خلیفہ دوم نے بارہا کہا ہے:(اگرعلی کی رہنمائی نہ ہوتی ،توعمرہلاک ہوجاتا)۔(۵)
خلیفہ سوم کے زمانہ میں لوگوں کی توجہ آپ کی طرف زیادہ ہوئی اوراس پوری ٢٥سالہ
مدت میں آپ کی تعلیم وتربیت کادائرہ دن بدن وسیع تر ہوتاگیا یہاں تک کہ مکتب ولایت سے بالواسطہ اور بلاواسطہ تربیت پانے والوں کی ایک بڑی جماعت نے خلیفہ سوم کے قتل کے فورابعد آپ کے پاس ہجوم کیا اورآپ کوخلافت قبول کرنے پر مجبور کیا ۔
حضرت امیرالمو منین نے خلافت کی باگ ڈورسنبھالتے ہی پیغمبراسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کی سیرت کو۔جیسے مدتوںسے فراموش کیاگیاتھا۔پھر سے زندہ کیا۔آپ نے مساوات اوراجتماعی عدالت نافذ کرکے تمام بیجا امتیازات کوختم کردیا۔تمام لاابالی گورنروںاورفرمانرواؤں کو معزول کردیااورانکے بیت المال سے لوٹے گئے مال ودولت اور خلیفہ کی طرف سے مختلف لوگوں کوبے حساب دی گئی جاگیروں و املاک کوضبط کیا،اور دینی ضوابط اورقوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کومناسب سزائیں سنائیں ۔
اثرو رسوخ رکھنے والے لیڈروںاورناجائز منافع حاصل کرنے والوں نے جب دیکھا کہ ان کے ذاتی منافعے خطرے میں پڑ رہے ہیں،توانہوں نے مخالفت کاپرچم بلند کر کے عثمان کے خو ن کابدلہ لینے کے بہانے سے داخلی خونین جنگوں کی آگ بھڑکادی جوحضرت کی مشکلات کاسبب اوراصلاحات رکھنے میں رکاوٹ بن گئیں ۔
حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے پانچ سالہ دور میں کمر توڑ َمشکلات کے باوجود بے شمار افراد کی تربیت کی اوراپنی تقریروں اورفصیح بیانات کے ذریعہ علمی میدان کے مختلف ہنروفنون کے گراں بہا خزانے یادگارکے طور پر چھوڑدئے ،ان میں سے ایک علم نحوکے اصولوںکا وضع کرنا ہے جو حقیقت میں عربی زبان کے قواعد وضوابط ہیں ۔
آپ کی بر جستہ شخصیت کے اوصاف ناقابل بیان ہیں ،آپ کے فضائل بے انتہا اور بے شمار ہیں ۔تاریخ ہرگز کسی ایسے شخص کو پیش نہیںکر سکتی جس نے آپ کے برابر دنیا کے دانشوروں، مصنّفوں اور متفکروں کے افکار کو اپنی طرف جذب کیا ہو۔
____________________
١۔نہج البلاغہ فیض الاسلام ،خطبہ ٢٠٠،ص٦٦٣۔
۲۔شرح غرر الحکم ،ج٢،ص٣٧٧،ح٢٨٨٢۔
۳۔ بحارالانوار،ج٣،ص٢٠٧ ،ح١۔
۴۔بحارالانوار،ج٤٠،ص٢٠١۔
۵۔بحارالانوار،ج٤٠ص٢٢٩۔
حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
(دوسرے امام)
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد خلافت کی باگ ڈور سنبھالی۔آپ معاویہ کے بلوے کو دبانے کے لئے ایک لشکر کو مسلح اور منظم کرنے میں لگ گئے ۔آپ نے لوگوں میں اپنے نانااور والدگرامی کی سیرت کو جاری رکھا ۔لیکن کچھ مدت کے بعد معلوم ہوا کہ معاویہ کی مخفیانہ سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے آپ کی کوششیں نا کام ہورہی ہیں ،آپ کے لشکر کے سردارمعاویہ سے سازباز کر چکے ہیں ،اوریہاںتک آمادہ تھے کہ آپ کوگرفتار کرکے معاویہ کے حوالہ کردیں یاقتل کردیں ۔
بدیہی ہے کہ ایسے حالات میں معاویہ سے جنگ کرنے میں امام حسن مجتبیٰ کے لئے شکست و ناکامی یقینی تھی، یہاں تک کہ اگر امام تنہا یا اپنے نزدیک ترین افراد کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہوتے ،تو معاویہ کی سلطنت میں کسی قسم کی ہلچل نہ مچتی اور لوگوں کے دلوںپر بھی کوئی اثرنہ ہوتا،کیونکہ معاویہ اپنی مخصوص شاطرانہ چال سے آسانی کے ساتھ آپ کو مختلف ذرایع حتی اپنے ہی افراد کے ذریعہ قتل کراسکتا تھا،اس کے بعد لباس عزا پہن کر آپ کی انتقام کادعویٰ کر کے فرزند پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے خون سے اپنے دامن کو دھوسکتا تھا ۔ان ناگفتہ بہ حالات کے پیش نظر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ کی طرف سے صلح کی تجویز کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا اور خلافت سے دستبر دارہوگئے ۔لیکن معاویہ نے تمام شرائط کو پامال کر کے ان میں سے کسی ایک پر عمل نہیں کیا۔
حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنی ،اپنے بھائی حضرت امام حسین اور اپنے چند اصحاب کی جان کو یقینی خطر ہ سے بچالیا اور اپنے خاص اصحاب کا ایک مختصرومحدود لیکن حقیقت پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا اور اصلی اسلام کو بالکل نا بود ہونے سے بچالیا۔
البتہ معاویہ ایسا شخص نہیں تھا جو امام حسن مجتبیٰ کے مقصد اورآپ کے منصوبہ سے بے خبر رہتا،اس لئے صلح بر قرار ہونے اور پورے طور پر تسلط جمانے کے بعد معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں اورحامیوں کو جہاں کہیں پایا ان کو مختلف ذرائع سے نابود کردیا ،اگر چہ صلح کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ خاندان ر سالت کے حامی اوردوست امان میں رہیں گے۔
بہر حال معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے مقدمات کو مستحکم کرنے کے لئے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو آپ کی بیوی کے ہاتھوں زہر دلا کر شہید کرا یا ،کیونکہ صلح نامہ کے دوسرے شرائط میں یہ بھی تھا کہ معاویہ کے بعد خلافت پھر سے حضرت امام حسن مجتبی کو ملے گی ۔
حضرت امام حسین علیہ السلام
(تیسرے امام)
حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے برادر بزرگوار کے بعد حکم خد ا اور اپنے بھائی کی وصیت سے امامت کے عہدہ پرفائز ہوئے او رمعاویہ کی خلافت کے دوران تقریباًدس سال زندگی گزاری اوراس مدت میں اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے رہے اور جب تک معاویہ زندہ تھا امام کوئی موثرکام انجام نہ دے سکے ۔تقریباً ساڑھے نوسال کے بعد معاویہ مر گیا ،اورخلافت جوسلطنت میں تبد یل ہو چکی تھی اس کے بیٹے یزید کو ملی ۔
یزید ،اپنے ریاکار باپ کے برعکس ،ایک مست ،مغرور،عیاش،فحاشی میں ڈوبا ہوا اور لاابالی جوان تھا ۔یزید نے حکومت کی باگ ڈورسنبھالتے ہی مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس کے لئے بیعت لے ورنہ ان کا سر قلم کر کے اس کے پاس بھیجدے ۔اس کے بعد مدینہ کے گورنر نے حکم کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا،آپ نے مہلت چاہی اور رات کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ راہی مکہ ہوئے ۔اورحرم خدا میں ،جواسلام میں ایک سرکاری پناہ گاہ ہے ،پناہ لی ،لیکن وہاں پر کچھ مہینے گزار نے کے بعد ،سمجھ گئے کہ یزید کسی قیمت پر آپ سے دست بردارہونے والا نہیںہے ،اوربیعت نہ کرنے کی صورت میں ،آپ کاقتل ہونا قطعی ہے۔اور دوسری جانب سے اس مدت کے دوران عراق سے کئی ہزار خطوط حضرت کی خدمت مین پہنچے تھے کی جن میں آپ کی مدد کاوعدہ دے کر ظالم بنی امیہ کے خلاف تحریک چلانے کی دعوت د ی تھی ۔
امام حسین علیہ السلام عمومی حالات کے مشاہدہ سے اورشواہدوقرائن سے سمجھ چکے تھے کہ آپ کی تحریک ظاہری طورپر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے،اس کے باوجود یزید کی بیعت سے انکار کرکے قتل ہونے پر آمادہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تحریک کا آغاز کر کے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔راستہ میں سرزمین کربلا (کوفہ سے تقریبا ً ستر کلومیٹر پہلے) دشمن کے ایک بڑے لشکر سے آپ کی مڈ بھیڑ ہوئی۔
امام حسین علیہ السلام راستہ میں لوگوں کو اپنی مدد کے لئے دعوت دے رہے تھے اوراپنے ساتھیوں سے تذکرہ کرتے تھے کہ اس سفر میں قطعی طورپر قتل ہونا ہے اور اپنا ساتھ چھوڑ نے پر اختیا ر دیتے تھے، اسی لئے جس دن آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوا توآپ کے گنے چنے جان نثار ساتھی باقی بچے تھے جنہوں نے آپ پر قربان ہونے کا فیصلہ کیا تھا ،لہٰذاوہ بڑی آسانی کے ساتھ دشمن کی ایک عظیم فوج کے ذریعہ انتہائی تنگ محاصرہ میں قرار پائے اور یہاں تک کہ ان پر پانی بھی بندکیاگیا ،اور ایسی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو بیعت کرنے یا قتل ہونے کے درمیان اختیار دیاگیا ۔
امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کیااورشہادت کے لئے آمادہ ہوگئے۔ ایک دن میں صبح سے عصر تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن سے لڑتے رہے ۔اس جنگ میں خود امام،آپ کے بیٹے، بھائی ،بھتیجے ،چچیرے بھائی اورآپ کے اصحاب کہ جن کی کل تعدادتقریباستر افراد کی تھی، شہید ہوئے ۔صرف آپ کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام بچے،جو شدیدبیمار ہونے کی وجہ سے جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے ۔
دشمن کے لشکر نے،حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مال کو لوٹ لیا اورآپ کے خاندان کو اسیر بنا لیا اورشہداء کے کٹے ہوئے سروں کے ہمراہ اسیروں کو کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا ۔
اس اسیری میں امام سجاد علیہ السلام نے شام میں اپنے خطبہ سے اسی طرح حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا نے کوفہ کے مجمع عام میں اور کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں اور شام میں یزید کے دربار میں اپنے خطبوں سے حق سے پردہ اٹھایا اور بنی امیہ کے ظلم وستم کو دنیا والوں کے سامنے آشکار اور واضح کردیا ۔
بہرحال امام حسین علیہ السلام کی تحریک ،ظلم ، و زیادتی اورلاابالی کے مقابلہ میں خود آپ اورآپ کے فرزندوں ،عزیزوں اوراصحاب کے پاک خون کے بہنے اورمال کی غارت اورخاندان کی اسیری پر ختم ہو ئی ۔یہ تحریک اپنی خصوصیات و امتیازات کے پیش نظر اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ ہے انقلاب کی تاریخ کے صفحات پر رقم ہے ۔یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام اس واقعہ سے زندہ ہے اور اگریہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو بنی امیہ اسلام کا نام ونشان باقی نہ رکھتے۔
اس جانکاہ واقعہ نے نمایاں طور پر پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اہل بیت علیہم السلام کے مقاصد کو بنی امیہ اوران کے طرفداروں کے مقاصد سے جدا کر کے حق وباطل کوواضح وروشن کردیا۔
یہ واقعہ نہایت کم وقت میں اسلامی معاشرہ کے کونے کونے میں منتشر ہوا اورشدیدانقلابوں اور بہت زیادہ خونریزوںکا سبب بنا جو بارہ سال تک جاری رہے وآخر کاربنی امیہ کے زوال کا ایک بنیادی سبب بنا۔
اس واقعہ کا واضح ترین اثر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی معنوی پرورش کے نتیجہ میں رونما ہوا جن کے دلوں میں علی بن ابیطالب کی ولایت نے جڑ پکڑ لی اوران لوگوںنے خاندان رسالت کی دوستی کواپنالائحہ عمل بنالیا اور دن بدن ان کی تعداد اور طاقت بڑھتی گئی ۔اور آج کی دنیامیں تقریباًدس کروڑمسلمان شیعہ کے نام سے موجود ہیں ۔
کیاامام حسن اورامام حسین علیہما السلام کی روش مختلف تھی ؟
اگرچہ ان دومحترم پیشوائوں کی روش۔جونص پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے مطابق برحق امام ہیں ۔ظاہراً مختلف نظرآتی ہیں،بعض لوگوں نے اس حدتک کہا ہے کہ:ان دوبھائیوں کے درمیان اس حد تک نظریاتی اختلاف پایاجاتاتھا کہ ایک نے چالیس ہزار سپاہی ہونے کے باوجود صلح کی اور دوسرے نے رشتہ داروں کے علاوہ چالیس دوست واحباب کے ساتھ جنگ کی حتی کہ شش ماہہ طفل شیرخوار کو بھی اس راہ میں قربان کیا۔
لیکن عمیق اوردقیق تحقیقات سے اس نظریہ کے خلاف ثابت ہوتا ہے،کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام تقریباً ساڑھے نوسال معاویہ کی سلطنت میں رہے اورکھلم کھلا مخالفت نہیں کی ۔امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کی شہادت کے بعد تقریباً ساڑھے نوسال معاویہ کی سلطنت میں زندگی گزاری اور تحریک کا نام تک نہیں لیا اور مخالفت نہیں کی ۔
پس دونوں کی روش میں اس ظاہری اختلاف کی اصلی ا بنیاد کو معاویہ اور یزید کی متضاد روشوں میں ڈھونڈ نا چاہئے نہ کہ ا ن دو محترم پیشوائوں کے نظریاتی اختلاف میں ۔
معاویہ کی روش بظاہراایک ایسی روش نہیں تھی جو بے دینی پر استوارہو اوراپنی اعلانیہ مخالفت سے احکام دین کا مذاق اڑائے ۔
معاویہ اپنے آپ کو ایک صحابی اور کاتب وحی کے طورپرپہچنواتا تھا اور اپنی بہن کے ذریعہ (جو زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المٔو منین تھیں )اپنے آپ کو ''خال المومنین''کہلاتا تھا اور خلیفہ دوم کا مور د اعتماد تھا اورعام لوگ خلیفہ پرپورا اعتماداورخاص احترام رکھتے تھے ۔
اسکے علاوہ اس نے لوگو ں کی نظر میں پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے قابل احترام اکثراصحاب (جیسے ابوہریرہ،عمروعاص،سمرہ،بسر اورمغیرةبن شعبہ و غیرہ)کو گورنری اوردیگر حساس حکومتی عہدوںپر فائز کیاتھا جولوگوں کے حسن ظن کو اس کی طرف مبذول کرتے تھے اور لوگوں میں اس کے فضائل اور دین کے سلسلہ میں صحابہ کے محفوظ ہونے کے بارے میں ۔یعنی جو کام بھی انجام دیں معذور ہیں۔ بہت سی روایتیں نقل کرتے تھے،لہذا معاویہ جوبھی کام انجام دیتا تھا وہ قابل توجیہ ہوتا تھا اور جب اس سے کام نہیں بنتا تھا تو معاویہ بھاری انعام واکرام اور لالچ دے کر اعتراض کرنے والوں کا منہ بندکرتاتھا ۔جہاں پر یہ حربہ کارگر ثابت نہیں ہوتا تھا ،تواپنے انہی حامیوں اور طرفداروں کے ذریعہ مخالفت کرنے والوں کو نابود کراتاتھا ۔چنانچہ اس کے ان ہی حامی صحابیوں کے ہاتھوں ،دسیوں ہزاربے گناہ شیعیان علی اوردیگر مسلمانوں حتی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کی ایک جماعت کو بھی قتل کیا گیا ۔
معاویہ تمام کاموں میں ایک حق بجانب روپ اختیارکرتا تھا اور ایک خاص صبرو تحّمل سے قدم بڑھاتا تھا اورایک خاص مہربانی سے لوگوں کو اپنا محب اور مطیع بنا لیتا تھا یہاں تک کہ کبھی اپنے خلاف گالیاں سنتاتھا اور جھگڑوں سے رو برو ہوتا تھا،لیکن خنداں پیشا نی اور عفوو بخشش کے ساتھ جواب دیتا تھا ،وہ اس طرح اپنی سیاست کو نافذ کرتاتھا ۔
حضرت امام حسن اورامام حسین علیہما السلام کابظاہراحترام کرتاتھا اوردوسری طرف سے اعلان کرتااتھا جوبھی شخص اہل بیت علیہم السلام کے فضّائل میں کوئی حدیث بیان کرے گا اس کی جان ومال اور عزت و آبرو کسی صورت میں محفوظ نہیں ہے اور جوشخص اصحاب کی منقبت میں کوئی حدیث بیان کرے گا تو اسے انعام واکرام سے نوازا جائیگا۔
اسی طرح یہ بھی حکم دیتا تھا کہ خطباء مسلمانوں کے منبروں سے علی کو(لازمی طورپر)گالیاں دیںاور اس کے حکم سے حضرت علی کے حامیوں کو جہاں بھی پاتے تھے موقع پر ہی قتل کرڈالتے تھے اوراس کام میں اس قدر زیادتی کی کہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں کی ایک بڑی تعداد کوبھی آپ کی دوستی کے الزام میں قتل کیا گیا ۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے انقلاب سے اسلام کونقصان پہنچتا۔ اور آپ اور آپ کے ساتھیوں کا خون رایگان ہوتا۔
ان حالات میں بعید نہیں تھا معاویہ امام حسین کو اپنی ہی افراد میں سے کسی کے ذریعہ قتل کرواتااور اس کے بعد عام لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور افکار کو بدلنے کے لئے آپ کے ماتم میں اپنا گریبان چاک کرتا اورآپ کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے سے آپ کے شیعوں کا قتل عام کرتا،کیونکہ اس نے یہی رویہ عثمان کے بارے میں اختیار کیا تھا ۔(۱)
لیکن یزید کی سیاسی روش کسی صورت میں اس کے باپ کی روش سے مشابہ نہیں تھی ۔وہ ایک خود خواہ اور لا ابا لی و بے دین جوان تھا ،زور وزبردستی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا،لوگوں کے افکار و نظریات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا ۔
یزید نے اسلام کوپس پردہ پہنچائے جانے والے نقصانات کو اپنے مختصر دور حکومت میں اچانک آ شکار کیا اور اس سے پردہ ہٹادیا۔
اپنی حکومت کے پہلے سال میں ،خاندان پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کا قتل عام کیا ۔
دوسرے سال مدینہ منورہ کو منہدم کیا اور تین دن تک لوگوں کی عزت،ناموس اور جان ومال کواپنے سپاہیوں کے لئے مباح قرار دیا۔
تیسرے سال کعبہ کو منہدم کردیا۔
اسی وجہ سے ،امام حسین علیہ السلام کے انقلاب نے لوگوں کے ذہنوںاور افکار میں جگہ پائی اورروز بروز یہ اثر گہرا اورنمایاںہوتاگیا اور ابتدائی مرحلہ میں خونین انقلابوں کی صورت میں ظاہر ہوا اورآخرکارمسلمانوں کی ایک عظیم تعداد کوحق وحقیقت کے حامیوں اور محبان اہل بیت علیہم السلام کے عنوان سے وجود میں لایا۔
١۔تاریخ گواہ ہے کہ عثمان نے معاویہ سے مسلسل مدد کی درخواست کی لیکن معاویہ نے اسکامثبت جواب نہیں دیا ،لیکن جب عثمان قتل کئے گئے تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے بہانہ سے امیرالمؤ منین حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی ۔
یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے یزید کو اپنی وصیتوں کے ضمن میں تاکیدو نصیحت کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی سروکار نہ رکھے اوران پراعتراض نہ کرے۔لیکن کیا یزیدکی مستی اورخودخواہی اسے اس با ت کی اجازت دیتی کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان میں تمیز دے سکے ؟!
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
(چوتھے امام)
امام سجاد علیہ السلام نے اپنی امامت کی مدت میں جس روش کو اختیار کیااسے دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے کہ جو مجموعی طورپر ائمہ اطہار علیہم السلام کی عام روش کے مطابق ہے۔ حضرت امام سجادعلیہ السلام کربلا کے جانکاہ واقعہ میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ تھے اورحسینی انقلاب میں شریک تھے اور آپ کے والدگرامی کی شہادت کے بعد آپ اسیر کئے گئے اور کربلاسے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائے گئے۔امام سجاد علیہ السلام نے اپنی اسیری میں تقیہ سے کام نہیں لیا اور بلا جھجک حق وحقیقت کا اظہار کرتے تھے ،اور موقع و محل کے مطابق اپنی تقریروں اور بیانات کے ذریعہ خاندان رسالت کی حقا نیت اوران کے فخر ومباہات کو عام وخاص تک پہنچاتے تھے اور اپنے والد بزگوار کی مظلو میت اور بنی امیہ کے دردناک ظلم وستم اور بے رحمی کو تشت ازبام کر کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو ایک پر تلاطم طوفان میں تبدیل کرتے تھے ۔
لیکن قید اور اسیری سے رہائی پانے کے بعد ،امام سجاد علیہ السلام مدینہ لوٹے اورجاںنثاری کا ماحول آرام وسکون کے ماحول میں تبدیل ہوا ،گھر میں گوشہ نشینی اختیار کی اور غیروں کے لئے دروازہ بندکردیا اور خدائے متعال کی عبادت میں مشغول ہوئے ۔اور خاموشی سے حق و حقیقت کے حامیوں کی تربیت کرتے رہے۔
حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنی امامت کے ٣٥سال کے دوران بالواسطہ یا براہراست لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی پرورش وتربیت کی اور ان کو اسلامی معارف کی تعلیم دی۔
جو دعائیں حضرت امام سجاد علیہ السلام محراب عبادت میں آسمانی لہجہ میں پڑ ھتے اور ان کے ذریعہ اپنے پروردگار سے رازونیاز فرماتے تھے ، وہ عظیم اسلامی معارف کے ایک مکمل دورہ پر مشتمل ہیں ۔ دعائوں کے مجموعہ کو ''صحیفئہ سجادیہ ''کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
(پانچویں امام)
حضرت امام محمدباقر علیہ السلام کی امامت کے زمانہ میں دینی علوم کی نشرو اشاعت کے لئے کسی حدتک ماحول سازگار ہوا ۔بنی امیہ کے د بائوکے نتیجہ میں اہل بیت علیہم السلام کی احادیث نابود ہو چکی تھیں جبکہ احکام کے لئے ہزاروں احادیث کی ضرورت ہوتی ہے ،لیکن اصحاب کے ذریعہ پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کی نقل کی گئی احادیث کی تعداد پانچ سوسے زیادہ نہ تھی ۔
مختصر یہ کہ اس زمانے میں کربلا کے جانکاہ واقعہ اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ٣٥سالہ کوششوں کے نتیجہ میں شیعوں کی ایک بڑی تعداد و جودمیں آگئی تھی۔لیکن وہ فقہ اسلامی سے خالی ہاتھ تھے ۔چونکہ بنی امیہ کی سلطنت،اندرونی اختلافات، راحت طلبی اور حکّام کی بے لیاقتی کے نتیجہ میں کمزور ہورہی تھی اور اس کے پیکر میں روز بروز سستی کے آثار نمایاں ہوتے جارہے تھے،لہذ اامام محمد باقرعلیہ السلام نے اس فرصت سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے علوم اہل بیت علیہم السلام اور فقہ اسلامی کے نشرواشاعت کاکام شروع کیا اور تعلیم وتربیت کے بعد اپنے مکتب سے بہت سے دانشوروں کومعاشرے کے حوالے کیا۔
حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام
(چھٹے امام)
چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں اسلامی علوم کی نشرواشاعت کے لئے زمین زیادہ ہموار اورحالات زیادہ مناسب تھے ،کیونکہ حضرت امام محمد باقرکے ذریعہ احادیث کی نشرواشاعت اورآپ کے مکتب کے شاگردوں کی تبلیغ سے لوگوں میں اسلامی معارف اورعلوم اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں شوق پیدا ہو چکا تھا اور حدیث سننے کے تشنہ تھے۔
اس کے علاوہ اموی سلطنت نیست ونابودہوچکی تھی اور عباسی سلطنت ابھی پوری طرح سے مستحکم نہیں ہو سکی تھی اوربنی عباس نے اپنے مقاصدکو حاصل کرنے اور بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت اور شہدائے کربلا کے خون کودستاویز قرار دیا تھا ،لہذا وہ اہل بیت علیہم السلام سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے ۔
اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف علوم کی تعلیم و تربیت کا کام شروع کیا ۔تمام اطراف واکناف سے علماء ودا نشور گروہ در گروہ آپ کے گھر پر آتے تھے اورآپ کی شاگردی کاشرف حاصل کر کے معارف اسلامی کے مختلف ہنر،اخلاق،تاریخ انبیاء وامم اور حکمت و مو عظہ کے بارے میں سوالات کرتے تھے اور جواب حاصل کرتے تھے ۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف طبقات کے لوگوں سے بحثیں کیں اور گونا گوں ملل ونحل سے مناظرے کئے اور علوم کے مختلف شعبوںمیں کافی شاگردوں کی تربیت کی، آپ کی احادیث اور علمی بیانات سے سیکڑوں کتابیں تالیف ہوئی ہیں ،جو ''اصول''کے نام سے مشہورہیں ۔
شیعوںنے،جو اسلام میں اہل بیت علیہم السلام کی روش پر چلتے ہیں،اپنے دینی مقاصداور مسائل سے آپ کی برکتوںسے مکمل طور پر ابہام کو دور کیا ہے اور اپنے مذہبی مجہولات کو آپ کے واضح اور روشن بیانات سے حل کردیا ۔اسی لئے شیعہ مذہب (کہ وہی مذہب اہل بیت ہے )لوگوں میں ''مذہب جعفری''کے نام سے معروف ہوگیا ۔
امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہماالسلام کی تحریک
اگر چہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے پیروئوں میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جارہا تھا ،لیکن بنی امیہ کے حکاّم کی طرف سے اہل بیت علیہم السلام کے پیروئوںپر زبردست دبائو کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام کے لئے ممکن نہیں تھا ،کہ معارف اسلامی کی تعلیم کا کام عملی اور اعلانیہ طورپر انجام دیں،یہاں تک کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ میں اموی سلطنت اندرونی اختلافات اور بنی عباس سے کشمکش کے نتیجہ میں کمزور ہونے کے بعدختم ہوئی گئی۔
اس لئے شیعہ اوراہل بیت علیہم السلام کے پیرو اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ٣٥سالہ امامت کے دوران تر بیت یافتہ شاگردوں کو موقع ملا اور وہ دوردراز علاقوں سے سیلاب کی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر پرآ کر دینی علوم اور اسلامی معارف کی تعلیم حاصل کرتے تھے ۔
امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسلامی معارف کی نشر واشاعت کاکام شروع کیا ،دنیا کے کونے کونے سے آنے والے دانشوروں کو قبول کر کے آپ ان کی تعلیم وتربیت فرماتے تھے اورآپ کی کوششوں کے نتیجہ میں ہزاروں دانشور مختلف علوم و فنون کو آپ سے سیکھ کر دنیابھرمیں ان علوم کی نشرواشاعت میں مشغول ہوئے ۔
حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تالیف کی ہوئی کتابوں کی تعداد چارسوہے جو''اصول اربعمئاة''کے نام سے شیعوں میں معروف ہیں ۔
ان کے بعد آنے والے باقی ائمہ علیہم السلام نے بھی ان دو اماموں کی روش پرعمل کرتے ہوئے معارف اسلامی کی نشرواشاعت کی ،بنی عباس کے سخت اورشدید دبائو کے باوجود ،انہوں نے بھی بہت سے دانشوروں کی پرورش و تربیت کی اوراسلام کے علمی خزانوں کو ان کے حوالے کیا ۔ان ہی ائمہ ھدیٰ علیہم السلام کی کوششوں کے نتیجہ میں آج،دنیا کے کونے کونے میں کروڑوں اہل حق موجود ہیں ۔
حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام
(ساتویں امام)
بنی عباس نے بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد خلافت پر قبضہ جمایا۔پھر اس کے بعدبنی فاطمہ کی طرف رخ کیا اور پوری طاقت کے ساتھ خاندان نبوت کو نابودکرنے پر اترآئے ،کچھ لوگوں کے سر قلم کئے ،کچھ کو زندہ دفنادیا اورکچھ کو عمارتوں کی بنیادوں میں یادیواروں میں چن دیا۔
چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو جلادیا اور خودحضرت کو چند بارعراق بلایا۔اس طرح چھٹے امام کی زندگی کے آخری دنوں میں تقیہ اور سخت ہو گیا تھااور چونکہ حضرت پرشدید پابندی تھی ،لہذاخاص شیعوں کے علاوہ آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے اورآخرکارعباسی خلیفہ منصور کے ذریعہ زہرسے شہید کئے گئے ۔اس طرح ساتویں امام حضرت موسی کاظم کی امامت کے زمانہ میں دشمنوں کا دبائو بہت سخت تھا اور روزبروز بڑھتاجارہا تھا ۔
حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے شدید تقیہ کے باوجود علوم اسلامی کی نشرواشاعت کو جاری رکھا اور بہت سی احادیث کو شیعوں کے حوالہ کردیا ۔چنانچہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آپ سے منقول فقہی احادیث پانچویں اور چھٹے امام کے بعددوسرے ائمہ کی نسبت سب سے زیادہ ہیں۔تقیہ کی شدت کی وجہ سے آپ سے منقول احادیث میں ''عالم وعبدصالح ''جیسی تعبیریں استعمال کی گئی ہیں اور حضرت کا نام صریحاً ذکرنہیں کیا گیا ہے ۔حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام عباسی خلفاء کے چار افراد:منصور،ہادی ،مہدی، اور ہارون کے معاصر تھے ۔آخر کار ہارون کے حکم سے آپ کو گرفتارکر کے قید خانہ میں ڈال دیا گیا اور برسوں تک ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل ہوتے رہے اور سر انجام زندان میں ہی زہردے کر آپ کو شہید کیا گیا ۔
حضرت امام رضا علیہ السلام
(آٹھویں امام)
حالات پر غوروفکر کرنے سے ہر صاحب نظرکے لئے واضح تھا کہ خلفائے وقت اوردشمنان اہل بیت علیہم السلام جتنا ائمہ ھدیٰ کو جسمانی اذیتیں پہنچا کر نابود کرنے کی کوشش کرتے تھے اوران کے شیعوں سے سختی سے پیش آتے تھے ،اتنا ہی ان کے پیروئوں کی تعداد بڑھتی جارہی تھی اور ان کا ایمان مزید مستحکم ہوتا جارہا تھا اوردربار خلافت ان کی نظروں میں ایک نجس اور ناپاک دربار سمجھاجاتا تھا ۔
یہ مطلب،ایک باطنی عقیدہ تھا جو ائمہ اطہارعلیہم السلام کے معاصر خلفاء کو ہمیشہ رنج وعذاب میں مبتلا کر رہا تھا اور حقیقت میں انھیں بے بس اور بیچارہ کرکے رکھدیا تھا۔
مامون ،بنی عباس کا ساتواں خلیفہ تھا اور حضرت امام رضاعلیہ السلام کا معاصر تھا ۔اس نے اپنے بھائی امین کوقتل کرنے کے بعدخلافت پر اپنی گرفت مظبوط کرلی اور اس فکر میں پڑا کہ اپنے آپ کو باطنی رنج وپریشانی سے ہمیشہ کے لئے نجات دے اور زور وزبردستی اوردبائو کے علاوہ کسی اور راستہ سے شیعوں کو اپنے راستہ سے ہٹادے۔
اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے جس سیاست کو مامون نے اختیار کیا ،وہ یہ تھی کہ اپنا ولی عہد ،حضرت امام رضا علیہ السلام کوبنایا تاکہ حضرت کو ناجائز خلافت کے نظا م میں داخل کر کے ،شیعوں کی نظروں میں آپ کو مشکوک کر کے ان کے ذہنوں سے امام کی عصمت وطہارت کو نکال دے ۔اس صورت میں مقام امامت کے لئے کوئی امتیاز باقی نہ رہتا ،جو شیعوں کے مذہب کا اصول ہے ،اس طرح ان کے مذہب کی بنیادخود بخود نابود ہو جاتی۔
اس سیاست کو عملی جامہ پہنانے میں ایک اور کامیابی بھی تھی وہ یہ کہ،بنی فاطمہ کی طرف سے خلافت بنی عباس کو سرنگوں کرنے کے لئے جو پے درپے تحریکیں سراٹھارہی تھیں ،ان کو کچل دیا جاتا،کیونکہ جب بنی فاطمی مشاہدہ کرتے کہ خلافت ان میں منتقل ہوچکی ہے ،تو فطری طورپراپنے خونین انقلابوںسے اجتناب کرتے۔البتہ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے بعدامام رضاعلیہ السلام کو راستے سے ہٹانے میں مامون کے لئے کوئی حرج نہیں تھا ۔
مامون نے حضرت امام رضاعلیہ السلام کو پہلے خلافت قبول کرنے اوراس کے بعدولی عہدی کاعہدہ قبول کرنے کی پیش کش کی۔امام نے مامون کی طرف سے تاکید ، اصرار اور دھمکی کے نتیجہ میں آخر کار اس شرط پر ولی عہدی کو قبول کیا کہ حکومت کے کاموں میں جیسے عزل ونصب میں مداخلت نہیں کریں گے۔
حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایسے ماحول میں لوگوں کے افکار کی ہدایت کرنے کا کام سنبھالا اور جہاں تک آپ کے لئے ممکن تھا مختلف مذاہب وادیان کے علماء سے بحثیں کیں اوراسلامی معارف اوردینی حقائق کے بارے میں گراں بہا بیانات فرمائے (مامون بھی مذہبی بحثوںکے بارے میں کافی دلچسپی رکھتاتھا ) اسلامی معارف کے اصولوں کے بارے میں جس طرح امیرالمومنین کے بیانات بہت ہیں اوردیگر ائمہ کی نسبت بیش تر ہیں۔
حضرت امام رضاعلیہ السلام کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ تھی ،کہ آپ کے آباء واجدادکی بہت سی احادیث جو شیعوں کے پاس تھیں ،ان سب کوآپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ کے اشارہ اورتشخیص سے ان میں سے ،دشمنوں کے ناپاک ہاتھوں کی جعل اوروضع کی گئی احادیث کومشخص کرکے مسترد کیاگیا ۔
حضرت امام رضاعلیہ السلام نے ولی عہدی کے طور پر جوسفر مدینہ منورہ سے'' مرو''تک کیا،اس کے دوران ،خاص کر ایران میں عجیب جوش وخروش پیداہوا اورلوگ ہرجگہ سے جوق در جوق زیارت کے لئے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور شب وروزآپ کے شمع وجود کے گردپروانہ وار رہتے تھے اورآپ سے دینی معارف واحکام سیکھتے تھے ۔
مامون نے جب دیکھا کہ لوگ بے مثال اورحیرت انگیز طور پر حضرت امام رضاعلیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں تواس کو اپنی سیاست کے غلط ہونے کا احساس ہوا ،اسلئے اس نے اپنی غلط سیاست میں اصلاح کرنے کی غرض سے امام کوزہر دیکر شہید کیا اور اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں کے بارے میں خلفاء کی اسی پرانی سیاست پر گامزن رہا ۔
حضرت امام محمدتقی علیہ السلام
(نویں امام)
حضرت امام علی نقی علیہ السلام
(دسویںامام)
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
(گیارہویں امام)
ان تین ہستیوں کی زندگی کے حالات مشابہ تھے ۔امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون نے آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد بلایا اور پیارو محبت سے پیش آیا ،اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کی اورپورے احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھا ۔
یہ طرزعمل ،اگرچہ دوستانہ دکھائی دیتاتھا ،لیکن مامون نے حقیقت میں اس سیاست کے ذریعہ امام علیہ السلام پر ہرلحاظ سے شدید پابندی لگائی تھی ۔حضرت امام علی نقی وحضرت امام حسن عسکری علیہما السلام کا اپنی امامت کے دوران سامرامیں ۔جوان دنوںدارالخلافہ تھا۔سکونت کرنابذات خودایک قسم کی نظر بندی تھی۔
ان تین اماموں کی امامت کی مدت مجموعی طور پر٥٧سال ہے ،ان دنوں ایران ،عراق اورشام میں رہنے والے شیعوں کی تعداد لاکھوںتک پہنچ گئی تھی اور ان میں ہزاروں رجال حدیث بھی موجودتھے۔اسکے باوجودان تین ائمہ علیہم السلام سے منقول احادیث بہت کم ہیں اور ان کی عمریں بھی کم تھیں ۔نویں امام ٢٥سال کی عمر میں دسویں امام ٤٠سال کی عمر میں اور گیارہویں امام ٢٧سال کی عمر میں شہید کئے گئے ۔یہ سب نکات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ان کے زمانے میں دشمنوںکی طرف سے ان پر شدید پابندی تھی اور ان کے کام میں روڑے اٹکائے جا تے تھے، لہذا یہ ائمہ اپنی ذمہ داریوںکوآزادانہ طورپر انجام نہیں دے سکتے تھے ،پھر بھی دین کے اصول اورفروع کے بارے میں ان تین ائمہ سے بعض گراں بہا احادیث نقل ہوئی ہیں ۔
حضرت امام مہدی موعودعجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
(بارہویںامام)
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ میں خلافت کی انتظامیہ نے فیصلہ کیاتھا کہ ہر ممکن وسیلہ اورذریعہ سے حضرت کے جانشین کو نابود کریں ،تا کہ اس کے ذریعہ مسئلہ امامت اور اس کے نتیجہ میں مذہب تشیع کوختم کردیں ۔حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر دوسری پابندیوں کے علاوہ یہ بھی ایک پابندی تھی ۔
اس لحاظ سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی پیدائش مخفی رکھی گئی اورآپ( عج) کی چھ سال کی عمر تک آپ (عج) کے پدربزرگوارزندہ تھے ۔آپ( عج) کولوگوں کی نگاہوںسے پوشیدہ رکھا جاتا تھا اورشیعوں کے چندخاص افراد کے علاوہ آپ( عج) کو کوئی نہیں دیکھ سکتاتھا ۔
والد گرامی کی شہادت کے بعد حضرت (عج) نے،خدا کے حکم سے غیبت صغری اختیار کی،اوراپنے چارخاص نائبوں کے ذریعہ جو یکے بعد دیگرے آپ( عج) کے نائب مقرر ہوئے تھے ،شیعوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے اوران کی مشکلات کو حل فرماتے تھے ۔
اس کے بعدسے حضرت(عج)آج تک غیبت کبری میں ہیں ،جب آپ(عج)کوخدا کاحکم ہو گاتو اس وقت ظہور فرماکرزمین کوعدل وانصاف سے بھردیں گے جوظلم وستم سے پھرچکی ہوگی ۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مہدی موعود(عج) اورآپ(عج)کی غیبت وظہور کے بارے میں شیعہ وسنی راویوں نے بے شما احادیث نقل کی ہیں اوراسی طرح شیعوں کی بزرگ شخصیتوں کی ایک بڑی تعدادآپ(عج)کے والد گرامی کی زندگی میں آپ(عج)کی خدمت میں پہنچ کرآپ(عج) کے نورانی جمال کادیدار کرچکی ہے اورآپ(عج)کے والدگرامی سے امامت کی خوش خبری سن چکی ہے۔
اسکے علاوہ نبوت اورامامت کی بحث میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیںکہ دنیاہرگز خدااوراس دین کی حفاظت کرنے والے امام سے خالی نہیں رہے گی۔
ائمہ دین کی روش کااخلاقی نتیجہ
خدا کے انبیاء اورائمہ دین کے بارے میں جو کچھ تاریخ سے خلاصہ کے طور پرحاصل ہوتا ہے ،وہ یہ ہے کہ وہ حقیقت پسنداورحق کے پیروتھے اورعالم بشریت کوحقیقت پسندی اورحق کی پیروی کرنے کی دعوت دیتے تھے اوراس سلسلے میں ہر قسم کی جاں نثاری اورقربانی دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔
دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ انسان اورانسانی معاشرہ کی کما حقّہ تربیت کریں ۔وہ چاہتے تھے کہ لوگوں پر جاہلانہ یاخرافاتی افکارکی حکمرانی کے بجائے صحیح افکاروعقائد حکم فرما ہوں ،اور انسانیت کے پاک دامن کوحیوانی خصلتوں سے داغدار اورآلودہ نہ ہونے دیں درندوںکی طرح ایک دوسرے کو پھاڑنے اوراپنااپیٹ بھر نے کے بجائے انسانی عادات کو اپنا کر زندگی کے بازارمیں انسانیت کا سرمایہ لگاکرانسانیت کے نقد فائدے سے سعادت حاصل کریں۔یعنی وہ ایسے تھے جو اپنی سعادت نہیں چاہتے تھے مگر معاشرے کی سعادت اور عالم انسانیت کے لئے اس کے علاوہ کسی فریضہ کو تشخیص نہیں دیتے تھے ۔
انہوں نے اپنی بھلائی اورسعادت(کہ انسان اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتا ہے)ا س میں دیکھی تھی کہ سب کے خیرخواہ ہوں اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی ایسے ہی ہوں ،یعنی جوشخص جس چیز کو اپنے لئے پسند کرتا ہے ،اسے دوسرے کیلئے پسند کرے اورجس چیزکواپنے لئے پسندنہیں کرتاہے اسے دوسروںکے لئے بھی پسندنہ کرے ۔
اسی حقیقت بینی اورحق کی پیروی کے نتیجہ میں ان حضرات نے اس عام انسانی فریضہ کی اہمیت ''خیرخواہی''اوردیگر جزئی فرائض ،جو اس کے فروع ہیں،کاپتہ چلایا ہے اورجاں نثاری وفداکاری جیسے صفات کے مالک بن گئے ہیں اورانہوں نے راہ حق میں جان ومال کی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا اور بدخواہی پر مشتمل ہرصفت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔وہ اپنے مال وجان کے بارے میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے ۔خودپرستی اورکنجوسی سے متنفر تھے ،جھوٹ نہیں بولتے تھے ،کسی پر تہمت نہیں لگاتے تھے ،دوسروںکی عزت اورجان ومال پر تجاوز نہیں کرتے تھے ۔ان صفات کی تفصیلی وضاحت اورآثار کو اخلاق کے حصہ میں ہوناچاہئے۔
ائمہ معصومین علیہم السلام کے اجمالی حالات
پہلے امام
نام: امیرالمومنین حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام
پیدائش: ٢٣سال قبل ہجرت
خلافت: ٣٥ ہجری
شہادت: ٤٠ ہجری
مدت خلافت: تقریباًپانچ سال
مد ت عمر: ٦٣سال
دوسرے امام
نام: حسن علیہ السلام
مشہور لقب: مجتبی
کنیت: ابو محمد
والدگرامی: حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیہ السلام
پیدائش: ٣ ہجری
شہادت: ٥٠ ہجری ،معاویہ کے ایماء پر اپنی زوجہ کے ذریعہ
زہرسے شہید کئے گئے۔
مدت عمر: ٤٨سال
مدت امامت: دس سال
تیسرے امام
نام : حسین علیہ السلام
لقب: سیدالشہدائ
کنیت: ابو عبد اللہ
والدگرامی : حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیہ السلام
پیدائش: ٤ ہجری
شہادت: ٦١ ہجری ،یزیدبن معاویہ کے حکم سے شہیدکئے گئے۔
مدت عمر: ٥٧سال
مدت امامت: دس سال
چوتھے امام
نام: علی علیہ السلام
لقب: سجاداورزین العابدین
کنیت: ابومحمد
والدگرامی: حضرت امام حسین علیہ السلام
پیدائش: ٣٨ ہجری
شہادت: ٩٤ ہجری میں ہشام بن عبدالملک کے حکم سے
زہردیاگیا۔
مدت عمر: ٦٦سال
مدت امامت: ٣٥سال
پانچویں امام
نام : محمدعلیہ السلام
لقب: باقر
کنیت: ابوجعفر
والدگرامی: حضرت امام سجادعلیہ السلام
پیدائش: ٥٨ ہجری
شہادت: ١١٧ ہجری میں ابراہیم بن ولید کے حکم سے
زہردیاگیا۔
مدت عمر: ٥٩سال
مدت امامت: ٢٣سال
چھٹے امام
نام: جعفرعلیہ السلام
لقب: صادق
کنیت: ابوعبد اللہ
والدگرامی: حضرت امام محمدباقر علیہ السلام
پیدائش: ٨٠ ہجری
شہادت: ١٤٨ ہجری میں منصور عباسی کے حکم سے زہردیاگیا
مدت عمر: ٦٨سال
مدت امامت: ٣١سال
ساتویں امام
نام: موسی علیہ السلام
لقب: کاظم
کنیت: ابوالحسن
والدگرامی: حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام
پیدائش: ١٢٨ ہجری
شہادت: ١٨٢ ہجری
مدت عمر: ٥٤سال
مدت امامت: ٣٥سال
آٹھویںامام
نام: علی علیہ السلام
لقب: رضا
کنیت: ابوالحسن
والدگرامی: حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام
پیدائش: ١٤٨ ہجری
شہادت: ٢٠٣ ہجری میں مامون عباسی کے ہاتھوں زہرسے
شہید کئے گئے
مدت عمر: ٥٥سال
مدت امامت: ٢١سال
نویں امام
نام: محمدعلیہ السلام
لقب: تقی اورجواد
کنیت: ابو جعفر
والدگرامی: حضرت امام رضا علیہ السلام
پیدا ئش: ١٩٥ ہجری
شہادت: ٢٢٠ ہجری میں معتصم عباسی کے ایماپراپنی زوجہ کے
ہاتھوںزہرسے شہید کئے گئے
مدت عمر: ٢٥سال
مدت امامت: ١٧سال
دسویں امام
نام: علی علیہ السلام
لقب: ہادی ونقی
کنیت: ابوالحسن
والدگرامی: حضرت امام محمدتقی علیہ السلام
پیدائش: ٢١٤ ہجری
شہادت: ٢٥٤ ہجری
مدت عمر: ٤٠سال
مدت امامت: ٣٤سال
گیارہویں امام
نام: حسن علیہ السلام
لقب: عسکری
کنیت: ابومحمد
والدگرامی: حضرت امام علی نقی علیہ السلام
پیدائش: ٢٣٢ ہجری
شہادت: ٢٦٠ ہجری
مدت عمر: ٢٨سال
مدت امامت: ٧سال
بارہویں امام
نام: م ح م د علیہ السلام
لقب: ہادی اورمہدی
کنیت: ابوالقاسم
والدگرامی: حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
پیدائش: ٢٥٦ ہجری
آپ خداکے حکم سے نظروں سے غائب ہیں ،جس دن خدا چاہے گاظہورفرماکردنیاکو عدل وانصاف سے بھردیں گے۔
اخلاق واحکام کے چند سبق
١۔اخلاق کے چند سبق
٢۔احکام کے چند سبق
١۔اخلاق کے چند سبق
جیسا کہ معلوم ہوا،دین مقدس اسلام ایک ایسا عام اور لافانی نظام ہے،جسے خدائے متعال نے انسان کی دنیوی واخروی زندگی کے لئے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے ،تاکہ انسانی معاشرے میں نافذ ہوجائے،اورانسانیت کی کشتی کو جہالت وبدبختی کے بھنور سے نکا ل کر نجات کے ساحل پرلگا دے ۔
چونکہ دین،زندگی کا نظام ہے ،لہذاضروری ہے کہ زندگی سے مربوط چیزوں کے بارے میں انسان کے لئے ایک فریضہ کومعین کرے اور اس کے انجام کو انسان سے طلب کرے۔کلی طورپر ہماری زندگی تین امور سے مربوط ہے :
١۔خدائے متعال سے ،کہ ہم اسکی مخلوق ہیں ،اسکی نعمت کاحق ہرحق سے زیادہ ہے اوراس کی ذات اقدس کے بارے میں فرض شناسی ہر واجب سے زیادہ واجب ہے۔
٢۔زندگی کارابطہ خودہمارے ساتھ۔
٣۔اپنے ہم جنسوں سے رابطہ،ہم اپنے ہم جنسوںکے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تاکہ اپنے کاروکوشش کوان کے تعاون اورمددسے انجام دیں۔اس بناپر، ہم قاعدے کے مطابق کلی طور پرتین فرائض رکھتے ہیں :
الف:خداکے بارے میں فریضہ۔
ب:اپنے بارے میں فریضہ۔
ج:دوسروں کے بارے میں فریضہ۔
خدا کے بارے میں انسان کافریضہ
خدا کے بارے میں ہمارا فریضہ،اہم ترین فریضہ ہے۔اس کو انجام دینے میں ہمیں پاک دل اورخالص نیت سے کوشش کرنی چاہئے۔سب سے پہلے انسانی فریضہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچانے،کیونکہ خدائے متعال کا وجود ،ہر مخلوق کے وجود کاسر چشمہ ہے اور ہروجود وحقیقت کا خالق ہے۔اس کے مقدس وجودکی معرفت اوراس کا علم ہر حقیقت بیں نگاہ کے لئے روشنی ہے ۔اس حقیقت سے بے اعتنائی اوردوری ،ہرقسم کی جہالت ،بے بصیرتی اورفریضہ کے نہ جاننے کا سر چشمہ ہے۔جوشخص حق کی معرفت سے بے اعتنائی کرے اورنتیجہ میں اپنے ضمیر کے روشن چراغ کو بجھادے،تواس کے لئے حقیقی انسانی سعادت کوحاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ۔
چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ،جولوگ خداشناسی سے رو گردا نی کر تے ہیں اوراپنی زندگی میں اس حقیقت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ،وہ انسانی معنویات سے کلی طورپر دور ہیں اوران کی منطق چوپایوں اوردرندوں کی منطق ہے خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے:
( فعرض عن مّن تولّی عن ذکرنا ولم یرد الّا الحیوة الدنیا٭ذلک مبلغهم من العلم ) ...) (نجم٣٠٢٩)
''لہذاجو شخص بھی ہمارے ذکرسے منہ پھیرے اورزندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے،آپ بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں،یہی ان کے علم کی انتہا ہے ۔''
البتہ یہ یاددہانی ضروری ہے کہ،خداشناسی ،انسان کے لئے۔جوایک حقیقت بین اوراستدلالی فطرت والی مخلوق ہے۔اضطراری اورقہری ہے،کیونکہ وہ اپنے خداداد شعور سے خلقت کے جس شئے پر بھی نگاہ کرتا ہے ،خالق کائنات کے وجوداور اس کے علم وقدرت کے آثار کا مشا ہدہ کرتا ہے ۔اس بناپر خداشناسی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انسان نے خداشناسی کو اپنے لئے ایجادکیا ہے،بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس واضح حقیقت کو ،کہ جس پر پردہ نہیںڈالا جاسکتا ،بے اعتنا ئی کی نگاہ سے نہ دیکھے اوراپنے ضمیر کو،جواسے ہروقت خدا کی طرف دعوت دیتا ہے ،مثبت جواب دے اوراس معرفت کی تحقیق کر کے ہرقسم کے شک وشبہہ کواپنے دل سے نکال دے۔
خدا پرستی
خدا شناسی کے بعدہمارادوسرافریضہ خداپرستی ہے،کیونکہ حق کی معرفت کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ سعادت وخوشبختی۔جوہماراتنہا مقصدہے۔ایک ایسے پروگرام پرعمل کرنے اوراسے نافذ کرنے میں پوشیدہ ہے،جسے خدائے متعا ل نے ہماری زندگی کے لئے معین فرمایا ہے اور اسے اپنے انبیاء کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے ،پس خدائے متعال کے حکم کی اطاعت اور اسکی بندگی ایسافریضہ ہے کہ جس کے مقابلہ میں ہر فریضہ ناچیز اور حقیر ہے ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( وقضی ربّک الّا تعبدوا الّا ایّاه ) ۔..) (اسرائ٢٣)
''اور آپ کے پروردگارکا فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا...''
( الم اعهد الیکم یابنی آدم ان لّا تعبدواالشّیطن انّه لکم عدوّ مبین ٭وان اعبدونی هذا صراط مّستقیم ) (نسائ٥٩)
''اولاد آدم !کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرناکہ وہ تمہاراکھلا ہوا دشمن ہے ٠اور میری عبادت کرنا کہ یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے ''
اس بناپر، ہمارا فریضہ ہے کہ مقام بندگی اور اپنی ضرورت کو پہچانیں اور خدائے متعا ل کی لا محدود عظمت وکبریائی کو مد نظر رکھیں اور اس کو ہر جہت سے اپنے اوپر مسلط جان کر اس کے فرمان کی اطاعت کریں ۔ہم پر واجب ہے کہ خدائے متعال کے سواکسی اورکی پرستش نہ کریں اور پیغمبرگرامیصلىاللهعليهوآلهوسلم اور ائمہ ھدی ۔کہ خدائے متعال نے ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے ۔کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کریں۔خدائے متعال فرماتا ہے :
(...( اطیعوااللّه واطیعواالرّسول واولی الامر منکم ) ۔..)
(نسائ٥٩)
''...اللہ کی اطاعت کرو ،رسول اور صاحبان امر(ائمہ )کی اطاعت کرو''
البتہ،خدائے متعال اوراولیائے دین کی اطاعت کے اثر میں ،عملًا خداسے منسوب ہر چیز کا مکمل احترام کرناچاہئے ۔خدااوراولیائے دین کے نام کو ادب کے ساتھ لینا چاہئے۔ خداکی کتاب (قرآن مجید)،کعبہ شریف،مساجد اوراولیائے دین کی قبور کا احترام کرنا چاہئے ،چنانچہ خدائے متعال فرما تا ہے:
(...( ومن یعظِّم شعائر اللّه فانّها من تقوی ) (حج٣٢)
''جوبھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی .''
اپنے بارے میں انسان کافریضہ
انسان ،اپنی زندگی میں جو بھی روش اختیار کرے اور جس راستہ پر چلے،حقیقت میں وہ اپنے لئے سعادت و کامیابی کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتا ۔چونکہ سعادت کو پہچاننا،کسی اورچیز کی پہچاننے کے ضمن میں ہے ،یعنی جب تک ہم خود کو نہ پہچانیں گے اس وقت تک اپنی حقیقی ضرورتوں ۔کہ ان کو پورا کرنے میں ہماری سعادت ہے۔کو بھی نہیں پہچان سکیں گے ۔اس بناپر انسان کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ خود کو پہچان لے تاکہ اس کے سبب اپنی سعادت وخوشبختی کو سمجھے اور اپنے پاس موجود وسائل کے ذریعہ اپنی ضرورتوں کودور کرنے کی کوشش کرے اوراپنی گراںبہا عمر،جواسکا تنہا سرمایہ ہے،کومفت میں ضا ئع نہ ہونے دے ۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
''جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیاہے ''(۱)
امیرالمؤ منین حضرت علی فرماتے ہیں :
''جس نے اپنے آپ کوپہچان لیا،وہ معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچ گیا ''(۲)
انسان،اپنے آپ کوپہچاننے کے بعدمتوجہ ہوتا ہے کہ اس کاسب سے بڑافریضہ یہ ہے کہ وہ گوہرانسانیت کی قدر کرے ۔
اس گوہرتابناک کو ہواوہوس کے ذریعہ پامال نہ کرے ،اپنی ظاہری وباطنی صفائی کے لئے کوشش کرے تاکہ ایک شیرین ،لذت بخش اورابدی زندگی کو حاصل کرسکے ۔
امیرالمؤ منین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
''جوشخص اپنا احترام کرے گا ،اسکے سامنے نفسانی خواہشات حقیراورناچیز ہوں گی۔''(۳)
انسانی وجود دوچیزوں کامرکّب ہے :''روح اوربدن''انسان کا فریضہ ہے کہ ان دونوں ارکان کی صحت واستحکام کے لئے کوشش کرے اوراسلا م کے مقدس دین میں دونوں حصوں کے بارے میں بیان کئے گئے مفصل اور کافی احکام کے مطابق بدن اور روح کی صفائی کی کوشش کرے۔
بدن کی صفائی
دین مقدس اسلام نے کچھ قوانین و ضوابط کے ضمن میں ،جسمانی صفائی کی کافی تاکید کی ہے، جیسے :خون ،مردار ،بعض حیوانوں کا گوشت اورزہریلی غذائوں کو کھانے سے منع کی ہے ۔شراب نوشی ،نجس پانی پینے ،پرُخوری ،اور بدن کو ضرر پہنچانے کی نہی کی ہے اس کے علاوہ دوسرے احکامات ہیں کہ اس فصل میں ان سب کی تفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے ،خلاصہ کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اسلام نے انسان کو تمام نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے ۔
صفائی کاخیال
صفائی،حفظان صحت کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے،اسی لئے دین اسلام میں اس اصول کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔جواہمیت اسلام میں صفائی کو دی گئی ہے ،کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی ہے۔پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :
''النظافة من الایمان'' (۴)
''صفائی ایمان کاحصہ ہے''
اسکے علاوہ اسلام عام طورپر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے ، بالخصوص ہر ایک کے لئے صفائی کی نصیحت کرتا ہے ،جیسے :ہاتھ پائوں کے ناخن کاٹنا ،سراوربدن کے زائد بالوں کو صاف کرنا ،کھانا کھانے سے پہلے اوربعد میں ہاتھوں کو دھونا ،بالوںکو کنگی کرنا،کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ،دن میں کئی بارمسواک کرنا ،گھر کو جھاڑو کرنا،راستوں ، گھر کے دروازوں اور درختوں وغیرہ کے نیچے کوصاف ستھرا رکھنا۔
اسکے علاوہ اسلام نے بعض عبادتوں کا حکم دیا ہے کہ جن کا تعلق صفائی وپاکیزگی وغیرہ سے ہے ،جیسے: لباس اور بدن کو نجاستوں سے پاک کرنا،دن میں کئی مرتبہ نماز کے لئے وضو کرنااورنمازو روزہ کے لئے مختلف غسل کرنا۔
کُلّی اور مسواک
انسان منہ سے کھاناکھاتا ہے اورکھانا کھانے کی وجہ سے منہ آلودہ ہوتا ہے،دانتوں کے درمیان ،زبان پراورمنہ کی دوسری جگہوں پر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رہ جاتے ہیں،اس لئے منہ کے اندربدبو پیدا ہوجا تی ہے اور بعض اوقات کھانے کے ٹکڑوں میں کیمیائی عمل وردعمل اورخمیر ہونے کی وجہ سے زہریلے مواد وجود میں آتے ہیں اور کھانے کے ساتھ مل کر معدے میں جاتے ہیں۔
اسکے علاوہ ایساشخص لوگوں کے مجمع میں سانس لیکربدبو پھیلاتا ہے اور دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے ۔
اس لئے شرع مقدس اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیاہے کہ ہردن (خاص کرہروضوسے پہلے)اپنے دانتوں کو مسواک کریں اورصاف پانی سے کلّی کریں اوراپنے منہ کوآ لودگی سے پاک کریں۔
استنشا ق(ناک میں پانی ڈالنا)
سانس لینا،انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہے اور غالبا ًجو ہواانسان کے رہنے کی جگہ پر ہوتی ہے ،گردوغبار اور کثافت سے خالی نہیں ہوتی ،البتہ ایسی ہوامیں سانس لینا نظام تنفس کے لئے مضر ہے ۔اس ضررکو روکنے کے لئے خدائے مہربان نے ناک کے اندرکچھ ایسے بال اگائے ہیں جو گرد وغبار کوپھیپھڑوں تک پہنچنے نہیں دیتے ،اس کے باوجودکبھی گرد وغبارناک کے اندر جمع ہو جا تا ہے جس کی وجہ سے ناک کے بال اپنی ذمہ داری نبھانے سے قاصر رہتے ہیں ۔اسلئے دین اسلام میں حکم دیاگیاہے کہ مسلمان دن میں کئی باروضوسے پہلے ناک میں پانی ڈالیں اور اپنی ناک میں صاف پانی ڈال کراپنے تنفس سے مربوط حفظان صحت کی رعایت کریں ۔
____________________
١۔بحارالانوار،ج٦١،ص٩٩۔
۲۔غررالحکم،ج٢ص١٢٨٧ص٦٩٨۔
۳۔غررالحکم ،ج٢،ص٦٨١،ح١١٠٩۔
۴۔نہج الفصاحہ،ح٣١٦١،ص٦٣٦۔
تہذیب اخلاق
انسان،اپنے خداداد ضمیر سے پسندیدہ اخلاق کی قدرو قیمت کو سمجھتا ہے اور اسکی انفرادی واجتماعی اہمیت کو جان لیتاہے ۔لہذا انسانی معاشرے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جوپسندیدہ اخلاق کی تعر یف اور پسندیدہ اخلاق رکھنے والے شخص کااحترام نہ کرے ۔
جواہمیت انسان پسندیدہ اخلاق کو دیتاہے وہ محتاج تعارف وبیان نہیںہے اوراسلام میں اخلاق کے بارے میں جووسیع احکام بیان ہوئے ہیں وہ سب واضح ہیں ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( ونفس وماسوّٰ ها٭فَلهَمَهافجورَهاوتقوٰها٭قد افلح من زکّٰها٭وقد خاب من دسّٰهٰا ) ( شمس٧۔١٠)
''اورنفس کی قسم اور ا س خداکی قسم جسں نے اسے درست کیاہے ٠پھر بدی اور تقویٰ کی ہدایت دی ہے ٠بیشک وہ کامیاب ہوگیاجس نے نفس کوپاکیزہ بنالیا٠اوروہ نامراد ہوگیا جس نے اسے آلودہ کردیاہے ''
حصول علم
پسندیدہ معنوی صفات میں سے ایک علم ہے اورعالم کی جاہل پر فضیلت وبرتری اظہر من الشمس ہے ۔
جو چیز انسان کودوسرے حیوانات سے جدا کرتی ہے ،بیشک وہ عقل کی طاقت اور علم کا زیور ہے۔دوسرے حیوانات میں سے ہر ایک اپنی خاص بنا وٹ کے مطابق ناقابل تغیر فطرت رکھتاہے اور یکساں صورت میں اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کی زندگی میں ہرگزکسی قسم کی ترقی اور بلندی کی کوئی امید نہیں پائی جاتی .وہ اپنے اور دوسروں کے لئے کوئی نیا باب نہیں کھول سکتے ہیں یہ صرف انسان ہے جوعقل کی طاقت سے،ہرروز اپنے گزشتہ معلومات میں جدید معلومات کااضافہ کرتاہے اور طبیعت اورمادرای طبیعت کے قوانین کوکشف کرکے ہرزمانہ میں اپنی مادی اور معنوی زندگی کو تازگی اوررونق بخشتا ہے،اپنے ماضی کے ادوار پرنظرڈال کراپنے اوردوسروں کے مستقبل کی بنیاد ڈالتا ہے ۔
اسلام نے علم حاصل کرنے کے سلسلہ میں اس قدرتاکید کی ہے کہ پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
''علم حاصل کرناہرمسلمان پر واجب ہے ''(۱)
''علم حاصل کرو،اگرچہ چین میں بھی ہو''(۲)
''گہوارہ سے قبر تک علم حاصل کر نیکی کو شش کرو''(۳)
اسلام،خلقت کے اسرار کوجاننے اورآسمانوں،زمین ،انسان کی فطرت،تاریخ وملل اور اپنے اسلاف کے آثار(فلسفہ ،علوم ریاضی وطبیعی وغیرہ)کے بارے میں غور وخوض کرنے کی بہت تاکید کرتا ہے اور اسی طرح اخلاقی اورشرعی مسائل (اسلامی اخلاق و قوانین )اور صنائع کے اقسام ۔جو انسان کی زندگی کو منظّم کرتے ہیں۔کو سیکھنے کی اسلام بہت ترغیب دیتااور تاکید کرتا ہے ۔پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں علم کی اہمیت اس قدر ہے کہ جنگ بدر میں جب کفار کی ایک جماعت مسلمانوں کے ہاتھوں اسیرہوگئی، توآنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسیروں میں سے ہر فرد زیادہ ر قومات ادا کرکے آزاد ہوسکتاہے ،لیکن اسیروں میں جو افراد تعلیم یافتہ تھے وہ یہ رقومات ادا کرنے سے اس شرط پر متثنیٰ قرار دیئے گئے کہ ان میں سے ہر ایک دس جوان مسلمانوں کو لکھناپڑھنا سکھائے ۔
اسلام کی نظرمیں طالب علم کی اہمیت
ہر مقصد تک پہنچنے کے لئے سعی وکوشش کی اہمیت خوداس مقصدکی اہمیت کے برابر ہوتی ہے اور چونکہ ہرانسان اپنی خداداد فطرت سے عالم بشریت میں علم ودانش کو ہر چیز سے بالا تر جانتا ہے ،لہذا طالب علم کی قدرو قیمت بالا ترین قدرو قیمت ہوگی اس چیز کے پیش نظر کہ اسلام ایسادین ہے کہ جو فطرت کی بنیادوں پر مستحکم واستوار ہے لہذا ا بلاشبہہ طالب علم کی سب سے زیادہ قدروقیمت کا قائل ہے ۔پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:
''جو علم حاصل کرنے کی راہ میں ہو ،وہ خداکا محبوب ہے ''(۵)
ا س کے باوجود کہ جہاد،دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اور اگر پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم یا امام حکم جہاد دیدیں توعام مسلمانوں کا جنگ میں شریک ہونا ضروری ہوجاتا ہے ،لیکن جو لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس حکم سے مستثیٰ اور معاف ہیں ۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ہمیشہ علمی مراکزمیں تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہنا چاہئے ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( وما کان المؤمنون لینفروا کآفّةً فلولا نفر من کلّ فرقة منهم طائفة لیتفقَّهوا فی الدّین ولینذروا قو مهم اذا رجعواالیهم لعلّهم یحذرون ) (توبہ١٢٢)
''صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لئے نکل پڑیں تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لئے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اورپھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تواسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسطرح ڈرنے لگیں ۔''
معلم اورمربی کی اہمیت
علم اور طالب علم کے بارے میں مذکورہ بیان سے اسلام میں معلم کی بھی اہمیت واضح ہوجا تی ہے ۔پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
''من تعلّمت منه حر فا صرت له عبدا'' (۶)
''جومجھے ایک کلمہ تعلیم دیدے میں خود کواس کا بندہ قراردوں گا''
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
''لوگوں کے تین گروہ ہیں :پہلا:عالم ربانی دوسرا:جواپنی اوردوسروں کی نجات کے لئے علم حاصل کرتا ہے ۔تیسرا:وہ لوگ جو عقل ودانش سے عاری ہوتے ہیں ان لوگوں کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو جانوروں کے سروصورت پربیٹھتی ہے اورہواکے چلنے پر ادھر ادھر اڑتی ہے یاجہاں سے بھی بدبو آتی ہے اسکی طرف دوڑتی ہے'' ۔
معلم اور شاگرد کا فریضہ
قرآن مجید،علم ودانش کو انسان کی حقیقی زندگی جانتا ہے ،کیونکہ اگر علم نہ ہوتاتوانسان اورجمادات اورمردوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔
اس بناپر،طالب علم کو چاہئے کہ اپنے معلم کو زندگی کا مرکز تصور کرے تاکہ تدریجاًاپنی حقیقی زندگی کواس سے حاصل کرسکے ،اس لحاظ سے اسے یہ تصورکرناچاہئے کہ اس کے تو سط سے اسے زندگی ملی ہے اس لئے اس کی عزت وتعظیم میں کوتاہی نہ کرے اوراگر تعلیم وتربیت کے سلسلہ میں اس کی طرف سے اگر سختی بھی دکھائی دے تو اس کی زندگی اورموت کے بعد اس کے احترام میں کوتاہی نہ کرے ۔
اسی طرح معلّم کوبھی اپنے آپ کواپنے شاگرد کی زندگی کا ذمہ دار سمجھنا چاہئے اورجب تک اسے ایک زندہ انسان اور فخرومباہات کے درجہ تک نہ پہنچا دے اس وقت تھکن محسوس نہ کرے اورآرام سے نہ بیٹھے۔
اگرکبھی اس کاشاگرد تعلیم وتربیت حاصل کرنے میں کوتاہی کرے تواستاد کاحوصلہ پست نہیں ہونا چاہئے ،اگر وہ تعلیم وتربیت میں ترقی کا مظاہرہ کرے تواس کی ہمت افزائی کرنی چاہئے،اگرلاپروائی کرے تواس کی حوصلہ افزائی کر کے اس میں شوق پیدا کرنا چاہئے اور شاگرد کے جذ بات کوہرگز اپنے طرزعمل سے مجروح نہ کرے ۔
ماں باپ کے بارے میں انسان کا فریضہ
ماں با پ اپنے فرزندکی پیدائش کا ذریعہ اوراس کے ابتدائی مربی ہیں اس سبب سے دین مقدس اسلام میں سب سے اہم نصیحت وتاکید ماں باپ کی اطاعت اوراحترام کے بارے میں کی گئی ہے ،یہاں تک کہ خدائے متعال توحید کے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے :
( وقضی ربُّک اَلّا تعبدواالّا ایّاه وبالوالدین احسٰناً ) ...)
(اسرائ٢٣)
''اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنااورماں باپ کے ساتھ اچھا برتائو کرنا ...''
جن روایتوں میں گناہان کبیرہ کو گنوایا گیا ہے ان میں شرک کے بعدوالدین کے ساتھ برے برتائوکو گناہ کبیرہ شمار کیاگیا ہے .خدائے متعال مذکورہ آیہ شریفہ کے ضمن میں بھی فرماتا ہے :
(...( اِمّا یبَلغنَّ عندک الکبر احدهما اوکلاهمافلا تُقل لَّهمااُفٍّ ولا تنهرهما و قل لهما قولاً کریماً٭واخفِض لهما جناح الذُّلّ من الَّرحمة ) ...) (اسرائ٢٤٢٣)
''...اور اگرتمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوںبوڑھے ہوجائیں توخبرداران سے اف بھی نہ کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں اوران سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا ، اور ان کے لئے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکادینا۔''
چہ خوش گفت زالی بہ فرزندخویش
چو دیدش پلنگ افکن وپیل تن
گر از عہد خردیت یاد آمدی
کہ بیچارہ بودی درآغو ش من
نہ کردی در این روز بر من جفا
کہ تو شیر مردی و من پیر زن
''کیاخوب کہا ہے ایک بوڑھیا نے اپنے بیٹے سے جب اس کو ایک طاقتورشیر اورہاتھی کے ماننددیکھااگرتجھے وہ اپنابچپن یاد آتاجب کہ تم میری آغوش میں ایک بیچارہ طفل تھے؟توآج تم مجھ پریہ ظلم نہ کرتے کہ تم ایک شیرمرد بن چکے ہو اورمیں ایک بوڑھی عورت ہوں۔''
دین مقدس اسلام میں ،ماں باپ کی اطاعت ،واجب کے ترک ہونے یاحرام میں مرتکب ہونے کے علاوہ، واجب ہے،اورتجربہ سے ثابت ہواہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو رنج وتکلیف پہنچائی ہے،وہ اپنی زندگی میں خوشبخت اورکامیاب وکامران نہیں ہوئے ہیں ۔
بزر گوں کا احترام
بوڑھوں کا احترام بھی لازم ہے ۔چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :
''بوڑھوں کااحترام اور تعظیم کرنا خدا کی تعظیم اورا حترام کرناہے ''(۷)
اپنے رشتہ داروںکے بارے میں انسان کافریضہ
انسان کے ماں باپ کے ذریعہ جورشتہ دارنسبی رابطہ رکھتے ہیں ،وہ طبیعی خاندان کوتشکیل دینے کا سبب بنتے ہیں اورخونی رشتہ اورانسانی خلیوں کے اشتراک کی وجہ سے انسان کو خاندان کاجزوقرار دیتے ہیں ۔اس طبیعی اتحاد اورارتباط کی وجہ سے اسلام نے اپنے پیروئوں کوصلہء رحم کاحکم دیا ہے اورقرآن مجید اور ائمہ دین کی روایتوں میں اس سلسلہ میں بہت ہی تاکید کی گئی ہے ۔خدائے متعال فرماتا ہے:
(...( وَاَّتقوااللّٰه الّذی تسا ئلَون به وَالارحام ان اللّه کان علیکم رقیباً ) (نسائ١)
''اور اس خداسے بھی ڈروجس کے ذریعہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواورقرا بت داروںکی بے تعلقی سے بھی ۔اللہ سب کے اعمال کا نگراں ہے ۔''
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
''میں اپنی امت کو صلہء رحم کی نصیحت کرتا ہوں اوراگررشتہ داروں کے درمیان ایک سال کی دوری کافاصلہ ہو تو بھی اپنے رشتہ کے پیوندکونہ توڑیں ۔''(۸)
ہمسایوں کے بارے میں انسان کافریضہ
چونکہ ہمسایہ زندگی بسر کر نے کی جگہ پر ایک دوسرے سے نزدیک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے زیادہ رابطہ رکھتے ہیں اورگویا ایک بڑے خاندان کے حکم میں ہوتے ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک کا اچھا اور برا طرزعمل ہمسایوں پر دوسروں کی نسبت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ۔
جورات کو اپنے گھر میں صبح ہونے تک شور و غل مچا تاہے ،وہ شہر کے آخر میں رہنے والوں کوتکلیف نہیں پہنچاتا ہے ،لیکن اپنے ہمسایہ کے آرام وآسائش میں خلل ڈالتا ہے ۔
جو مالدار اپنے خوب صورت محل میں عیش وعشرت میں زندگی گزار رہا ہے،دور رہنے والے مفلسوں کی نگاہوں سے دور ہے ،لیکن ہر لمحہ اپنے ایک تنگ دست اور غریب ہمسایہ کی جھونپڑی میں اُگے ہوئے ایک پھول کے پودے کو آگ لگا تا ہے ،تو یقینا ایک دن ایسا آئے گا جب وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے گا ۔اس لحاظ سے دین مقدس اسلام میں ہمسایہ کے حالات کی رعایت کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے ۔پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
''جبرئیل امین نے ہمسایہ کے بارے میں اس قدرمجھے نصیحت کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ خدائے متعال ہمسایہ کو وارثوں میں قرار دے گا ''(۹)
نیزفرمایا:
''جوشخص اپنے ہمسایہ کو تکلیف پہنچائے گا ،اس تک بہشت کی خوشبونہیں پہنچے گی ۔جو اپنے ہمسایوں کے حق کی رعایت نہیں کرے گا ،وہ ہم میں سے نہیں ہے،اور جو سیر ہوگااور وہ جانتا ہو اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور اسے کچھ نہ دے تو وہ مسلمان نہیںہے ۔''(۱۰)
ماتحتوں اور بیچاروں کے بارے میں انسان کا فریضہ
بیشک معاشرے کی تشکیل لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہوتی ہے اور ایک معاشرے کے افراد کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ محتاجوں اور بے چاروں کی دستگیری کریں اور جو لوگ اپنی زندگی کی ضروریات کو پوراکرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ،کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کر کے ان کی مشکلات کو حل کرے ۔
آج تو یہ مسئلہ واضح ہوچکا ہے کہ مالداروں کے مفلس و نادار ا فراد کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ایسا بڑا خطرہ لاحق ہے کہ ،جو معاشرے کو نابود کر سکتا ہے اورسب سے پہلے مالدار ہی اس خطرے کے شکار ہوں گے۔
اسلام نے اس خطرہ کے پیش نظرچودہ سوسال پہلے ہی حکم دیا ہے ،کہ مالداروں کو اپنی آمدنی کے ایک حصہ کو ہر سال کمزوروں اور حاجتمندوں میں تقسیم کرنا چاہئے اور اگراس سے ان کی ضرورت پوری نہ ہو سکے تو مستحب ہے کہ غریبوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے جتنا ممکن ہوسکے راہ خدا میں انفاق کریں ۔
خدائے متعال فرماتا ہے :
( لن تنالواالبرّ حتّٰی تنفقوا مِمّاتُحِبّون ) ...) (آل عمران ٩٢)
''تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو''
لوگوں کی خدمت و مدد کے بارے میں نقل کی گئی حدیثیں بے شمار ہیں۔پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
''خیرالنّاس انفعهم للنّاس'' (۱۱)
''لوگوں میں سب سے بہتروہ ہے جوسب سے زیادہ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو۔''
نیز فرماتے ہیں :
''قیامت کے دن خداکے نزدیک اس شخص کا مقام سب سے بلند ہو گا جوخدا کے بندوں کی حاجت روائی کی راہ میں سب سے زیادہ اقدام کرے۔''(۱۲)
در بلا یار باش یاران را
تا کند فضل ایزدت یاری
بہ ہمہ حال بدروی روزی
تخم نیکی کہ این زمان کاری
معاشرے کے بارے میں انسان کا فریضہ
چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد سے کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کے کام وکوشش سے استفادہ کرتے ہیں اوراپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ۔ان افراد سے تشکیل پانے والا معاشرہ ایک بڑے انسان کے مانند ہے اور تمام افراد اس بڑے انسان کے اعضاء کے مانند ہیں ۔
انسان کے بدن کاہرعضو، اپنے مخصوص کام کو انجام دیتا ہے اور اپنے کام کے نفع کے علاوہ دوسرے اعضاء کے منافع سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے ،یعنی اپنی سر گرمی کی حالت میں اپنے نفع کو دوسرے اعضاء کے منا فع کے ضمن میں حاصل کرتا ہے اوردوسروں کی زندگی کے سائے میں اپنی زندگی کو جاری رکھتا ہے ۔اگر سارے اعضاء خود غرض ہوتے اور دوسروں کے کام نہ آتے،مثلا جہاںپر ہاتھ پائوںاپنے کام میں مشغول ہیں ،آنکھ اپنی نگاہ سے ان کاتعاون نہ کرتی یامنہ غذاکو چبانے اوراس سے لذت حاصل کرنے پر اکتفا کرتا اور معدہ کی ضرورت کوپورا نہ کرتا یعنی کھانے کو نہ نگلتا توانسان بلا فاصلہ مر جاتا اورنتیجہ کے طور پر خود غرض وانحصار طلب اعضاء بھی مر جاتے۔
معاشرہ کے بارے میں معاشرے کے افراد کا فریضہ بھی ایک انسان کے بدن کے اعضاء کے مانند ہے ۔یعنی انسان کواپنا منافع معاشرے کے منافع کے ضمن میں حاصل کرنا چاہئے اور اپنے کام وکوشش سے معاشرے کو فائدہ پہنچانے کا خیال ہونا چاہئے تاکہ اپنی محنتوں سے بہرہ مند ہو سکے اور سبھی کو فائدہ پہنچائے تاکہ خود بھی بہرہ مند ہوسکے ۔تمام لوگوںکے حقوق سے دفاع کرے تاکہ خود اسکے حقوق نابودنہ ہوں ۔یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم اپنی خدادادفطرت سے سمجھتے ہیں اوردین مقدس اسلام بھی ۔جوفطرت وخلقت پر استوارہے۔اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں رکھتا۔
پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
''مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اوراجنبیوں کے مقابلہ میں ایک دست،ایک دل اوریک جہت ہیں ''(۱۳)
مزیدفرماتے ہیں :
''المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه'' (۱۴)
''مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اورزبان سے دوسرے مسلمان امان میں رہیں ''
مزیدفرماتے ہیں:
''من اصبح ولم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم'' (۱۵)
'' جو مسلمانوں کے مسائل کواہمیت نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔''
اسی وجہ سے،پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک میں لشکر اسلام کو لے کرروم کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے تواس وقت تین افراد نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔اسلامی لشکر کے جنگ سے واپس آنے پرجب یہ تینوں آدمی ان کے استقبال کےلئے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا،توآنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنے رخ کو موڑ لیااور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اوراسی طرح مسلمانوں نے بھی ان سے اپنا منھ موڑلیا،نتیجہ میں مدینہ منورہ میں کسی نے حتی ان کی عورتوںنے بھی ان سے بات نہیں کی انہوں نے بے بس ہوکرمدینہ کے پہاڑوں میں پناہ لی اور توبہ واستغفار کیا۔چند دنوں کے بعد خدائے متعال نے ان کی توبہ قبول کی پھروہ شہرکے اندرآگئے ۔
____________________
١۔اصول کافی ،ج١،ص٣٠۔
٢۔نہج الفصاحہ،ح٣٢٤،ص٦٣۔
۴۔نہج الفصاحہ،ح٣٢٧،ص٦٤۔
۵۔بحارالانوار،(ج١ ص١٧٨،ح٦٠)
۶۔عوالی اللئانی ،ج١،ص٢٩٢،ح١٩٣۔
۷۔بحارالانوار،ج٧٥،ص١٣٦ح٢۔
۸۔اصول کافی .ج٢،ص١٥١۔
۹۔مستدرک الوسائل ،ج٨،ص٤٢٧۔
۱۰۔سفینتہ البحار،ج١،ص١٩٠۔
۱۱۔نہج الفصاحہ،ح١٥٠٠،ص٣١٥۔
۱۲۔کنزالعمال ،ج٦ ،ص٥٩٥۔
۱۳۔ نہج الفصاحہ ، ص ٦٢٥، ح ٣٠٨١ و ٣٠٨٢۔
۱۴۔بحارالانوارج٧٧ص٥٣۔
۱۵۔ اصول کافی، ج ٢، ص ١٦٣۔
عدالت
قرآن مجیداورائمہ دین کی روایتوں کے مطابق عدالت کی دوقسمیں ہیں:انفرادی عدالت اوراجتماعی عدالت ۔عدالت کی یہ دونوں قسمیں دین مبین اسلام کی نظر میں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔
انفرادی عدالت
انفرادی عدالت سے مرادوہ عدالت ہے کہ انسان جھوٹ ،غیبت اوردوسرے گناہان کبیرہ سے پرہیز کر ے اور دوسرے گناہوں کوباربار انجام نہ دے .جس میں یہ صفت ہو ،اسے عادل کہتے ہیں اوراسلام کے قوانین کے مطابق ایساشخص جج ،حاکم ،تقلید ،اوردیگر اجتماعی ذمہ داریوں کوسنبھال سکتا ہے ۔لیکن جس میں یہ دینی صفات موجودنہ ہوں وہ ان اختیارات سے بہرہ مندنہیں ہوسکتاہے۔
اجتماعی عدالت
''اجتماعی عدالت''سے مرادوہ عدالت ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق کے بارے میں افراط وتفریط نہ کرے اورسب کو قانون الہٰی کے مقابلہ میں مساوی قراردے اور اجتماعی عدالت کو نافذ کرنے میں دینی مقررات کے حق سے تجاوزنہ کرے،جذبات میں نہ آئے اورسیدھے راستہ سے منحرف نہ ہو ۔خدائے متعال فرماتاہے:
( انّ اللّه یامربالعدل ) ...) (نحل٩٠)
''بیشک اللہ عدل کاحکم یتا ہے ...''
بیشمارآیتوں اور روایتوں میں گفتاروکردارمیں عدالت کے بارے میں حکم ہواہے اورخدائے متعال نے اپنے کلام پاک میں چندمواقع پر ظالموں پر صراحتاً لعنت بھیجی ہے ۔
علم اخلاق میں ''عدالت'' سے مرادملکات وصفات نفسانی میں میانہ روی ہے اور یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے جوانفرادی واجتماعی عدالت کی رعایت کرتا ہو۔
سچائی
لوگوں کے درمیان آپس میں رابطہ،جوانسان کی اجتماعی بنیاد ہے، ''گفتگو''سے برقرارہوتی ہے ۔اس بنا پرسچ بات جو انسان کیلئے پو شیدہ حقیقت کو ظاہر کرتی ہے ،اجتماع کے ضروری ارکان میں سے ایک ہے ،اوراہم فائدے۔جن سے اجتماع ہرگز بے نیاز نہیںہے ۔سچ بات سے حاصل ہوتے ہیں ۔سچائی کے فوائد کومند رجہ ذیل چندجملوں میں بیان کیاجاسکتا ہے :
١۔سچ بولنے والا،اپنے ہم جنسوں کے لئے قابل اعتمادہوتا ہے اور ان کواس کی ہربات کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہں ہوتی۔
٢۔سچ بولنے والا،اپنے ضمیر کے مقا بلہ میں سربلنداورجھوٹ کے رنج سے آسودہ ہوتا ہے ۔
٣۔سچ بولنے والا،اپنے عہدوپیمان کی وفاکرتا ہے اورجوامانت اسکے حوالہ کی جاتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا ہے ،کیونکہ رفتار میں سچائی،گفتارکی سچائی سے جدانہیں ہے ۔
٤۔سچ بولنے سے،اکثر اختلافات اورلڑائی جھگڑے ختم ہوجا تے ہیں،کیونکہ اکثر اختلافات اورجھگڑے اس لئے وجودمیں آتے ہیں کہ ایک طرف یا دونوں طرف کے لوگ حق و حقیقت سے منکرہوتے ہیں ۔
٥۔سچ بولنے سے ،اخلاقی عیوب اور قانون کی خلاف ورزی کا ایک بڑاحصہ خودبخودختم ہوجا تا ہے ،کیونکہ اکثر لوگ اسی قسم کے کردارکو چھپانے کیلئے جھوٹ بولتے ہیں امیرالمئومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
حقیقی مسلمان وہ ہے جو سچ بولنے کو۔ خواہ اس کے نقصان میں ہو ۔جھوٹ بولنے پر ترجیح دیتا ہے چاہے وہ اس کے لئے مفید ہی کیوں نہ ہواوراس طر ح وہ اندرونی سکون حاصل کرتا ہے۔(۱)
جھو ٹ
''جھوٹ''اسلام میں گناہ کبیرہ ہے،جس کے لئے خدائے متعال کے کلام میں یقینی عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے۔
جھوٹ، صرف شرع میں ہی گناہ اور بر ا عمل نہیں ہے بلکہ عقل کی رو سے بھی اس کی برائی واضح ہے ۔یہ ناپسندیدہ عمل ،معاشرے میں پھیلنے سے،تھوڑی ہی مدت میں لوگوں کے اجتماعی رابطہ یعنی اعتماد کو ختم کر دیتا ہے ،اوراس قسم کے رابطہ کے ختم ہونے سے ،لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا لہذا ،انفرادی طورپرزندگی گزارتے ہیں ،اگر چہ بظاہر اجتماعی صورت دکھائی دیتی ہے ۔
جھوٹ کے نقصانات
سچ بولنے کے بارے میں مذکورہ بیان سے جھوٹ بولنے کے نقصانات بھی واضح ہو جاتے ہیں۔جھوٹ بولنے والا انسانی معاشرے کا نابکاردشمن ہوتا ہے اوراپنے جھوٹ سے،جو ایک بڑا جرم ہے ،معاشرے کوخراب کرڈالتا ہے ،کیونکہ جھوٹ،نشہ آورچیز کے مانند ہے جومعاشرے کی عقل وشعورکی طاقت کونابود کرکے حقائق پر پردہ پوشی کرتا ہے یاشراب کے مانندہے جولوگوں کو مست کرکے عقل کی طاقت کو برے اوربھلے میں تمیز کرنے سے بیکار بنادیتا ہے ۔اسی لئے اسلام نے جھوٹ کوگناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے اور جھوٹ بولنے والے کے لئے کسی قسم کی دینی شخصیت کاقائل نہیں ہے۔
پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
''تین طائفے منافق ہیں ،اگرچہ وہ نمازبھی پڑھیں اورروزہ بھی رکھیں :
جھوٹ بولنے والا،اپنے وعدہ پر وفانہ کر نے والااورامانت میں خیانت کرنے والا ہے''۔(۲)
امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:
''انسان جب ایمان کی لذت کوچکھ لیتا ہے ، تو جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اگر چہ مذاق میں بھی ہو۔''(۳)
غیبت وتہمت
دوسروں کی''بدگوئی''کرنا اوران کی سرزنش کرنا،اگرسچ ہوتو''غیبت''ہے اور اگرجھوٹ ہوتو''تہمت''ہے کبھی اسے''بہتان'' بھی کہا جاتا ہے ۔
البتہ پروردگار عالم نے انسان کو(پیغمبروںاورائمہ اطہار کے علاوہ)معصوم خلق نہیں کیاہے اورہرشخص خود میں موجود نقائص کی وجہ سے خطاو لغزش سے محفوظ نہیں ہے اور عام لوگ اس پردہ کے پیچھے زندگی کرتے ہیں جسے اللہ نے اپنی حکمت سے ان کے اعمال پر کھینچا ہے ۔چنانچہ اگر ایک لمحہ کے لئے اس الہیٰ پردے کوان کے نقائص اور عیوب سے ہٹا د یا جائے تو سب ایک دوسرے سے متنفرہو کربھاگ جائیں گے ،اور ان کے معاشرے کی عمارت زمین بوس ہوکرویران ہو جائیگی ۔اس لئے خدائے متعال نے غیبت کوحرام قراردیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے امان میں رہیں ۔اور ان کی زندگی کاظاہری ماحول آراستہ ہوجائے تاکہ یہی ظاہری زیبائی تدریجا ًباطنی برائی کی اصلاح کرے۔
خدائے متعال فرماتا ہے :
(...( ولایغتب بعضکم بعضًااٰیحبّ احدُکم ان یا کلَ لحم اخیه میتاً ) ...) (حجرات١٢)
''...ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو کہ کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گاکہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟..''
''تہمت''کا گناہ اور اس کی برائی غیبت سے زیادہ شدید ہے اوراس کی برائی عقل کی رو سے واضح ہے ۔خدائے متعال نے اپنے کلام پاک میں اس کی برائی اورناجائز ہونے کو مسلم جاناہے اوربلا چون وچراذکر فرماتاہے:
( انّمایفتری الکذب الَّذین لایؤمنون ) ...) (نحل١٠٥)
''بیشک جوایمان نہیںرکھتے ہیں وہ افتراکہتے ہیں ...''
لوگوں کی عزت پر تجاوز
اسلام میں عصمت دری ،گناہان کبیرہ میں سے ہے اورمواقع کے فرق کے مطابق اس جرم کے لئے سخت سزائیں ،جیسے کوڑے،سنگسار اورقتل وضع ہوئی ہیں۔
اس برے عمل کی راہ کا کھلاہونا ،اگرچہ طرفین کی رضامندی سے ہی ہو نسلوں کو۔جسے اسلام نے زیادہ اہمیت دی ہے ،متزلزل کرکے رکھدیتا ہے اور وراثت وغیرہ کے احکام کومعطل کردیتاہے اورآخر کارماں باپ اور فرزند کے پیار کو بے اثر کرکے رکھدیتا ہے اورمعاشرے کے حقیقی ضامن زادو ولدکی فطری دلچسپی کونابود کردیتاہے۔
رشوت
کسی ایسے حکم یا کام کے انجام دینے کے لئے پیسے یا کوئی تحفہ لینا ،جبکہ وہ کام پیسے یاتحفہ لینے والے کافریضہ ہو ، تو اس کو ''رشوت ''کہتے ہیں ۔
اسلام میں '' رشوت ''گناہ کبیرہ ہے اوراس کامرتکب ہونے والا،اجتماعی اوردینی فوائد(عدالت)سے محروم اورعذاب الہیٰ کامستحق ہوتاہے ۔کتاب وسنت اسکے گواہ ہیں ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے اوران کے درمیان واسطہ بننے والے، پر لعنت کی ہے ۔(۴)
چھٹے امام حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
'' کسی کی حاجت پورا کرکے رشوت لینا خداسے کفرکے برابر ہے ''(۵)
البتہ یہ سب سرزنش اورمذمت اس رشوت کے بارے میں ہے جو حق بجانب حکم اور عادلانہ عمل کے بارے میں لی جائے اور جو رشوت غیر حق بجانب حکم اورظالمانہ عمل کے لئے لی جائے ،اس کاگناہ بہت بڑا اوراس کی سزاشدیدتر ہے۔
حسن معاشرت
انسان جو سماج میں زندگی بسر کرتا ہے ، اس کے لئے لوگوںکے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ۔بیشک یہ مل جل کر رہنا اس لئے ہے تاکہ انسان اپنی انسان اپنی اجتماعی زندگی کاتحفظ کرسکے اور روزبروزاپنی مادی ومعنوی ترقی میں اضافہ کرے اورزندگی کی مشکلات کوبہتروآسان ترصورت میں حل کرے۔
لہذا،لوگوںسے ایسا برتائو کرناچاہئے جومحبوبیت کاسبب بنے اور دن بدن انسان کے اجتماعی وزن کو بڑھاوادے اوراس کے دوستوں میں اضافہ ہو ،کیونکہ اگرلوگ کسی سے مل کر سنگینی یاتلخی کا احساس کریں گے توان کے دلوں میں نفرت اورتنگی پیدا ہوجائے گی اورآخر کارایک ایسادن آئے گا جب سب لوگ اس سے دوری اختیار کریں گے اورایسا شخص معاشرے میں منفورومبغوض ہو جائے گا اور اس کو سماج میں ہونے کے باوجود تنہائی کی حالت میں اوراپنے وطن میں ہوتے ہوئے بھی غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنا پڑے گی اوریہ حالت انسان کی بدبختی کا تلخ وتاریک ترین نمونہ ہے ۔
اس لئے دین مقدس اسلام نے اپنے پیروئوں کے لئے حسن معاشرت کی نصیحت وتاکید کی ہے اور اس کے بارے میں بہترین آداب ورسوم بیان فرمائے ہیں۔منجملہ حکم دیاہے کہ مسلمانوں کوملاقات کے وقت ایک دوسرے کوسلام کرناچاہئے اور فضیلت اس کے لئے ہے جو سلام کرنے میں سبقت حاصل کرے۔
پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ،سلام کرنے میں پہل کرتے تھے حتی عورتوںاور بچوں کو بھی سلام کرتے تھے ۔اگرکوئی شخص آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کوسلام کرتاتوآپصلىاللهعليهوآلهوسلم اسکا بہترین جواب دیتے تھے۔خدائے متعال فرماتا ہے:
( واذاحیّیِتم بتحیة فحّیواباحسن منهااوردُّوها ) ...)
(نسائ٨٦)
''جب تم لوگوں کوسلام کیاجائے،تو تم اس سے بہتر یاویساہی جواب دو''
مزید حکم دیاہے کہ انسان لوگوں سے ملتے وقت تواضع اورانکساری سے پیش آئے اور ہرایک کا اسکی اجتماعی حیثیت کے مطا بق احترام کرے۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( وعباد الرَّحمن الّذین یمشون علی الارض هوناً ) ...)
(فرقان٦٣)
''اور اللہ کے بندے وہی ہیں جوزمین پرآہستہ فروتنی اورانکساری سے چلتے ہیں ۔''
قابل ذکرنکتہ یہ ہے کہ تواضع اورانکساری کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انسان خود کو لوگوں کے سامنے ذلیل وخوار کرے اوراپنی انسانیت کو نقصان پہنچائے ،بلکہ مقصدیہ ہے کہ اپنی قدرومنز لت اورفخرومباہات کو لوگوں کے سامنے ظاہرنہ کرے اوردوسرے عظیم فخرومباہات کو خود سے مخصوص نہ کرے اورلوگوں کو حقیروناچیز نہ سمجھے ۔اسی طرح لوگوں کے احترام کا معنی یہ ہیں کہ لوگوں کا اس حدتک احترام کرے کہ چاپلوسی نہ ہو بلکہ ہرایک کا اس کی دینی واجتماعی قدرومنزلت کی حد میں احترام کرے،بزرگوں کاان کی بزرگی کے مطابق احترام کرے اوردوسروں کا بھی ان کی انسانیت کے مطابق احترام کرے ۔
نیز احترام واکرام کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اگرکسی سے کوئی ناشائستہ کام سرزدہوتے دیکھے توآنکھیں بند کرکے گزرجائے یاایک ایسی محفل میں جہاں پراہل محفل انسانی شرافت کے خلاف کام انجام دیتے ہوں یاکوئی خلاف شرع عمل انجام دیتے ہوں تو رسوائی سے ڈرکران کے ساتھ ہم رنگ و جماعت ہوجائے ۔لوگوں کا احترام حقیقت میں انسانی شرافت اوران کی دینی قدروں کا احترام ہے نہ کہ ان کے جسم اوراعضاء کا احترام ۔اگر کوئی شخص اپنی انسانی شرافت اوردینی ترجیحات کونابودکردے تو کوئی دلیل نہیں بنتی کہ اس کااحترام کیا جائے ۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
دوسروں کی اطاعت کے ذریعہ خدا کی معصیت انجام نہیں دیناچاہئے ۔(۶)
____________________
١۔نہج البلاغہ صالح ، کلمات قصار نمبر ٤٥٨ دٹھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ۔
۲۔میزان الحکمہ،ج١٠،ص١٥٤۔
۳۔اصول کافی ،ج٢،ص٣٤٠ ،ح١١۔
۴۔سفینةالبحائج١،ص٥٢٣۔
۵۔سفینةالبحائج١،ص٥٢٣۔
۶۔وسائل الشیعہ ،ج١١،ص٤٢٢۔
نیکوں کی مصاحبت
اس کے باوجود کہ انسان بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے ، مگر وہ زندگی کے تقاضے کے مطابق مجبورہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ دوسروں کی نسبت زیادہ مل جل کر رہے ،یہ وہ لوگ ہیں جو''دوست'' کے نام مشہور ہیں ۔
البتہ اس دوستی کاسبب اخلاق،روش، اورپیشہ وغیرہ میں ایک قسم کی یکسانیت ہے جودویاچند افراد کے درمیان پائی جاتی ہے اور چونکہ وابستگی اورمصاحبت کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ دو ہم نشین افراد کے عادات واخلاق ایک دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں ،لہذا انسان کونیک انسانوںکی دوستی اختیار کرنی چاہئے ،کیونکہ اس صورت میں ان کے نیک اخلاق اس میں سرایت کریں گے اس کی بے لوث اور خیرخواہانہ دوستی سے استفادہ کرے گا اوراس کی دوستی کی پائداری سے مطمئن رہے گا۔اس کے علا وہ لوگوںکی نظروں میں اس کی اجتماعی حیثیت بھی بڑھ جائے گی ۔
امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
''خیر الاصحاب من یَد لُّکَ علی الخیر''
''بہترین دوست وہ ہے جوتجھے نیک کام کی طرف راہنمائی کرے۔''
مزید فرماتا ہے :
''المرء یوزن بخلیله ''
''مرداپنے دوست کے ذریعہ تولا جاتا ہے ''(۱)
تو اول بگوباچہ کس زیستی
کہ تامن بگویم کہ توکیستی
ہمان قیمت آ شنایان تو
بود قیمت و ارزش جان تو
تم پہلے یہ بتاوکہ تم کس کے ہم نشیں ہوتاکہ میں بتاسکوں کہ تم کون ہوتیری قدروقیمت بھی وہی ہوگی جو تیرے دوست کی ہے۔
بروں کی مصاحبت
بروں اور گنہگاروںکے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بدبختی اور برے انجام کاسبب بنتاہے ۔اس مطلب کی وضاحت کے لئے اتناہی کافی ہے کہ اگرہم مجرموں اور بدکرداروں جیسے چوروں اورڈاکوئوں سے ان کے انحراف وگمراہی کے سبب کے بارے میں پوچھیں تو وہ کسی شک وشبہہ کے بغیرجواب دیں گے کہ برے لوگوں کی مصاحبت اورمعاشرت نے ہمیں
اس مصیبت میں گرفتارکیا ہے ۔ہزاروں بدکرداروں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا کی جس نے خودبخودناشائستہ راستہ کوانتخاب کیاہو۔
امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
''بروں کی ہم نشنی سے پرہیز کرو،کیونکہ برادوست تم کو اپنے جیسا بنادے گا، اور وہ تمہارے جیسانہیں بنے گا''(۲)
مزید فرماتے ہیں :
''ایاک ومصادقة الفاجر فانه یبیع مصادقه بالتّا فة'' (۳)
''بدکردارکی دوستی سے پرہیز کروکیونکہ وہ تم کو معمولی چیز کے مقابلہ میں بیچ دے گا.''
بابدان کم نشین کہ درمانی
خوپذیراست نفس انسانی
''بروں کی ہم نشنی کم اختیار کرو،کیونکہ انسان دوسروں کی عادت کوقبول کرنے والا ہوتا ہے ''
ماں باپ پر اولاد کے حقوق
انسان کو جوکام انجام دیناچاہئے جس کے بارے میں انجام دیتا ہو او راس کو اس کانفع ملتا ہو تو اسے ''حق'' کہتے ہیں اور جس کے لئے اسے انجام دینا چاہئے اسے ''فریضہ، حکم اور تکلیف'' کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی کے لئے اجرت پر کوئی کام انجام دیتا ہے،تو اجرت ادا کرنا صاحب کا رکا فرض ہے اور مزدور کا حق ہے۔ اگر صاحب کار نے اجرت ادا نہ کی تو
مزدور اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اور اپنے حق کا دفاع کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اس طرح خلق کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی ابدی نہیں ہے اور خواہ نخواہ کچھ مدت کے بعد، رخت سفر باندھتا ہے، خدائے تعالے نے انسان کی نسل کو نابودی سے بچانے کے لئے تناسل وتوالد کی روش کو قرار دیا ہے اور انسان کو تناسل کے وسائل مہیا کئے ہیں اور اس کے باطنی جذبات کو اس کام کی طرف متوجہ کیا ہے۔
اسی مکمل آمادگی کا نتیجہ ہے کہ انسان فطری طور پر اپنی اولاد کو اپنے بدن کاٹکڑا سمجھتا ہے اور اس کی بقا کو اپنی بقا جانتا ہے او راس کی آسائش و کامیابی کی راہ میں ہر قسم کی تلاش و کوشش کرتا ہے اور گوناگوں رنج و الم برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ذات یا شخصیت کی نابود ی کو اپنی ذات یا شخصیت کی نابودی جانتا ہے۔ حقیقت میں وہ خالق کائنات کے حکم کی تعمیل کر تاہے جو بشر کی بقا چاہتا ہے۔ لہذا ماں باپ کا فرض ہے کہ جس حکم میں ضمیر و شرع متفق ہیں اس کو اپنے فرزند کے بارے میں نافذ کریں اور اس کی اچھی پرورش کریں تا کہ وہ ایک شائستہ انسان بن جائے، اس کے لئے اسی چیز کا انتخاب کریں جس کو انسانیت کی نگاہ میں اپنے لئے انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم ان میں سے بعض حقوق کو بیان کرتے ہیں:
١۔ پہلے ہی دن سے جب بچہ بات یا اشارہ کو سمجھنے لگے، اس کے ضمیر میں پسندیدہ اخلاق او رشائستہ صفات کی بنیاد ڈال کر انھیں مستحکم کریں اور حتی الامکان اسے بیہودہ باتوںکے ذریعہ نہ ڈرائیں اور اسے بُرے اور عفت کے خلاف کاموں سے روکیں اور خود بھی اس کے سامنے جھوٹ بولنے ،گالیاں دینے اور برے الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کریں اور اس کے سامنے پسندیدہ کام انجام دیں تا کہ شریف او رعالی مزاج بن جائے اور اپنی طرف سے سنجیدگی،ہمت او رعدالت کامظاہرہ کریں تا کہ ان کی عدالت دوستی اورانسان پروری ''انتقال اخلاق'' کے قانون کے تحت اس میں منتقل ہوجائے اور زیادتی ، حوصلہ شکنی اور خود پرستی سے محفوظ رہے۔
٢۔ جب تک ممےّزنہ ہوجائے کھانے پینے، سونے اور اس کی دوسری ضرورتوں میں اس کاخیال رکھیں اور اس کے جسمی حفظان صحت کی رعایت کریں تا کہ وہ ایک سالم بدن اور قوی دماغ اور اچھا مزاج والابن کر تعلیم و تربیت کے لئے آمادہ ہوجائے۔
٣۔ جب بچہ میں تعلیم و تربیت کی استعداد پیدا ہو جائے( عام طو رپر یہ مرحلہ سات سال کی عمر میں آتا ہے) اسے معلم کے حوالہ کریں اور کوشش کریں کہ ایک شائستہ معلم کی تربیت میں رہے تاکہ جو کچھ اس سے سنے اس کا اس پر اچھا اثر پڑے اور وہ اس کے روح کی شرافت ، تزکیہ نفس او رتہذیب اخلاق کا سبب بنے۔
٤۔ جب بچے کی عمر اتنی ہوجائے کہ وہ عام پروگراموں یا خاندانی نشست و برخاست میں شرکت کر سکتا ہو، تو اسے اجتماعی رسومات سے آشنا کرنے کے لئے اپنے ساتھ پروگراموں میں لے جاناچاہئے اور پسندیدہ معاشرتوں کے طرز عمل سے اسے آگاہ کرنا چاہئے۔
اولاد پر ماں باپ کے حقوق
وہ آواز جو ضمیر او رشرع کے منادی کی طرف سے ماں باپ کے کانوں میں پہنچی ا ور انھیں اولاد کے بارے میں ذمہ دار بنادیا، اسی طرح ضمیر اور شرع کی آوازنے اولاد کو بھی متوجہ کیا اور اس پر فرض کردیا کہ اپنے ماں باپ کی نیکیوں کا ۔ ہاتھ، زبان یا ہر وسیلہ سے۔ شکریہ بجالائے۔
ماں باپ وہ ہیں جو خدا کے ارادہ سے اپنے فرزند کو وجود میں لائے ہیں اور اپنے آرام و سکون اس کے معنوی اور جسمانی آرام و سکون پر قربان کرکے ایک عمر راتوں کو جاگ کر اور دن میں رنج و غم برداشت کرکے اسے ایک قوی انسان بناتے ہیں۔
کتنی نامردی، پستی اور نمک حرامی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچائے یا ان کے بوڑھاپے اور ناتوانی کے دنوں میں ان کی مدد نہ کرے!!
خدا کی توحید ، جو انسان کا پہلا فریضہ ہے،کے بعددوسرا فریضہ جو اسلام نے انسان کے لئے معین کیا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے:
( وقضی ربُّک الاّ تعبد وا اَلّاا ایّاه و بالوالدین احساناً ) ...)
( اسرائ/ ٢٣)
''اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا...''
اسلام میں مقرر شدہ فریضے کے مطابق، فرزند کو کسی صورت میں یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار سمجھے اور ایک ایسا کام انجام دے جو ان کی رنجید گی کا سبب بنے ، اسے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہئے اوران کی نسبت فروتنی اور انکساری او راحسان و نیکی کے ساتھ پیش آنا چاہئے، خاص کر ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ لیکن جاننا چاہئے کہ ماں باپ کی مرضی کی رعایت کرنا صرف مستحب اور مباح کاموں میں ہے، واجبات میں ان کی مرضی کے مطابق انجام دینا لازم نہیں ہے۔
بھائیوںاور بہنوں کے باہمی حقوق
قرآن مجید میں ، رشتہ داروں کے با رے میں بارہا تا کید کی گئی ہے اور قطع رابطہ سے منع کیاگیاہے ۔ ماں باپ اور اولاد کے بعد انسان کے قریبی ترین رشتہ دار بھائی اور بہن ہیں اور ان کے درمیان اجتماعی رابطہ فطری ہے اور یہ رابطہ تمام رابطوں سے مستحکم اور بنیادی تر ہے۔ بھائی بہنوں کا فریضہ ہے،کہ ضرورت پر رشتہ کے ناطوں کونہ توڑیں اور آپس میں تعاون کرکے حتی الامکان ایک دوسرے کی مدد کریں اور ضرورت پر ایک دوسرے کی دستگیری کریں ۔ بڑے ، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اورہمدردی سے پیش آئیں او رچھوٹے بھی بڑوں کا احترام کریں۔
عاق والدین
خاندانی اجتماع میں اولاد کی ماں باپ سے وہی نسبت ہے جو ایک درخت میں شاخوں کی جڑ سے ہوئی ہے، چونکہ جس طرح درخت کی شاخوں کا وجود جڑ پر منحصر ہوتاہے، اسی طرح فرزند کی زندگی بنیاد ڈالنے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔چنانچہ انسانی معاشرہ والدین اوراولاد کے دوگروہ سے تشکیل پاتا ہے ،اسلئے معاشرے کی اصلی بنیاد والدین ہی ہیں ۔
ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا اورانھیں اذیت وآزارپہنچانا ، نمک حرامی اورنامردی کے علاوہ انسانیت کے انحطاط اور معاشرے کی نابودی کا سبب بنتا ہے ۔ کیوںکہ اولاد کی طرف سے ماںباپ کی بے احترامی ،ماں باپ کی طرف سے بھی عدم محبت اوربے توجہی کی صورت میں ظاہر ہوگی اوردوسر ے یہ کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو ذلیل وخوار اور پست نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اپنی اولاد سے اپنے سے زیادہ توقع نہیں رکھیں گے اوراپنے بوڑھا پے اورناتوانی کے دنوں میں ان کی طرف سے دستگیری اور مدد کی کوئی امید نہیں رکھیں گے اوراسطرح لا محالہ خاندان کی تشکیل سردمہری کا شکار ہوگی ،جیسا کہ آج کل بہت سے نوجوانوں میں ایسی حالت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔
اس طرزفکر کا عام ہونا قطعی طورپر تناسل اور توالد کی راہ کو مسدود کرتا ہے،کیونکہ کوئی عقل مند اپنی گراں بہا عمرکوایک ایسے پودے کی پرورش میں صرف نہیں کرتا جس کانہ وہ پھل کھاسکے گا اورنہ اس کے سایہ میں بیٹھ سکے گا اور نہ اس کو دیکھنے میں غم واندوہ کے علاوہ اسے کوئی فائدہ ہو گا ۔ممکن ہے ہم تصور کریں کہ حکومت مختلف انعامات سے لوگوں کو خاندان کی تشکیل میں تشویق کرے اور اسطرح ،تناسل وتوالد کامسئلہ حل ہو جائے ،لیکن یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ اجتماعی رسومات میں سے اگر کوئی بھی طریقہ اور رسم فطری پشت پنا ہی (جیسے ماں باپ اور اولاد کے جذبات )نہ رکھتی ہو تو وہ پائدار نہیں ہے۔
اس کے علاوہ فطری جبلتوں میں سے کسی ایک جبلت کو چھوڑنا انسان کومعنوی لذتوں سے محروم کرتا ہے۔
عزت نفس اور کامیابی
یہ بات مسلم اوریقینی ہے کہ ہر معاشرے میں بے چارے اورنادار،مدداوردستگیری کے مستحق ہوتے ہیں ۔سرمایہ داروں کافرض ہے کہ ان کی مدد کریں اوران کے اس مسلم حق کو پامال نہ کریں اورشرع مقدس میں اسلام نے بھی اس حق کی رعایت کے سلسلہ میں تاکید و نصیحت کی ہے ،اور دولتمندوں پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ناداروں اور بیچاروں کی مدد کریں ۔
خدائے متعال نے قرآن مجید میں خود کو نیکی کرنے والا،بخشش وعطا کرنے والا اور معاف کرنے والاکہاہے .اوراپنے بندوں کو یہ پسندیدہ صفتیں پیدا کرنے کی ترغیب وتشویق فرماتا ہے ۔
''خدائے متعال نیک کام انجام دینے والوں کے ساتھ ہے ۔''(۴)
نیز فرماتا ہے :
''جس چیز کو انفاق کرتے ہووہ خودتمہارے فائدے میں ہے ۔''(۵)
دوسری جگہ پر فرماتا ہے :
''جو کچھ انفاق کرتے ہو،وہ تمھیں پلٹادیا جاتا ہے اورتم نے کسی قسم کانقصان نہیں اٹھایا ہے''(۶)
احسان اور محتاجوں کی مدد
اجتماعی حالات اوراحسان کے فوائد کے بارے میں غور و فکر اور مطا لعہ ان آیات کے مضمون کوواضح کردیتا ہے ،کیونکہ حقیقت میں تمام اجتماعی توانائیاں سارے افراد کے لئے
کام کرتی ہیں اور جس معاشرے میں کچھ غریب و نادار فقر وتنگ دستی کی وجہ سے کام اور کوشش سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ان کی تعداد کے اعتبار سے مال وثروت کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کے نامطلوب نتائج تمام لوگوں کواپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اورنوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ دولت منددوسروں سے زیادہ بیچارے ہوجاتے ہیں، لیکن اگر مالدار اپنی نیکی اور بخشش سے ناداروں کی دستگیری کریں توان کے حق میں بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں کہ من جملہ ان کے:
١۔اس کام سے دوسروں کے دلوں میں اپنے بارے میں محبت پیدا کرتے ہیں اورایک گروہ کو اپناعاشق بناتے ہیں ۔
٢۔ایک ناچیز مال سے اپنے لئے زیادہ احترام حاصل کرتے ہیں ۔
٣۔تمام لوگوں کی پشت پناہی کو اپنے لئے حاصل کرتے ہیں ،کیونکہ لوگ نیکی کرنے والے کی طرف داری کرتے ہیں ۔
٤۔اس دن کے خطرے سے محفوظ رہتے ہیں کہ جس دن تمام ناداروں کی ناراضگی جمع ہوکرہرخشک وتر کوبہادے گی۔
٥۔وہی ناچیز مال جوانفاق کیا ہے ،اقتصاد کا پہیہ حرکت میں آنے کاسبب بنتا ہے اور معاشرے کے مال میں اضافہ ہو کرخود ان کی طرف پلٹتا ہے ۔
خدا کی راہ میں انفاق کرنے کی فضیلت اور اسکی طرف ترغیب اور تشویق کرنے کے بارے میں بہت سی آیات وروایات موجود ہیں ۔
تعاون
احسان ونیکی کامسئلہ جو بیان ہوچکا ،تعاون کے مختلف شعبوں میں سے ایک ہے جوانسانی معاشرے کی بنیاد ہے ،کیونکہ سماج کی حقیقت، افراد کاایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تاکہ ایک دوسرے کی مدد سے سبھی کاکام ٹھیک ہو جائے اور سبھی کی زندگی مستحکم اورسبھی کی ضرورتیںپوری ہوجائیں ۔ لیکن یہ تصورنہیں کرناچاہئے کہ دین مقدس اسلام نے نیکی کوصرف مال کی صورت میں چاہا ہے ،بلکہ ہربیچارے کی دستگیری ،اگرمال کی ضرورت بھی نہ ہو،دین مقدس اسلام کامقصدہے اورانسانی ضمیرکا مطلوب بھی ہے ۔
ایک جاہل کو علم سکھانا،ایک اندھے کاہاتھ پکڑنا،ایک گمراہ کی راہنمائی کرنااورگرے ہوئے کی مدد کرناوغیرہ سب احسان اورنیکی کے مصادیق اور اس تعاون میں سے ہیںکہ ہم نے اجتماع کو تشکیل دینے کے پہلے دن اس کے اعتبارکی تصدیق اورتائید کی ہے اور واضح ہے کہ اگرانسان ،بعض جزئی کام انجام نہ دے تو وہ بنیادی کام بھی انجام نہیں دے گا ،اگرغیراہم اور جزئی فرائض کی رعایت نہ کرے،تو وہ کلی اور اہم فرائض کوبھی انجام نہیں دے گا ۔
خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت کرن
نیک کام کا پسندیدہ ہونا ان نتائج کی بنا پر ہے جواس سے حاصل ہوتے ہیں البتہ جس قدریہ نتائج وآثارعوامی تراورپائندہ تر ہوں ،اسی قدر نیکی بھی پسندیدہ تر وعالی تر ہوگی ،ایک بیمار کا علاج کرنا نیک کا م اوراحسان ہے ،لیکن ایک ہسپتال کوتعمیر کرنااور اسے چالو کرناجس میں روزانہ سیکڑوں بیماروں کاعلاج کیا جائے،اس کے ساتھ قابل موازنہ نہیںہے ۔ایک طالب علم کی تعلیم پسندیدہ ہے ،لیکن ایک ادارہ کی تاسیس کے ساتھ قابل موازنہ نہیں ہے جس میں سالانہ سیکڑوں دانشور علم حاصل کرکے فارغ ہو جائیں۔یہی وجہ ہے کہ عام اوقاف اور عوامی سطح کے خیرات و نیکیاں احسان ونیکیوں کے عالی مراتب شمار ہوتے ہیں ۔
شرع کی زبان میں ان عمومی خیرات کو''صدقہ جاریہ''سے تعبیر کیاگیا ہے۔پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
''مرد کی سربلندی کاسبب دوچیزیں ہیں ،ایک فرزند صالح اوردوسرے صدقہ جاریہ ''
چنانچہ کتاب وسنت سے معلوم ہوتاہے کہ جب تک''صدقہ جاریہ'' باقی رہتاہے خدائے متعال ،صدقہ دینے والے کے نام ثواب لکھتا ہے ۔
یتیم کامال کھان
جس طرح لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا عقلاً وشرعاًپسندیدہ ہے اسی طرح خدا کے بندوں کے ساتھ بُرائی کرنا ناروا اورقابل مذمت کام ہے ،لیکن شرع مقدس اسلام میں ظلم کے چند مواقع کی شدت کے ساتھ نہی کی گئی ہے، کہ ان میں سے ایک ''مال یتیم میں تفریط'' ہے۔
اسلام نے یتیم کا مال کھانے کو گناہان کبیر میں شما رکیا ہے اور قرآن مجید میں صراحت سے بیان کیا گیا ہے، کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، حقیقت میں وہ آگ کھاتا ہے اور اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے بیانات سے معلوم ہوتاہے کہ اس قدر تاکید کا سبب یہ ہے کہ اگر کسی بوڑھے انسان سے ظلم کیا جائے تو ممکن ہے وہ مقابلہ کرنے کے لئے اٹھ کر اپنے حق کا دفاع کرے گا، لیکن کم عمر یتیم اپنے حق کا دفاع کرنے سے عاجز ہے۔
کسی کوقتل کرن
ظلم کا ایک اور مقام جسے شرع مقدس اسلام میں بہت ناپسند و قابل مذمت سمجھاگیاہے وہ ''قتل نفس اور بے گناہ کو قتل کرنا'' ہے۔
قتل نفس گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور خدائے متعال نے اپنے کلام میں ، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر جاناہے، یہ اس لئے ہے کہ انسان کو قتل کرنے والا انسانیت کے ساتھ سروکار رکھتا ہے اور انسانیت ایک آدمی اور ہزار آدمی میں یکساں ہے۔
رحمتِ خدا سے مایوسی
اسلام میں ایک خطرناک ترین گناہ ''خدا کی رحمت سے مایوسی ہے خدا ئے تعالے فرماتاہے:
( قل یٰعبادی الّذین اَسرفُوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمة اللّه ان اللّه یغفر الذُّنوب جمیعا انّه هو الغفور الرّحیم )
(زمر٥٣)
''پیغمبر! آپ پیغام پہنچاد یجئے کہ اے میرے بندو اجنھوں نے اپنے نفس پرزیادتی کی ہے رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والاہے اور وہ یقینا زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔''
ایک دوسری جگہ پر رحمت خداسے مایوس شخص کو قرآن کافر جانتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی رحمت اور بخشش سے مایوس ہوا، تو پھراس کے پاس باطنی طور پر تحریک کرنے والا محرک نہیں ہے کہ اچھے اور پسندیدہ کام انجام دے یا گناہا ن کبیرہ و صغیرہ اور بُرے کردار سے اجتناب کرے، کیونکہ ان دونوںچیزوں میں اصلی محرک عذاب خدا سے بچنے کے لئے ''رحمت و نجات کی امید'' ہے۔ اورچونکہ یہ امید اس شخص میں نہیں پائی جاتی ہے لہذایہ شخص اس کافر سے کسی قسم کا فرق نہیں رکھتا ہے جو کسی دین کا پابند نہیں ہے۔
جہاد اور دفاع سے فرارکی سزا
میدان جنگ سے بھاگنے اور دشمن کو پیٹھ دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ ، بھاگنے والا، اپنی جان کو معاشرے کی زندگی سے زیادہ قیمتی جانتا ہے اور حقیقت میں یہ دشمن کے سامنے دینی مقدسات اور معاشرے کی جان و مال کو پیش کرنے کے مترادف ہے جو اس کی زندگی کی حیثیتیوں کو دھمکا تا ہے۔
اسی لئے جہاداوردفاع سے بھاگنے کوگناہان کبیرہ میں شمارکیاگیا ہے اور خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے :
( ومَن یولّهم یومئذ دبره الامتحِّرفا لقتال اومتحّیزاالی فئةفقد باء بغضب من اللّه وماوٰه جهنم ) ...) (انفال١٦)
''اورجوآ ج کے دن پیٹھ دکھائیگا وہ غضب الہیٰ کا حقدار ہوگا اور اس کا ٹھکاناجہنم ہوگا علاوہ ان لوگوں کے جو جنگی حکمت عملی کی بناپرپیچھے ہٹ جائیں یاکسی دوسرے گروہ کی پناہ لینے کے لئے اپنی جگہ چھوڑدیں ۔''
____________________
١۔میزان الحکمة،ج٢،ص٣٢٧۔
۲۔شرح غررالحکم ،ج٢،ص٢٨٩۔
۳۔غررالحکم ،ح١٠٧،ص١٥٩۔
۴۔(عنکبوت٦٩)۔
۵۔(بقرہ٢٧٢)۔
۶۔(انفال ٦٠)۔
وطن کادفاع
مذ کورہ بیانات کے پیش نظراسلامی معاشرہ اورمسلمانوں کے گھربار کادفاع اہم ترین واجبات میں سے ہے ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( ولاتقولوا لمن یقتل فی سبیل اللّه اموات بل احیا ء ولکن لاتشعرون ) (بقرہ١٥٤)
''اورجولوگ راہ خدا میں قتل ہوجاتے ہیں انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمھیں ان کی زندگی کاشعور نہیں ہے ''
اسلام کی ابتداء میں جان ہتھیلی پر لے کر خونین جنگوں میں شرکت کر نے والے مجاہدوں اوراپنے پاک خون میں غلطاں ہونے والے شہیدوں کے بارے میں انتہائی حیرت انگیزاورعبرتناک داستانیں موجود ہیں ،یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے پاک خون اورٹکرے ٹکڑے ہوئے بدن سے اس دین مقدس اسلام کومستحکم بنایا ہے ۔
حق کا دفاع
ایک دوسرادفاع جوآب وخاک کے دفاع سے عمیق تراوروسیع ترہوتا ہے ،وہ حق کادفاع ہے ۔یہ دین اسلام کا تنہامقصدہے۔اس خدائی روش کابنیادی مقصد حق وحقیقت کوزندہ کرنا ہے ،اسی لئے اس دین پاک کو''دین حق''کہاگیا ہے ۔یعنی وہ دین جوحق کی طرف سے ہے، حق کے سواکچھ نہیں ہے اور حق کے علاوہ کسی چیز کو اپنامقصد قرارنہیں دیتاہے ۔
خدائے متعال اپنی کتاب کی توصیف میں ،جوتمام حقائق کی جامع کتاب ہے فرماتاہے:
(...( یهدی الی الحق والی طریق مستقیم ) (احقاف٣٠)
''...قرآن مجید راہنمائی کرتاہے حق کی طرف اورسیدھے راستہ کی طرف جس میں کسی قسم کاتناقض اورتضادنہیں پایاجاسکتاہے''
اسلئے ہرمسلما ن پر لازم ہے کہ وہ حق کی پیروی کرے اورحق بات کہے حق سنے اوراپنی تمام توانائیوں اور ہرممکن راہ سے حق کادفاع کرے۔
غیظ وغضب
غیظ و غضب ایک ایسی حالت ہے کہ اگر انسان میں پیدا ہوجائے تو اسے انتقام کی فکر میں ڈالتی ہے اور اس کے باطنی آرام کو انتقام لینے کی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔ اگر انسان اس حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے سلسلہ میں تھوڑی سی سستی اور کوتا ہی کرے تو بلافاصلہ اس کی عقل سلیم غیظ وغضب کے سامنے ہتھیا ر ڈال دیتی ہے اور ہر برا ئی اور نارواو ناشائستہ چیزاسے صحیح نظر آتی ہے اور وہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ انتقامی جذبہ کی وجہ سے ہر درندہ سے بڑا درندہ و اور ہر آگ سے زیادہ شعلہ ور ہوتا ہے ۔
اسلام میں انتقام لینے کے سیلاب کو روکنے کے لئے بہت ہی تاکید ہوئی ہے اور اس کی پیروی کرنے کی زبر دست مذمت کی گئی ہے۔ خدائے متعال ان لوگوں پربہت عنایت کرتا ہے اور انھیں عفو کرتاہے جو اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتے ہیں اورغصہ کی حالت میں بردباری سے کام لیتے ہیں۔ فرماتاہے:
(...( والکاظمین الغیظ و العافین عن النّاس ) (آل عمران/١٣٤)
''...اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔''
(...( و اذاما غضبوا هم یغفرون ) ( شوری/٣٧)
''... اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔''
کام کا واجب ہونا اور صنعت و حرفت کی اہمیت
کام اور سرگرمی ،وہ بنیادیں ہیں،جن پر نظام خلقت استوار ہے اور یہ ہر مخلوق کی بقاء کے ضامن ہیں۔ خدائے متعال نے اپنی مخلوقات میں سے ہر ایک کو اس کے حالات کے مطابق کچھ وسائل سے مسلح کیا ہے کہ ان سے استفادہ کرنے پر وہ منافع کو حاصل کرتاہے اور نقصانات سے بچتا ہے۔
انسان خداکی مخلوقات میں حیرت انگیز ترین اور پیچیدہ ترین مخلوق ہے، دوسری مخلوقات کی نسبت اس کی حا جتیں زیادہ ہیں اور لہذا زیادہ سرگرمی کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعہ، اپنی بے شمار ضرورتوں کو پورا کرسکے اور اپنے خاندانی نظام جسے فطرتاً تشکیل دیناچاہئے کو بھی برقرار کرسکے۔
اسلام چونکہ ایک فطری اور اجتماعی دین ہے، لہذا اس نے کارو کسب کوواجب قرارد یا ہے اور بیکار انسانوں کی اہمیت کا قائل نہیں ہے۔
اسلام میں ،ہرفرد کوا پنے سلیقہ اورشوق کے مطابق صنعت وحرفت جس کی طرف خدائے متعال نے انسانی فکر کی ہدایت کی ہے ان میں سے کسی ایک کوانتخاب کرنا چاہئے اوراس طریقہ سے اپنی روزی کمائے اورمعاشرے کی ذمہ داریوں میں سے کسی ایک کواپنے ذمہ لے لے اور لوگوں کی آسودگی کے بارے میں کوشش کرے ۔خدائے متعال فرماتا ہے :
( واَن لیس للانسان اِلّا ماسعی ) (نجم٣٩)
''اور یہ کہ انسان کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے ،مگر یہ کہ سعی وکوشش کرے۔''
بیکاری کے نقصانات
مذکورہ بیانات سے واضح ہوا کہ کاروکوشش ایک راستہ ہے جسے خالق کائنات نے انسان کے اختیارمیں قراردیا ہے تاکہ اسے طے کر کے اپنی زندگی کی سعادت کو پاسکے ،البتہ خلقت و فطرت کی راہ سے انحراف چاہے کم ہی کیوں نہ ہوانسان کے لئے نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ۔اس صورت میں جس چیز پرنظام زندگی استوار ہے ،اس سے انحراف کرنے میں دنیاوآخرت کی بد بختی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ۔
اسی لئے ساتویں امام حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں :
''کام میں سستی اورتھکاوٹ کااظہارنہ کرناورنہ دنیاوآخرت تیرے ہاتھ سے چلی جائیگی۔''(۱)
خود اعتمادی
عقائد کے باب میں بار ہایاد دہانی کرائی گئی کہ اسلام کاعام پرو گرام یہ ہے کہ انسان خدائے یکتا کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرے اور خالق کائنات کے علاوہ کسی کے سامنے سرتعظیم خم نہ کرے ۔
سب خدا کی مخلو ق اور اس کی پرورش یافتہ ہیں اوراس کا رزق کھاتے ہیں اورکسی کو کسی پر فضیلت کاحق نہیں ہے ،سوائے اس چیز کے جوخدا کی طرف پلٹے ۔
ہر مسلمان کو اپنے نفس پر اعتماد کرنا چاہئے اورجوآزادی خدانے اسے دی ہے اس سے استفادہ کرے ،اورجو وسائل اسے فراہم کئے ہیں ان سے بھرپورا فائدہ اٹھائے اور زندگی کی راہ کوطے کرے ،نہ یہ کہ دوسروں پرامید باندھ کرہر روز خدا کے لئے ایک شریک ٹھہرائے اور ایک تازہ بت بنائے ۔
نوکر کو جاننا چاہئے کہ وہ اپنی روٹی کھاتا ہے نہ مالک کی ۔مزدورکو جانناچاہئے کہ وہ اپنی کمائی کی اجرت حاصل کرتا ہے نہ صاحب کار کی مفت میں دی گئی بخشش .ہرملازم کو ایمان رکھنا چاہئے کہ وہ اپنے کام کی مزدوری حاصل کرتا ہے نہ رئیس یا حکومت مربوطہ ادارہ یامعاشرے کاتحفہ۔
آخر کار آزاد انسان کو خدا کے علاوہ کسی سے امید نہیں باندھنی چاہئے اور کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہئے ورنہ اس کے باطن میں وہی پستی اورشر ک کی غلامی پیدا ہوجائے گی جس کے آشکارا طور پر بت پرست شکار ہیں ۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بیکاری کی عادت کر نے وا لوں اوراپنا بوجھ دوسروں پر ڈالنے والوں پرلعنت بھیجی ہے ۔
دور حاضر میں اجتماعی اور نفسیاتی تحقیقات سے واضح طورپر معلوم ہوتاہے کہ اجتماعی برائیوں کاایک بڑا حصہ بیکاری کی وجہ سے ہے ۔یہی بیکاری ہے جومعاشرے کے اقتصاد اورثقافت کے پہیے کو چلنے سے روکتی ہے اور ہرقسم کے اخلاقی زوال اورخرافات پرستی کو رواج بخشتی ہے ۔
کھیتی باڑی اور اس کے فائدے
کھیتی باڑی جس کے ذریعہ معاشرے کے لئے اناج مہیا کئے جاتے ہیں اپنی اہمیت کے پیش نظر انسان کے پسندیدہ ترین مشغلوں میں شمار ہوتی ہے ،اسی لئے اسلام میں اس شغل کو اختیار کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے ۔
چھٹے امام،حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
''قیامت کے دن کا شت کاروں کا مقام ہرمقام سے بلندتر ہوگا ۔''(۲)
پانچویں امام حضرت امام محمدباقرعلیہ السلام فرماتے ہیں :
''کوئی بھی کام کھیتی باڑ ی سے بہتراور اس کا فائدہ اس سے زیادہ عمومی نہںہے .کیونکہ نیک وبد،چرند وپرند سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اورزبان حال سے کسان کے لئے دعا کرتے ہیں۔(۳)
دوسروںکے سہارے زندگی گزارنے کے نقصانات
''طفیلی زندگی''یعنی دوسروں کی امید اور پشت پناہی میں زندگی گزارنا۔حقیقت میں ایسی زندگی،انسانی فخر،شرافت اورآزادی کو کھودینے اور تمام اجتماعی برائیوں اور جرم وگناہ کا باعث ہے کہ جس کا سر چشمہ ذلت وخواری ہے ۔
جودوسرو ں کے سہارے ہوتا ہے اس کی نگاہ لوگوں کی دست کرم پر ہوتی ہے ، وہ حقیقت میں اپنے ارادہ و ضمیر کو اس راہ میں بیچ دیتا ہے ،اسے کرم فرما کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے وہ اس سے جو کچھ چاہتا ہے خواہ ''حق ہو یا باطل اچھا ہویابرُا''وہ اسے انجام دینے پر مجبورہوتا ہے۔اورہر ننگ وعار کو قبول کرنے ،اجنبی پرستی ،ہرظلم وبے انصافی پر راضی ہو جانے اورآخر کار،تمام انسانی قواعد وضوابط کو پامال کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔
اسلام میں ضرورت کے بغیر سوال کرنا حرام ہے ،فقراء کی مالی امداد،جو اسلامی ضوابط میں ہے ،صرف ان فقیروں سے مربوط ہے کہ جن کی آمدنی ان کے اخراجات کے لئے کافی نہ ہو یا کوئی کار وبارنہ ہو۔
ناپ تول میں کمی کی سزا
اسلام کی نظر میں ناپ تول میں کمی کرنا گناہ کبیرہ ہے ۔خدائے متعال اس گناہ کے مرتکب افراد کی سرزنش اور مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے :
( ویل للمطفّفین٭ اَلاَ یظُنّ اولئک أنهم مبعوثون٭ لیوم عظیم ) ( مطفّفین١۔٥)
''ویل ہے ان کے لئے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں...کیا انھیں یہ خیال نہیںہے کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھا ئے جانے والے ہیں؟۔''
ناپ تول میں کمی کرنے والا، لوگوں پر ظلم کرنے کے علاوہ، ان کے مال کو چوری کے را ستہ سے لوٹتا ہے، لوگوں میں اپنے اعتماد کو کھودیتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنے گاہکوں او راس کے بعد اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔
ظلم و ستم کی برائی
خدائے متعال نے اپنے کلام پاک میں سیکڑوں بار ''ظلم'' کا ذکر کیا ہے اور اس بری صفت جو درندوں کی خصلت ہے کی مذمت کی ہے(قرآن مجید کے دوتہائی سوروں میں ، جو مجموعاً ١١٤ سورے ہیں، ظلم کا ذکر کیا گیا ہے)
ایسا کوئی انسان پایانہیں جاسکتا کہ جس نے اپنی فطرت سے ظلم کی برائی کو درک نہ کیا ہو، یا کم ازکم یہ نہ جانتاہوکہ ظلم و ستم نے انسانی معاشرے کے پیکر پر کتنی دردناک مصیبتیں ڈھائی ہیں اور کتنا خون بہایاہے اور کتنے گھروں کو ویران کیا ہے۔
تجربے سے یقینی طور پر ثابت ہوا ہے کہ ظلم و ستم کے محل کتنے ہی مضبوط کیوںنہ ہوں پائدار نہیں ہوتے اور کسی نہ کسی وقت ظالموں کے سروں پر گر کرڈھیر ہوجاتے ہیں۔ خدائے متعال فرماتاہے:
(...( ان اللّه لا یهدی القوم الظّٰلمین ) ( انعام/١٤٤)
''...خدائے متعال ہرگز ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے.''
اولیائے دین فرماتے ہیں:
''سلطنت اور ملک ، کفر سے باقی رہ سکتا ہے، لیکن ظلم و ستم سے باقی نہیں رہ سکتا''(۴)
مردم آزاری اور شرارت حرام ہے
یہ دو صفتیں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، کیونکہ ''اذیت'' پہنچانا، دوسروں کو زبان سے رنج و تکلیف پہنچاناہے، جیسے گالی دینا اور ایسی بات کہنا جس سے مخاطب رنجید ہ ہوجائے یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام انجام دینا جس سے لوگ ناراض ہوجائیں۔ ''شرارت'' ایسا کام انجام دینا جو لوگوںکے لئے ''شر'' کا باعث ہو۔
بہر حال یہ دو صفتیں انسان کی ان آرزؤں کے مقابلہ میں قرار پائی ہیں، کہ انسان جن تک پہنچنے کے لئے اجتماع کو وجود میں لایا ہے، کہ وہ زندگی کی آرام و آسائش ہے۔
یہاں پر اسلام کا شرع مقدس، معاشرے کی مصلحت کو پہلے درجہ میں قرار دیتا ہے اور مردم آزاری و شرارت کو حرام قرار دیتا ہے ، چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے:
( وَالَّذین یُوذون المؤمنین و المومنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتٰنا و اثماً مبیناً ) ( احزاب٥٨)
''اور جو لوگ صاحبان ایمان مرد یا عورت کو بغیر کچھ کئے دھرے اذیت دیتے ہیں، انہوں نے بڑے بہتا ن اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سرپر اٹھا رکھا ہے۔''
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:
''جس شخص نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور میری اذیت خدا کی اذیت ہے، ایسے شخص پر توریت، انجیل اور قرآن مجید میں لعنت کی گئی ہے۔''(۵)
چوری
چوری ایک برا اور نامناسب مشغلہ ہے جو معاشرے کی اقتصادی حیثیت کو خطرہ میں ڈالتا ہے۔ بدیہی ہے کہ انسان کی زندگی کے ابتدائی ضروریات میں سے مال و ثروت ہے جسے انسان اپنی عمر کی قیمت پر حاصل کرتا ہے او راس کی حفاظت کے لئے اس کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنادیتا ہے تا کہ ہر قسم کے تجاوز سے محفوظ رہے اور اس طرح اس کا مال معاشرے کی زند گی کی ضمانت او ر اس کا پشت و پناہ بن جائے۔ البتہ اس دیوار کو توڑنا اور اس نظم کو ختم کرنا ایک ایسی عمر کے سرمایہ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے کہ جس کو حاصل کرنے میں اس کی پوری عمر خرچ ہوئی ہے اور لوگوں کی سرگرمیوں کے ایک بڑے حصہ کو معطل کرنا لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کے برابر ہے۔
اسی لئے اسلام نے اس نفرت انگیز عمل کے لئے کہ خود چور کا ضمیر بھی اس کے جرم ہونے کی گواہی دیتا ہے، یہ سزا مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ (یعنی دائیں ہاتھ کی چار انگلیاںکاٹ دی جائیں ) خدائے متعال فرماتاہے:
( والسّارق والسّارقة فاقطعوا ایدیهما جزائً بما کسبا ) ...)
(مائدہ ٣٨)
''چو ر مرد او رچور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو کہ یہ ان کے لئے بدلہ اور خدا کی طرف سے ایک سزا ہے...''
فرض شناسی
زندگی کے یہ بے شمار وسائل جو آج کل ہم انسانوں کے اختیار میں ہیں اورہم ان کو حاصل کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کے لئے دن رات کوشش کرتے ہیں، ابتداء میں انسان کے اختیار میں نہیں تھے، بلکہ انسان کی سرگرمیوں کے نتیجہ میں تدریجاً وجود میں آئے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جارہاہے۔ لیکن بہر صورت ابتدائی بشر سے لیکر آج کے متمدن انسان تک ہرگز کا ر و کوشش کا سلسلہ نہیں رکاہے بلکہ انسان نے اپنی خدا داد فطرت کے ذریعہ اپنی زندگی کے وسائل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جس انسان کی وجودی توانائی کی سرگرمی ٹھپ ہو جاتی ہے تواس کو مسلح کرنے کے داخلی و خارجی وسائل، آنکھ ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، دماغ،دل ، پھیپھڑے اور جگر وغیرہ بے کار ہوجائیں گے،اور وہ مردہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔
اسی لئے انسان نہ صرف مجبورہوکر کام کرتا ہے ،بلکہ اس جہت سے بھی کہ وہ انسان ہے لہذا گوناگوںسرگرمیاں انجام دیتا ہے ،کیونکہ وہ اپنے انسانی شعور سے درک کرتا ہے کہ جس راہ سے بھی ممکن ہو ،وہ اپنی زندگی کی سعادت اورخوشبختی کو حاصل کرے ،اس لئے کاروکوشش میں لگ جاتا ہے اوراپنے مطالبات کی راہ میں قدم رکھتا ہے ،لہذا انسان جس ماحول اور جس روش پر زندگی گزار تا ہے خواہ:دینی ہویا غیردینی ،قانونی ہو یا استبدادی اورشہری ہویاخانہ بدوشی کی، اس میں اپنے لئے کچھ تکالیف وفرائض (وہ کام جن کا زندگی میں انجام دینا لازم جانتا ہے ) کااحساس کرتا ہے کہ ان کوانجام دینے میں انسان کی حقیقی آرزوئوں کو پورا کرسکتا ہے اوراس کے لئے خوشحالی کی اور آسودہ و سعادتمندانہ زندگی فراہم کرسکتا ہے ۔
البتہ ان تکا لیف اور فرائض ،جوسعادتمندی کی تنہا راہ ہے ،کی قدروقیمت خود انسانیت کی قدر و قیمت ہے کہ ہم اس سے زیادہ گراں بہا کسی چیز کا تصور نہیں کرسکتے اوراسے کسی دوسری چیزسے بدل نہیںسکتے ۔
اس بناپر ''فرض شناسی''اور اسکا انجام دینا عمل کے میدان میں اہم ترین مسئلہ ہے کہ اس کا سروکار انسان کی زندگی سے ہے ،کیونکہ اس کی اہمیت خود انسان کی اہمیت ہے ،جو شخص اپنے مسلمہ فرائض کوانجام دینے میں پہلو تہی کرتا ہے ،یاکبھی کوتاہی کرتا ہے ،تو وہ اسی کے مطابق انسانیت کی بلندی سے گرجاتا ہے اور فطری طورپر اپنی پستی اور بے قیمتی کا اعتراف کرتا ہے یا جوبھی خلاف ورزی کرتا ہے ،وہ اپنے معاشرے کے پیکر پر بلکہ حقیقت میں اپنے پیکر پرایک کاری ضرب لگاتاہے ۔
خدائے متعال فرماتاہے :
( والعصر٭انّ الانسٰن لفی خسر٭الا الَّذین آمنوا وعملواالصّٰلحت وتواصوا باِلحق وتواصوابالصّبر )
(عصر٣١)
''قسم ہے عصر کی بیشک انسان خسارہ میں ہے ٠علاوہ ان لوگوں کے جوایمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال انجام دئے اور ایک دوسرے کو حق اورصبر کی وصیت ونصیحت کی۔''
نیز فرماتا ہے :
( ظهر الفساد فی البرّوالبحر بماکسبت ایدی النّٰاس ) ...)
(روم٤١)
''لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بناپر فساد خشکی اورتری ہر جگہ غالب آگیا ہے ۔''
فریضہ کی تعیین میں مختلف روشوں کا اختلاف
عا لم انسانیت میں فریضہ کو پہچاننے اور اس پرعمل کرنے کی اہمیت بذات خود ایک پائدارو مسلم فریضہ ہے اور ہرگز کوئی ایسا انسان نہیں پایاجاسکتا جواپنی انسانی فطرت سے اس حقیقت کامنکر ہو ۔
جی ہاں ،چونکہ انسانی فرائض انسان کی زندگی کی سعادت سے مکمل رابطہ رکھتے ہیں اوردین انسانی زندگی کے بارے میں غیردینی طریقوںسے نظریاتی اختلاف رکھتا ہے لہذادینی فرائض،دوسرے فرائض کی روشوں سے اختلاف رکھیں گے۔
دین کا عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک لامحدوداورابدی ہے ،جوموت سے ختم نہیںہوتی اور موت کے بعداس ابدی زندگی کاسرمایہ وہی صحیح عقائد ،پسندیدہ اخلاق اوراعمال صالحہ ہیں جنھیں انسان نے دنیا میں حاصل کیا ہے۔
اس لحاظ سے دین نے جو فرائض اور تکالیف فرداورمعاشرہ کے لئے مرتب کئے ہیں ،ان میں اس ابدی دنیاکی زندگی کو بھی مدنظر رکھا ہے ۔
دین اپنے قوانین کوخداشناسی اورخداکی عبادت وبندگی کی روشنی میں مقّرر کرتا ہے جس کاواضح اثرموت کے بعد قیامت کے دن ظاہر ہو گا ۔
غیر دینی طریقے (جوبھی ہوں)صرف اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو مدنظر رکھتے ہیں اور انسان کے لئے کچھ فرائض وضع کرتے ہیں تا کہ ان کے ذریعہ مادی زندگی اور جسمانی قوای جو تمام حیوانوں میں مشترک ہیںسے بہتر استفادہ کریں۔حقیقت میں یہ طریقے ایک حیوانی زندگی کو انسان کے لئے مرتب کرتے ہیں کہ جس کی منطق کا سرچشمہ چرندوں اور درندوں کے جذبات ہوتے ہیں اور انسان کی حقیقت پسندی اور اس کی معنویات سے بھری ابدی زندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔
یہی وجہ ہے کہ انسانیت کے بلند اخلاق (جیسا کہ قطعی تجربہ بات سے ثابت ہے) غیر دینی معاشروں سے رفتہ رفتہ ختم ہورہے ہیں اور روز بروز ان کا اخلاقی انحطاط و اضح و آشکارتر ہوتاجارہاہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں: دین کی بنیاد ، تقلید پر ہے، یعنی چون وچرا کے بغیر فرائض اور قوانین کے ایک سلسلہ کو قبول کرنا ، لیکن اجتماعی طریقے وقت کی منطق کے ساتھ قابل مطابقت ہیں۔
جنہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے اس نکتہ سے غفلت کی ہے کہ جو قوانین و ضوابط معاشرے میں نافذ ہوتے ہیں، ا ن کو بلا چون و چرا نافذ ہونا چاہئے۔
ہرگز یہ نہ دیکھا گیا ہے اور نہ ہی سناگیا ہے کہ کسی ملک میں لوگ ملک میں لاگو قوانین پر مناظرہ اور بحث و گفتگو کے بعد ان پر عمل کرتے ہوں اور جو بھی ان قوانین کے فلسفہ کو نہ سمجھ سکا وہ اس پر عمل کرنے سے معاف ہو اور ان کو قبول کرنے میں مختار ہو، اس سلسلہ میں دینی اور غیر دینی روش میں کوئی فرق نہیں ہے۔
لیکن کسی ملک کے فطری او راجتماعی حالات کا مطالعہ اور اس کی عام روش میں جستجو کرکے اس ملک کے قوانین کے کلیات کی حکمت کے کچھ جزئیات معلوم کئے جاسکتے ہیں۔
دینی قوانین میں بھی یہی خاصیت پائی جاتی ہے۔ حقیقت پسندانہ راہ سے اور خلقت اور انسان کی فطری ضرورتوںکے بارے میں جستجو کرکے دین کے قوانین کے کلیا ت جو فطری روش ہے کے بارے میں بعض جزئیات کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔
قرآن مجید او ربہت سی روایتیں انسان کو سوچنے ، غورو فکر او رتدبر کی دعوت دیتی ہیں اور بعض احکام میں اجمالی مصلحت کے بارے میں حکم یا اشارہ کیا جاتاہے، چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ا وراہل بیت اطہار علیہم السلام سے احکام کے فلسفہ کے بارے میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں اور در دست ہیں۔
دفاع کی اہمیت
جس طرح ایک انسان اپنی زندگی میں خوشبختی اور سعادت کا شیدائی ہوتا ہے اور ان کو حاصل کرنے میں سرگرم عمل ہو تا ہے، اسی طرح وہ ہرطرف سے بے شمار خطرات سے بھی دوچارہوتاہے۔ ان میں سے بعض خطرے اس کے اصل وجود کو اور بعض اس کی زندگی کی سعادت و خوشبختی کو نشانہ بناتے ہیں، اس لئے انسان ان کو دور کرنے کے لئے مقابلہ اور دفاع کرنے پر مجبور ہے۔
انسان کی خلقت میں بھی ان ہی دو مرحلوں ''جذب و دفع'' کی پیشنگوئی کی گئی ہے، اور اس کے وجود کی عمارت میں مناسب وسائل استعمال ہوئے ہیں۔اسی طرح معاشرہ کے کچھ فوائد ہیں کہ جنھیں حاصل کرناچاہئے اوربعض خطرات سے بھی دوچار ہے کہ بہر حال ان کے مقابلہ میں کھڑے ہوکر اپنی زندگی کے مقدسات کا دفاع کرنا چاہئے۔
جس نے لوگوں کی جانوں کو ختم کرنے ، آزادی کے پرچم کو سرنگوں کرنے یا ان کی آزادی کو ختم کرنے کو اپنا مقصد قرار دیا ہے، وہ معاشرے کا دشمن ہے۔ انسان کا فقر و ایما ن کی کمزوری اور نادانی معاشرے کے دشمن ہیں ، جو اپنے معاشرے ، یعنی زندگی کی سعادت اور انسا نی حقیقت کا پابند ہے، اسے اپنے ان خطرناک دشمنوں کے مقابلہ میں دفاع کرنا چاہئے۔
بخش دین
اس میں کوئی شک و شبہہ نہیں ہے کہ انسان کے ضمیر میں ، اصل زندگی اور شرافت مندانہ زندگی کی ایک ہی بنیادہے اور جو زندگی شرافت کے ساتھ ہولیکن انسان کی سعادت اس میں نہ ہو، تو وہ حقیقت میں زندگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی موت ہے جو طبیعی موت سے تلخ و ناگوارہے، جو انسان اپنی شرافت و سعادت کی اہمیت کا قائل ہے، اسے اس پست زندگی سے موت کی طرح فرار کرنا چاہئے۔
انسان جس ما حول میں بھی رہ رہا ہو اور جس روش کی طرف بھی مائل ہو، وہ اپنی خدا داد فطرت سے سمجھتا ہے کہ محترم و مقدس میں موت، بذات خود ایک سعادت ہے، دین کی منطق میں یہ مسئلہ دوسری ہر منطق سے زیادہ واضح اوروہم و گمان کے خرافات سے نہایت دورہے، جو شخص دین کے حکم سے اپنے دینی معاشرے کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان نچھا ور کردے ،وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی چیز سے محروم نہیں ہوا ہے بلکہ اس نے اپنی چند روزہ زندگی کو خدا کی راہ میں پیش کرکے ایک نہایت شیرین، گراں بہااور ابدی زندگی کو حاصل کیا ہے اور یقینا اس کی سعادت ناقابل زوال ہے .چنانچہ خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے :
( ولاتحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اللّه امواتاً بل احیائ عند ربّهم یرزقون ) (آل عمران ١٦٩)
''اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرناوہ زندہ ہیں اوراپنے پروردگار کے یہاں رزق پارہے ہیں ''
لیکن غیر دینی طریقے،جوانسان کی زندگی کو اسی دنیا کی چند روزہ زندگی تک محدودجانتے ہیں،ہرگز نہیں کہہ سکتیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے یا سعادت وخوشبختی حاصل کرتا ہے ، مگر یہ کہ وہم و گمان اور خرافات سے سمجھ میں آ جائے کہ جو وطن یا قومی مقدسات کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے ،اس کا نام جاں نثاروں اورقوم کے فداکاروں کی فہرست میں قرار پاسکتا ہے اور تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاسکتا ہے اور ہمیشہ کے لئے زندہ وجاوید رہ سکتا ہے ۔
لیکن جو تمجید اور تعظیم اسلام میں خدا کی راہ میں شہید ہونے اور قتل کئے جانے کے سلسلے میں کی گئی ہے ،وہ کسی اورصالح عمل کے لئے نہیں کی گئی ہے ۔پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
''ہرنیکی سے بالاتر ایک نیکی ہے یہاں تک کہ راہ خدامیں شہید ہو جائے ،اس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے ۔''(۶)
صدراسلام کے مسلمان پیغمبرخداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتے تھے اورآنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجہ میں شہادت کے اعلی درجہ پر فائز ہوتے تھے اور شہادت کے ذریعہ دنیاسے چلے جانیوالوں کے لئے گریہ نہیں کرتے تھے ،کیونکہ وہ زندہ ہیں اورنہیں مرے ہیں ۔
مال کی ز کواة
مال سے انسان کی زندگی میں جو اعتدال پیدا ہوتاہے ،وہ محتاج بیان نہیں ہے ۔اسکی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ بہت سے لوگ زندگی مال کوہی جانتے ہیں اور انسان کے لئے مال ودولت کے علاوہ کسی فضیلت وشرافت کے قائل نہیں ہیں ۔اوراپنی تمام سرگرمیوں کو پیسے جمع کرنے اورمال ذخیرہ کرنے میں صرف کرتے ہیں اور نتیجہ میں مال سے یہی دلبستگی اور حرص ان کو بخل کی صفت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں اور کبھی اس سے بلند ترقدم اٹھاکر پستی اوربخل کے سامنے تسلیم ہو کرخود بھی اس مال سے بہرہ مند ہونے سے محروم ہوجاتے ہیں ،اس طرح نہ خودکھاتے ہیں اورنہ دوسروں کو کھلاتے ہیں اور صرف پیسے جمع کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں ۔
جوافرادبخل کی ناپسندیدہ صفت میں مبتلا ہیں (البتہ کنجوسی میں مبتلا ہونے والے ان لوگوں سے پست ہیں )وہ انسانی فطرت سے گرجاتے ہیں اورزندگی کے بازار میں دیوالیہ ہوتے ہیں ،کیونکہ :
١۔زندگی میں ،صرف اپنی سعادت ،خوشبختی اور آسودگی کو چاہتے ہیں اورانفرادی زندگی کے قائل ہوتے ہیں ،جبکہ انسان کی فطرت نے اجتماعی زندگی کو ہمارے لئے زندگی کے عنوان سے پہچنوایا ہے اورانفرادی زندگی جس راہ سے بھی ہو،اس کاانجام ناکامی ہے ۔
٢۔اپنی قدرت کا دوسروں کے سامنے مظاہرہ کرکے محتاجوں اورناداروں کی خا طر و تواضع کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں اور باوجودیکہ محتاجوں کی کوئی مدد نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان سے ہمیشہ اپنی تعظیم کرانا چاہتے ہیں ،ان کے ساتھ غلاموں کا سلوک کرتے ہیں اوربت پرستی کاجذبہ زندہ رکھتے ہیںجس کے نتیجہ میں معاشرے سے ہرقسم کی شہامت ،شجاعت ،فطرت کی بلندی اورانسانی فخرومباہات ختم ہوجاتے ہیں ۔
٣۔اس کے علاوہ کہ وہ خود پاک جذبات،محبت،مودت،انسان دوستی،خیرخواہی اور انسانی ہمدردی کو پامال کرتے ہیں ،معاشرے میں جرم وخیانت اور ہرقسم کی پستی ورذالت کو ترویج دیتے ہیں،کیونکہ جرم وجفا،جیسے: بدگوئی ،بے حیائی ،چوری ،ڈاکہ زنی اورآدم کشی کا قوی ترین طبیعی عامل محتاجوں کے طبقہ میں موجودفقروفاقہ غیظ و غضب اور کینہ وہ انتقامی جذبہ ہے جومالداروں کے بارے میں ناداروں اوربیچاروں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے ،کہ اس کے بخیل اورکنجوس مال داراس کے باعث ہوتے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بخیل شخص در حقیقت معاشرہ کاسب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، بہرحال وہ خدا کے غضب وسخت سزااور لوگوں کی نفرت میں گرفتار ہوگا ۔
قرآن مجید میں بخل اورکنجوسی کی ناپسند صفتوں کی مذمت اورسرزنش میں اور اس کے برعکس جود وسخاوت،اورخدا کی راہ میں انفاق اور ناداروں وبے چاروں کی دستگیری کرنے والوں کی مدح وثناء میں بہت سی آ یتیں نازل ہوئی ہیں ۔
خدائے متعال اپنے کلام پاک میں وعدہ کیاہے کہ ،جومال انفاق کیا جاتا ہے ،اس کے عوض دس اوربعض مواقع میں سترّ بلکہ سات سوسے بیش تر تک اضافہ کرکے انفاق کرنے والے کو واپس بھیجا جاتا ہے۔
تجربہ سے بھی ثابت ہو اہے کہ سخی لوگ جب جوانمردی کے ساتھ حاجتمندوں کی مدد کرتے ہیں اور انسانی معاشرے کی مشکلات کو دورکرتے ہیں توروز بہ روز ان کی دولت او رنعمتوں میں اضافہ ہوتاہے۔
کار گرہ گشا نشود در زمانہ بند
ہزگر کسی ندید در انگشت شانہ بند
اگر لو گ کسی دن مشکلات سے دوچار ہوجائیںتو تمام دل ان کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے جو دوسروں کے حق میں مدد کی ہے وہ اجتماعی صورت میں ان کے حق میں لوٹے گی ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اچھے کردار سے ایک شریف انسان کے مانند اپنے ضمیر کو آرام بخشاہے، واجب اور مستحب حقوق کے بارے میں ندائے آسمانی کو لبیک کہا ہے اور انسانیت کے پاک جذبات سے مہربانی، شفقت، انسان دوستی اور خیر خواہی سے استفادہ کیا ہے، اس طرح عام محبوبیت اور خالص احترام کے مستحق ہوئے اور آخر کار خدا کی خوشنودی او رابدی سعادت کو کم ترین قیمت پر خرید لیا ۔
علم کی زکواة
''علم او رثقافت'' بے نظیر دولت ہے، جن سے انسان اپنی زندگی میں ہرگز بے نیاز نہیں ہوتاہے اور ایسا انسان نہیں پایا جاسکتا ، جو اپنی انسانی فطرت سے جہل پر علم کی برتری کو درک نہ کرتا ہو یا علماء اور دانشوروں کے احترام میں ان کے حق میں فیصلہ نہ دیتا ہو۔
خدائے متعال اپنے کلام پاک میں عالم و جاہل میں فرق کے بارے میں زندہ و مردہ اور بینا و او ر نابینا کی مثال دیتاہے۔ اوراسلام میں علم و دانش کو جو اہمیت دی گئی ہے، وہ اہمیت کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی، یہاں تک کہ پیغمبر اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:
''علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے ''(۷)
نیز فرماتے ہیں:
''گہوارہ سے قبر تک علم حاصل کرو چاہے دنیا کے اس پار بھی ہو۔ ''(۸)
اسی کے پیش نظر اسلام نے بخل اور کنجوسی کی نہی کی ہے۔ علم کو چھپانے کی مذمت کی ہے، بلکہ دینی علوم کو چھپانا حرام قرار دیا ہے اور عالم کو جاہل کی تربیت کرنے کاذمہ دار قرار دیا ہے۔
معاشرے کے اندرونی دشمنوں سے مقابلہ
چنانچہ ، فطرت کے حکم سے، معاشرے کے بیرونی دشمنوں سے جنگ کرنی چاہئے اور معاشرہ کو نقصان سے بچانا چائے اور ، اسی طرح معاشرے کے اندرونی دشمنوں سے بھی جنگ او رمقابلہ کرنا چاہئے۔ معاشرے کا اندرونی دشمن وہ ہے جو عام روش او رجاری قوانین کی مخالفت کرتا ہے اور اس طر ح معاشرے کی زندگی کے ناطے کو توڑدیتا ہے اور جاری نظام کو درہم و برہم کردیتا ہے، اس لئے نظم و نسق ،امور کی حفاظت اور معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لئے کچھ افراد پر مشتمل پلیس و غیرہ کا نظام تشکیل دیا جاتا ہے اورخلاف ورزی کرنے والوں کے لئے مختلف سزائیں مقرر کی جاتی ہیں۔
اسلام نے بھی قواے نافذہ کے علاوہ، معاشرے کے افراد کے لئے مختلف سزائیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکرکو واجب قرار دیا ہے اور اس طرح مقابلہ کو مزید عوامی اور موثر تر بنادیا ہے۔
اسلام اور معاشرے کی دوسری روشوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسری روشیں صرف لوگوں کے افعال و اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ کرتی ہیں ، لیکن اسلام لوگوں کے افعال کے علاوہ ان کے اخلاق کی طرف بھی توجہ کرکے دونوں مرحلوں میں فساد کے ساتھ مقابلہ کرتاہے۔
جن اعمال کو اسلام نے گناہ اور معصیت کے طور پر حرام قرار دیا ہے، وہ ایسے اعمال ہیں جن سے معاشرے میں بُرے اثرات اور منحوس نتائج بر آمد ہوتے ہیں،اس توصیف کے پیش نظر ان میں سے بعض اعمال براہ راست مرتکب ہو نے والے ایک فرد یا تمام افراد کو برباد کردیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے کسی عضو میں زخم کے مانند معاشرے میں رخنہ ڈالتاہے۔ اکثر گناہ جو انسان کی بندگی کی حالت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں او رالہٰی حقوق کو ضرر پہنچاتے ہیں، ان کی بھی یہی حالت ہے، جیسے نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا و غیرہ۔
ان میں سے بعض اعمال اجتماعی زندگی کے لئے بالواسطہ خطرہ بنتے ہیں، معاشرے کے پیکر کو تباہ وبرباد کرکے رکھدیتے ہیں۔ ان کی مثال ان بیماریوں کی سی ہے جو براہ راست انسان کی زندگی سے سروکار رکھتی ہیںاور زندگی کے رشتہ کو توڑ دیتی ہیں جیسے جھوٹ بولنا اور تہمت لگانا اسلام کی نظر میں ماں باپ کے حقوق ، غیبت اور لوگوں پر تجاوز کا بھی یہی حکم ہے۔
اسلام میں گناہان کبیرہ کی عام سزا
مذکورہ بُرے اعمال ، اسلام میں گناہان کبیرہ کہے جاتے ہیں اور خدائے متعال نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر ان گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لئے عذاب کا وعدہ دیا ہے۔
اس کے علاوہ ان میں سے بعض کے بارے میں سخت سزائیںمقّرر کی ہیں۔ کلی طور پر ان گناہوںکے مرتکب لوگ (اگر ایک ہی بار بھی انجام دیں) عدل و انصاف کا خاتمہ کرتے ہیں، یعنی معاشرے کے ایک صالح عضو سے اس کی شرافت کو سلب کرتے ہیں۔
جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتاہے وہ اپنی عدالت کو کھودیتا ہے اور وہ ان اختیارات سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا، جن سے معاشرے کاایک صالح عضو بہرہ مند ہوتا ہے۔ وہ اسلامی حکومت میں کوئی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا ، خلافت کے عہدہ پر فائز نہیں ہوسکتا، امام جماعت نہیں بن سکتا ، اورکسی کے حق میں یامخالفت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اور وہ اسی حالت میں رہے گا جب تک کہ توبہ نہ کرلے او ر مسلسل تقوی و پرہیز گاری سے دوبارہ ''عدالت'' کی صفت کا مالک بن جائے۔
____________________
١۔تحف العقول ،ص٤٠٩۔
۲۔میزان الحکمة،ج٤ص٢١٣۔
۳۔میزان الحکمةج٤ص٢١٣۔
۴۔ امالی شیخ مفید، ص ٣١٠(حواشی میں آیا ہے)۔
۵۔ الغدیر،ج ١٠، ص ٣٦٨۔
۶۔میزان الحکمة ج١،ص٤٠٠۔
۷۔ اصول کافی،ج ١، ص ٣٠، ح ١۔
۸۔نہج الفصاحہ ، ص ٦٤، ج ٣٢٤، ٣٢٧۔
احکام کے بارے میں چندسبق
اجتہاد اورتقلید
انسان کی زندگی میں پائی جا نے والی حاجتیں اوران کو پوراکرنے کے لئے ان کی سرگرمیاں،اتنی زیادہ ہیں کہ ایک معمولی انسان ان کوگننے اورشمار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا،ان سب کے بارے میں اور مہارت حاصل کرکے کافی مقدار میں معلومات حاصل کرنے کی بات ہی نہیں!
دوسرے یہ کہ انسان اپنے کام کو فکروارادہ سے انجام دیتا ہے اور جہاں پر اسے کوئی فیصلہ کرنا ہو،تو اس کے بارے میں اس کے پاس کافی معلو مات ہونا چاہئے ورنہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کرسکتااس کو اپنے انجام دینے والے کاموں میں خود ماہر ہونا چاہئے یا کسی ما ہر سے پوچھے اوراس کے حکم کے مطابق اس کام کو انجام دے ۔چنانچہ فطری طورپر ہم مریضوں کاعلاج کرنے کے لئے طبیب سے،مکان کانقشہ بنانے کے سلسلہ میں انجینئرسے ،معماری میں معمارسے رجوع کرتے ہیں اور دروازے اورکھڑ کیاں بنانے میں نجّارپر اعتماد کرتے ہیں ۔
پس ہم ہمیشہ بہت کم کاموں کے علاوہ اپنے دوسرے تمام مسائل میں تقلید کرتے ہیں۔جویہ کہتا ہے کہ :''میں اپنی زندگی میں تقلید کے سامنے ہتھیارنہیں ڈالتا ہوں''وہ شخص یااپنی بات کے معنی کونہیں سمجھا ہے یاایک فکری آفت میں مبتلا ہوا ہے ۔
چونکہ اسلام نے اپنی شریعت کی بنیاد انسانی فطرت پر ڈالی ہے ، لہذااسی روش کاانتخاب کیاہے۔اسلام نے اپنے پیروئوںکو حکم دیا ہے کہ دینی معارف اوراحکام کو سیکھیںان معارف کا سر چشمہ کتاب خدااور پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآئمہ ھدی علیہم السلام کی سنت کے علاوہ کوئی اورچیز نہیںہے ۔
بدیہی ہے کہ تمام دینی معارف کو کتاب وسنت سے حاصل کرنا،ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے اوریہ کام مسلمانوں کے ایک خاص گروہ کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لئے ممکن نہیں ہے ۔
اس لئے خود بخود دین کاحکم اس صورت میں نکلتا ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جودینی معارف واحکام کواستدلال کی راہ سے حاصل نہیں کرسکتے،انھیںان لوگوںکی طرف رجوع کرنا چاہئے جودینی احکام کودلیل سے حاصل کر چکے ہوں اوراسطرح اپنے فریضہ پرعمل کریں ۔
جو عالم دینی احکام کواستدلال کی راہ سے حاصل کرتا ہے ،اس کو''مجتہد'' اور اس کے کام کو''اجتہاد''کہا جاتا ہے اورجو مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ''مقلد'' اور اس کے اس کام کو''تقلید''کہتے ہیں ۔
البتہ اس نکتہ کو جانناچاہئے کہ تقلید،عبادت،معاملات اور دین کے دوسرے عملی احکام میں جائز ہے ،لیکن اصول دین میں ،جواعتقادی مسئلہ ہے،کسی صورت میں کسی کی تقلیدنہیں کی جاسکتی ہے۔کیونکہ اصول دین میں ایمان وعقیدہ ضروری ہے نہ عمل،اس لئے دوسروں کے ایمان کواپنا ایمان فرض نہیں کیا جاسکتاہے ،یعنی یہ نہیں کہاجاسکتاہے کہ خدا ایک ہے اس دلیل پر کہ ہمارے والدین یا عالم ایسا کہتے ہیں ۔یا مرنے کے بعدزندگی حق ہے ،کیونکہ تمام مسلمان اس کا عقیدہ رکھتے ہیں ۔
اس لئے ہرمسلمان پرواجب ہے کہ اپنے اصول دین کودلیل کی راہ سے جانے اگرچہ سادہ طریقہ سے ہی ہو۔
نجاسات
نجاسات(نجس چیزیں )چند چیزیں ہیں :
١و٢:پیشاپ اورپاخانہ۔(۱)
اس حرام گوشت حیوان کاپیشاب اورپاخانہ نجس ہے جوخون جہندہ رکھتا ہویعنی وہ حیوان جس کی رگ کاٹنے پرخون اچھل کرنکلے ،جیسے:بلی ،لومڑی ،خرگوش وغیرہ ،بلکہ اگر مرغی یا کوئی دوسراحیوان ،جونجاست کھانے کی وجہ سے حرام گوشت بن چکا ہو ، تواس کا بھی پیشاب وپاخانہ نجس ہے ۔
٣۔خون جہندہ رکھنے والے حیوانوں کامردار،خواہ حلال گوشت ہوں یاحرام گوشت،لیکن حرام گوشت حیوان کے بعض اجزاء جیسے ،اون ،بال اورناخن جو جان نہیں رکھتے ہیں پاک ہیں ۔
٤۔خون جہندہ رکھنے والے حیوانوں کاخون ،خواہ حلال گوشت ہوں یاحرام گوشت۔
٥و٦۔خشکی میں رہنے والے کتے اورسور ،ان کے تمام اجزاء یہاں تک کہ ان کے بال بھی نجس ہیں ۔
٧۔شراب اورمست کرنے والی ہر سیال چیز۔
٨۔آب جو ۔
مطہّرات
(پاک کرنے والی چیزیں )
ہروہ چیز جس سے نجاست پاک کی جاتی ہے ،اسے (مطہر)کہتے ہیں اورمطہرات درج ذیل ہیں :
١۔پانی،
یہ ہرنجس ہوئی چیز کو پاک کرتا ہے،لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ پانی مطلق ہو۔اسلئے مضاف پانی،جیسے ہندوانہ اورگلاب کے پانی سے نجاست پاک نہیں ہوتی اوران سے وضوو غسل بھی صحیح نہیں ہے ۔(۲)
٢۔زمین ،
یہ جوتے کی تہ اورپائوں کے تلوے کو پاک کرتی ہے۔
٣۔آفتاب ،
یہ نجس زمین اور چٹائی وغیرہ کو اپنی گرمی سے خشک کرکے پاک کرتا ہے۔
٤۔استحالہ ،
یعنی نجس چیز اپنی جنس بدل کرایک پاک چیزکی صورت میں ظاہر ہوجائے۔جیسے کتّانمک کی کان میں گرکرنمک میں تبدیل ہو جائے۔
٥۔انتقال ،
یعنی انسان کے بدن کاخون یاخون جہندہ رکھنے والے کسی حیوان کاخون ایک ایسے حیوان کے بدن میں منتقل ہوجائے جوخون جہندہ نہ رکھتا ہو۔جیسے انسان کے بدن کاخون مچھر یامکھی وغیرہ کے بدن میں منتقل ہوجائے ۔
٦۔عین نجاست کازائل ہوجانا،
یعنی حیوان کے ظاہراور انسان کے باطن،مثلاً اگرحیوان کی پشت یاانسان کی ناک کے اندرکاحصہ خون آلود ہوجائے ،تو خون کے زائل ہونے کے بعدپاک ہوجاتا ہے اور اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔
٧۔تبعیّت،
تبعیت سے مرادیہ ہے کہ ایک نجس چیز دوسری نجس چیز کے پاک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے ،جیسے کافر کے مسلمان ہونے سے اس کافرزندباپ کی تبیعت میں پاک ہو جاتا ہے۔
٨۔کم ہونا،
یعنی انگور کاپانی ابا لنے سے نجس ہو جاتا ہے ،لیکن اگر ابالنے کے ذریعہ دو تہائی پانی بھاپ میں تبدیل ہو کرکم ہو جائے تو باقی پانی پاک ہوجاتا ہے۔
غسل
غسل دوطریقہ سے انجام دیا جاسکتا ہے :(ترتیبی اورارتماسی )
غسل ترتیبی سے مرادیہ ہے کہ سروگردن اور دائیں و بائیں طرف کوترتیب سے دھو یا جائے۔
غسل ارتماسی یہ ہے کہ انسان یکبارگی پورے بدن کو پانی میں ڈبودے۔غسل کی دوقسمیں ہیں:واجب اور مستحب ۔دین اسلام میں مستحب غسل بہت زیادہ ہیںاور واجب غسل سات ہیں :
١۔غسل جنابت
٢۔غسل میت
٣۔غسل مس میت،یعنی اگرانسان مردہ کے بدن کوسرد ہونے کے بعد اور غسل میت دینے سے پہلے مس کرے ،یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس کے بدن سے ملائے ،تواسے غسل کرنا چاہئے ۔
٤۔نذریاعہدکیا ہو یاقسم کھائی ہوکہ غسل کرے گا۔
٥۔غسل حیض
٦۔غسل نفاس
٧۔غسل استحاضہ
پہلے چارغسل مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں اورآخری تین غسل صرف عورتوں سے مخصوص ہیں ۔
شخص مجنب پر جو چیزیں حرام ہیں ،وہ حسب ذیل ہیں:
١۔اپنے بدن کے کسی حصہ کوقرآن مجید کے الفاظ،خداکے نام اور پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم وائمہ اطہار علیہم السلام کے ناموں سے مس کرنا۔
٢۔مسجد الحرام اورمسجدالنبیصلىاللهعليهوآلهوسلم میں داخل ہونا ۔
٣۔دوسری تمام مسا جد میں رُکنااورکوئی چیزان میں رکھنا ۔
٤۔قرآن مجید کے ان چار سوروں میں سے کسی ایک کی تلاوت کرنا کہ جن پر سجدہ واجب ہے۔یعنی سور ہ نجعم ،اقرائ،الم تنزیل اورحم سجدہ ۔
جنابت،حیض،نفاس اوراستحاضہ کے تمام ا حکام کوتوضیح المسائل سے حاصل کرناچاہئے ۔
نوٹ۔ غسل میں بھی وضو کی طرح نیت کرنالازم ہے اورغسل سے پہلے بدن پاک ہوناچاہئے اور بدن تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہئے ۔
____________________
١۔پیشاب نکلنے کی جگہ صرف پانی سے پاک ہوتی ہے اورپاخانہ نکلنے کی جگہ کوپانی سے دھویا جاسکتا ہے یاپتھریا اسکے مانندتین ٹکڑوں سے پاک کیا جاسکتا ہے .البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ پاخانہ اپنی جگہ سے باہر نہ پھیلا ہو ورنہ پانی کے بغیرپاک نہیں ہوگا۔ضمناًیاد دہانی کی جاتی ہے کہ اگرپاخانہ تین پتھر سے صاف نہ ہواتو اس سے زیادہ پتّھر سے پاک کیا جائے ۔
۲۔پانی کی دوقسمیں ہیں :کرُاورقلیل۔کرُپانی: بیس مثقال کم ١٢٨من تبریزی ہے ،جوتقریباً٣٨٤کلوگرام ہوتا ہے اوراگر کوئی نجاست اس سے مل جائے ،تونجس نہیں ہوتا ،قلیل پانی: وہ پانی جوکرُسے کم ہو،اگراس سے کوئی نجاست مل جائے تو وہ نجس ہوجاتا ہے اور اس کا پاک ہونا اس طرح ہے کہ جاری یابارش کے پانی سے متصل ہو جائے یااس پرایک کرُکااضافہ کیا جائے ۔
وضو اور اس کے احکام
انسان کے لئے وضوسے پہلے مسواک کرنااورکلّی کرنا مستحب ہے یعنی پاک پانی منہ میں ڈالے اورکلّی کرے ۔اس کے علاوہ استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنابھی مستحب ہے ۔
وضو کی کیفیت اوراس کے شرائط
وضومیں چہرے کوسر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک اور ہاتھوں کوکہنی سے انگلیوںکے سرے تک دھونا چاہئے اور سر کے اگلے حصہ پر اور پیروںکے اوپری حصہ پر مسح کرناچاہئے ۔وضومیں مندرجہ ذیل چیزوں کاخیال رکھنا ضروری ہے :
١۔وضوکے اعضاء پاک ہوں۔
٢۔وضوکاپانی پاک، مطلق اورمباح ہو ۔(۱)
٣۔نیت:یعنی وضوکورضا ئے الہی کے لئے انجام دیناچاہئے ،لہذا اگر ٹھنڈک حاصل کرنے یا کسی دوسرے مقصد سے وضو کرے،توصحیح نہیں ہے ۔
٤۔تر تیب :یعنی پہلے چہرہ پھردایاں ہاتھ اس کے بعد بایاں ہاتھ دھونا چاہئے، اس کے بعدسر پھر پائوں کا مسح کرناچاہئے۔
٥۔مولات:یعنی وضوکے افعال یکے بعد دیگرے انجام دے اوران کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ کسی عضوکودھونے یامسح کرنے کے وقت اس سے پہلا والاعضوخشک ہو جائے،لیکن اگروضو کے افعال پے درپے انجام پانے کے باوجودہواگرم ہونے یابدن کی گرمی وغیرہ کی وجہ سے وضوکی رطوبت خشک ہو جائے تووضوصحیح ہے ۔
نوٹ:یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کامسح سر کی کھال پر ہوبلکہ سر کے اگلے حصہ کے بالوں پربھی صحیح ہے ،لیکن اگرسر کے دوسرے حصوں کے بال اگلے حصہ پر جمع ہوئے ہوںتو پہلے انھیںہٹاناچاہئے اوراگر سر کے اگلے حصہ کے بال اس قدر لمبے ہوں کہ کنگھی کرنے سے چہرے پر آئیں تواس صورت میں بالوں کی جڑپر مسح کرناچاہئے یامانگ نکال کرکھال پرمسح کرناچاہئے ۔
مبطلات وضو
جوچیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں انھیں ''مبطلات''کہتے ہیں اور وہ آٹھ ہیں:
١۔پیشاب
٢۔پاخانہ
٣۔ریاح(یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہوا پاخانہ کے مقام سے خارج ہو یابیماری اور آپریشن کی وجہ سے،مخرج دوسری جگہ ہو گیا ہو)
٤۔بیہوشی
٥۔مستی
٦۔وہ نیند،جس میں آنکھیں نہ دیکھ سکیں اورکان نہ سن سکیں ،اس بناپراگرآنکھیں نہ دیکھیں لیکن کان سنیںتووضوباطل نہیںہوتاہے۔
٧۔دیوانگی
٨۔جنابت اور وہ اسباب جن کے لئے غسل کیا جاتا ہے نیزاستحاضہ جسے عورتیںبعض اوقات دیکھتی ہیں،وضوکو باطل کرتا ہے ۔
تیمم
اگرانسان وقت کی تنگی،بیماری یا پانی نہ ہونے یااسی طرح کی کسی اورچیز کی وجہ سے نمازاور اس کے ماننددوسرے اعمال کے لئے وضو یاغسل نہ کرسکے تو اسے تیمم کرناچاہئے۔
تیمم کا طریقہ
تیمم میں چار چیزیں واجب ہیں :
١۔نیت
٢۔دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مٹی یا اس چیز پر مارنا جس پر تیمم کرنا صحیح ہے۔
٣۔دونوں ہاتھو ںکی ہتھیلیوںکو سر کے بال اگنے کی جگہ سے بھوئوں اور ناک کے اوپر پوری پیشانی پر پھیرنا ۔بہتر ہے کہ ہاتھوں کوبھوئوں پر بھی پھیرا جائے ۔
٤۔بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پوری پشت پراور اس کے بعددائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پوری پشت پر کھینچنا ۔
وضو کے بدلے کئے جا نے والے تیمم میں اتنی ہی مقدارکافی ہے لیکن اگر تیمم غسل کے بدلے ہو ،توایک بار پھر ہاتھوں کو زمین پر مار کر صرف ہاتھوں کی پشت پر مسح کرے ۔
تیمم کے احکام
١۔اگر مٹی نہ ملے تو ریت پر، اوراگر ریت نہ ملے تو ڈھیلے پر ،اوراگر وہ بھی نہ ملے تو پتھر پر تیمم کرنا چاہئے اور جب ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ملے تو کہیں پر جمع ہوئی گردوغبار پر تیمم کرنا چاہئے ۔
٢۔چونے اور دوسری معدنی چیزوں پرتیمم کرنا صحیح ہے ۔
٣۔اگر پانی کو مہنگا بیچاجارہا ہو،لیکن انسان اسے خرید سکتا ہوتو تیمم نہیں کرسکتا ہے بلکہ اسے پانی خرید کروضواورغسل کرنا چاہئے ۔
____________________
١۔یعنی پانی انسان کااپناہوناچاہئے یااس کامالک اس سے وضوکرنے پرراضی ہو۔
نماز
خدائے متعال فرماتا ہے :
( ماسلککم فی سقر،قالوا لم نک من المصلّین )
(مدثر٤٣٤٢)
''جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گاآخرتمھیں کس چیز نے جہنم میں پہنچادیا ہے ؟تووہ کہیں گے ہم نمازگزارنہیں تھے ۔''
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
''نماز دین کاستون ہے ،اگر بارگاہ الہٰی میں یہ قبول ہو جائے گی تودوسری عبادتیں بھی قبول ہوں گی اوراگر یہ قبول نہ ہوئی ،تودوسری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی''
جس طرح ایک انسان ،دن رات میں پانچ بارایک نہر میں نہائے تواس کے بدن میں کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا ،اسی طرح پانچ وقت کی نمازیں بھی انسان کوگناہوں سے پاک کرتی ہیں ،جاننا چاہئے کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن اسے اہمیت نہیں دیتا،وہ اس شخص کے مانندہے ،جو اصلاًنمازنہیں پڑھتا ہے ۔خدائے متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے :
( فویل للمصلّین،الّذین هم عن صلاتهم ساهون ) (ماعون ٥٤)
''تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے جواپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔''
ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے ،اور دیکھاکہ ایک شخص نمازپڑھ رہا ہے ،لیکن رکوع وسجود کو مکمل طورپر بجا نہیں لارہا ہے،آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
''یہ شخص جس طرح نماز پڑھ رہا ہے اگر اسی حالت میں اس دنیا سے گزر گیا تو مسلمان کی حیثیت سے دنیاسے نہیں گیا ہے ۔''
اس بناپرنما ز کو خضوع و خشوع کی حالت میں پڑھنا چاہئے اور نماز پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ کس ذات سے محو گفتگوہے او ر رکوع و سجود اور دوسرے تمام اعمال کو صحیح طور پر انجام دے تا کہ نماز کے عالی نتائج سے بہرہ مند ہوجائے۔ خدائے متعال قرآن مجید میں نماز کے بارے میں فرماتاہے:
( انَّ الصَّلوة تنهیٰ عن الفحشاء و المنکر ) ...) (عنکبوت٤٥)
''...نماز ہر برائی اور بدکار ی سے روکتی ہے...''
یقینا ایسا ہی ہے، کیونکہ نماز کے آداب اس طرح ہیں کہ اگر نماز گزاران کا لحاظ رکھے تو کبھی برائی کے پیچھے نہیں جائے گا۔ مثلا آداب نماز میں سے ایک یہ ہے کہ نماز گزار کی جگہ او رلباس غصبی نہ ہوں، اگر اس کے لباس میں حتی ایک دھاگابھی غصبی ہو تواس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو جو نماز گزار اس حد تک حرام سے پرہیز کرنے پر مجبور ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ حرام مال کو استعمال کرے یاکسی کا حق ضائع کرے!
نیز نماز اس صورت میں قبول ہوتی ہے کہ انسان ، حرص، حسد اور دوسری بری صفتوں سے دور رہے اور مسلّم ہے کہ تمام برائیوں کا سرچشمہ یہی بری اور ناشائستہ صفتیں ہیں اورنماز ی جب اپنے آپ کو ان صفتوں سے دور رکھے گا، تووہ یقینا تمام برائیوں سے دور رہے گا۔
اگر بعض لو گ نماز پڑھنے کے با وجود ناپسند کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کاسبب یہ ہے کہ وہ نماز کے ضروری احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے اور نتیجہ میں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ اس کے عالی نتائج سے محروم رہتے ہیں۔
دین اسلام کے شارع مقدس نے نمازکو اس قدر اہمیت دی ہے کہ ، ہر حال میں حتی جان کنی کی حالت میں بھی انسان پر نماز کو واجب قرار دیا ہے، اگر وہ نماز کو زبان پر جاری نہیں کرسکتا ہے تو دل پرجاری کرنا چاہئے او راگر جنگ ، دشمن کے خوف یا اضطرار اور مجبور ی کی وجہ سے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے لئے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنا واجب نہیں ہے اور جس طرف بھی ممکن ہو نماز پڑھے۔
واجب نمازیں
واجب نمازیں چھ ہیں:
١۔ پنجگانہ نمازیں(۱)
٢۔ نماز آیات
٣۔ نماز میت
٤۔ واجب طواف کی نماز
٥۔ ماں باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پرو اجب ہوتی ہیں۔
٦۔ وہ نمازیں جو اجارہ، نذر، قسم اور عہد کی وجہ سے واجب ہوتی ہیں۔
مقدمات نماز
نماز بجالانے، یعنی پروردگار عالم کی خدمت میں حاضر ہونے اور ذات مقدس الہٰی کی اظہار بندگی او رپرستش ، کے لئے کچھ مقدمات ضروری ہیں ۔ جب تک یہ مقدما ت فراہم نہ ہو جائیں نماز صحیح نہیں ہے اور یہ مقدمات حسب ذیل ہیں:
١۔ طہارت
٢۔ وقت
٣۔ لباس
٤۔ مکان
٥۔ قبلہ
ان مقدمات کی تفصیل درج ذیل ہے:
١۔ طہارت
نماز ی کونماز کی حالت میں با طہارت ہوناچاہئے، اپنے فریضہ کے مطابق نماز کو با وضو یا غسل یا تیمم کے ذریعہ بجالائے اور اس کا بدن ا ور لباس نجاست سے آلودہ نہ ہوں۔
٢۔ وقت
نماز ظہر و عصر میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص وقت او ر مشترک وقت ہے، نماز ظہر کا مخصوص وقت اول ظہر(۲) سے نماز ظہر پڑھنے کا وقت گزرنے تک ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں سہواً بھی نماز عصر پڑھے، تو اس کی نماز باطل ہے۔
نماز عصر کا مخصوص وقت، اس وقت ہوتا ہے جب مغرب سے پہلے صرف نماز عصر پڑھنے کے برابر وقت بچاہو۔ اگر کسی نے اس وقت تک ظہر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اس کی نماز ظہر قضا ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز ظہر کے مخصوص وقت اور نماز عصر کے مخصوص وقت کے درمیان کا وقت نماز ظہر وعصر کامشترک وقت ہے ۔اگر کوئی شخص غلطی سے اس و قت کے اندر نماز عصر کو نماز ظہرسے پہلے پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے ظہر کی نماز اس کے بعد پڑھنی چاہئے۔
نماز مغرب کا مخصوص وقت(۳) اول مغرب سے تین رکعت نماز پڑھنے کے وقت کے برابر ہے۔نمازعشاکا مخصوص وقت وہ وقت ہے جب نصف شب(۴) سے پہلے نمازعشاپڑھنے کے برابر وقت بچا ہو ۔اگرکسی نے اس وقت تک نماز مغرب نہیں پڑھی ہے تو اسے پہلے نماز عشا پڑھنی چاہئے پھر اس کے بعدنماز مغرب پڑھے۔
نماز مغرب کے مخصوص وقت اور نماز عشاء کے مخصوص وقت کے درمیان نماز مغرب و عشا کا مشترک وقت ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں غلطی سے نماز مغرب سے پہلے نماز عشا کو پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے نماز مغرب کو اس کے بعد بجالاناچاہئے۔
نماز صبح کا وقت اول فجر(۵) صادق سے سورج نکلنے تک ہے۔
٣۔ لباس
نمازی کے لباس میں چند چیزیں شرط ہیں:
١۔ لباس مباح ہو، یعنی نمازی کا اپنا لباس ہو یا اگر اپنا لباس نہ ہو تو اس لباس کا مالک اس میں نماز پڑھنے پر راضی ہو۔
٢۔ لباس نجس نہ ہو۔ ٣۔ مردار کی کھال کا نہ ہو، خواہ حلال گوشت حیوان کی کھال ہو یا حرام گوشت کی۔
٤۔ حرام گوشت حیوان کے اون یا بالوں کا نہ ہو۔ لیکن سمور کے کھال سے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔
٥۔ اگر نماز ی مرد ہے تو ریشمی اور زرباف لباس نہیں ہونا چاہئے اور خود کو بھی سونے سے زینت نہ کرے۔ نمازکے علاوہ بھی مر دوں کے لئے ریشمی لباس پہننا او رسونے سے زینت کرناحرام ہے۔
٤۔مکان
نمازی کے مکان۔ یعنی وہ جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے۔ کے کچھ شرائط ہیں:
١۔ مباح ہو۔
٢۔ ساکن ہو۔ اگر ایک ایسی جگہ جو متحرک ہو، جیسے گاڑی میں اور متحرک کشتی میں نماز پڑھنے پر مجبور ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ گاڑی وغیرہ قبلہ کے مخالف سمت میں چل رہی ہوں تو نماز ی کو قبلہ کی طرف گھومنا چاہئے۔
٣۔ اگر مکان نجس ہو تو اس قدر ترنہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز ی کے بدن یا لباس تک پہنچ جائے۔ لیکن پیشانی رکھنے کی جگہ اگر نجس ہو تو خشک ہونے کی صورت میں بھی نماز باطل ہے۔
٤۔ پیشانی رکھنے کی جگہ گھٹنوں کی جگہ سے ، ملی ہوئی چار انگلیوں سے زیادہ پست یا بلند نہیں ہونی چاہئے۔
٥۔ قبلہ
خانہ کعبہ ،جو مکہ مکرمہ میں ہے، قبلہ ہے اور اسی کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنی چاہئے۔ البتہ جو لوگ دور ہیں وہ اگر اس طرح کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں کہ کہا جائے کہ قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے ہیں ، تو کافی ہے، اسی طرح دوسری چیزیں جیسے حیوانات کا ذبح کرنا بھی قبلہ کی طرف رخ کرکے انجام دیا جاناچاہئے۔
جو شخص بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے دائیں پہلو پر ایسے لیٹ کرنماز پڑھنا چاہئے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلہ کی طرف ہو،اور اگر ممکن نہ ہو تو بائیں پہلو پر اس طرح لیٹے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلہ کی طرف ہواور اگریہ بھی ممکن نہ ہو تو اسے پشت پر اس طرح لیٹنا چاہئے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ کی طرف ہوں۔ اگر انسان تحقیق کے بعد نہ سمجھ سکے کہ قبلہ کس طرف ہے تو اسے مسلمانوں کے محرابوں ، قبروں یا دوسرے راستوں سے پیدا ہوئے گمان کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔
واجبات نماز
واجبات نماز یعنی وہ چیزیں جو نماز میں واجب ہیں، گیارہ ہیں:
١۔ نیت
٢۔ تکبیرة الاحرام
٣۔ قیام
٤۔ قرات
٥۔ رکوع
٦۔ سجود
٧۔ تشہد
٨۔ سلام
٩۔ ترتیب، یعنی نماز کے اجزاء کو معین شدہ دستور کے مطابق پڑھے، آگے پیچھے نہ کرے۔
١٠۔ طمانیت، یعنی نماز کو وقار اور آرام سے پڑھے۔
١١۔ موالات: یعنی نماز کے اجزاء کو پے در پے بجالائے اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ڈالے۔
مذکورہ گیارہ چیزوں میں سے پانچ چیزیں ارکان ہیں کہ اگر عمداً یا سہواً کم و زیاد ہو جائیں، تو نماز باطل ہے اور باقی چیزیں رکن نہیں ہیں، صرف اس صو رت میں نماز باطل ہوگی کہ ان میں عمداً کمی وزیاد تی کی جائے۔
ارکان نماز
ارکان نماز حسب ذیل ہیں:
١۔ نیت
٢۔ تکبیرة الاحرام
٣۔ قیام ۔ تکبیرة الاحرام کے وقت پر قیام اور متصل بہ رکوع
٤۔رکوع
٥۔دوسجدے
١۔نیت
''نیت''سے مراد یہ ہے کہ انسان نماز کو قصد قربت سے، یعنی خدائے متعال کے حکم کو بجا لانے کے لئے انجام دے ۔ضروری نہیں ہے کہ نیت کو دل سے گزارے یا مثلاًزبان سے کہے :
'' میں چار رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربةً الی اللّہ ''
٢۔تکبیر ة الاحرام
اذان واقامت کہنے کے بعد، نیت کے ساتھ''اللّٰہ اکبر''کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے اور چونکہ اس تکبیر کے کہنے سے کچھ چیزیں جیسے کھانا،پینا ،ہنسنااور قبلہ کی طرف پشت کرنا،حرام ہو جاتی ہیں،اس لئے اسے تکبیرةالاحرام کہتے ہیں۔اور مستحب ہے کہ تکبیرةالاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو بلندکریں،اس عمل سے خدائے متعال کی بزرگی کو مدنظر رکھ کر غیر خدا کو حقیرسمجھ کر چھوڑ دیں ۔
٣۔قیام
تکبیرة الاحرام کہتے وقت میں قیام اورقیام متصل بہ رکوع ،رکن ہے ،لیکن حمد اورسورہ پڑھتے وقت قیام اور رکوع کے بعدوالا قیام رکن نہیں ہے .اس بناء پر اگر کوئی شخص رکوع کو بھول جائے اور سجدے میں پہنچنے سے پہلے اسے یاد آجائے اسے کھڑاہونے کے بعدرکوع میں جانا چاہئے ، لیکن اگرجھکے ہوئے رکوع کی حالت میں ہی سجدہ کی طرف پلٹے،تو چونکہ قیام متصل بہ رکوع انجام نہں پایا ہے اس لئے اسکی نماز باطل ہے ۔
٤۔رکو ع
نمازی کو قرائت کے بعداس قدر جھکنا چاہئے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور اس عمل کو رکوع کہتے ہیں ۔رکوع میں ایک مرتبہ ''سبحان ربّی العظیم وبحمدہ ''یا تین مرتبہ'' سبحان اللہ'' کہنا چاہئے ۔رکوع کے بعدمکمل طور پر کھڑا ہونا چاہئے اس کے بعدسجدے میں جانا چاہئے ۔
٥۔سجدہ
''سجدہ'' یہ ہے کہ پیشانی ،دونوں ہتھیلیاں ،دونوں گھٹنے اور دونوں پائوں کے انگوٹھوں کے سرے کو زمین پر رکھے اورایک مرتبہ'' سبحان ربّی الاعلی و بحمدہ '' یا'' سبحان اللّہ'' تین مرتبہ پڑھے۔اس کے بعد بیٹھے اورسجدہ میں جاکر مذکورہ ذکر پڑ ھے۔
جس چیزپرپیشانی رکھتاہے وہ زمین یازمین سے اگنے والی چیز ہونی چاہئے،کھانے پینے،پوشاک اورمعدنی چیزوں پر سجدہ جائز نہیں ہے ۔
تشہد وسلام
اگرنمازدورکعتی ہے، تو دو سجدے بجالانے کے بعد کھڑا ہو جائے اور حمد و سورہ کے بعد قنوت(۶) بجالائے پھر رکوع اور دو سجدوں کے بعد تشہد(۷) پڑ ھے پھر سلام(۸) پڑھ کر نماز تمام کرے۔
اگر نماز تین رکعتی ہوتو تشہد کے بعد اٹھے اور صرف ایک بار حمدیا تین مرتبہ سبحان اللّہ و الحمد لِلّٰہ و لا الہ اِلاَّ اللّٰہ و اللّٰہ اکبر پڑھے، پھر رکوع ، دو سجدے، تشہد اور سلام پڑھے۔
اور اگر نماز چار رکعتی ہے تو چو تھی رکعت کو تیسری رکعت کی طرح بجالا کر، تشہد کے بعد سلام پڑھے ۔
____________________
۱۔ یومیہ نمازوں سے مراد: صبح کی دو رکعتیں، ظہر و عصر کی چار چار رکعتیں، مغرب کی تین رکعتیں اور عشا کی چاررکعتیں ہیں۔
۲۔ اگر ایک لکڑی یا اس کے مانند کوئی چیز سیدھی زمین میں نصب کی جائے تو، سورج چڑھنے پر اس کا سایہ مغرب کی طرف پڑے گا جس قدر سورج او پرچڑھے گا، یہ سایہ کم ہوتاجائے گا اور اول ظہر میں اس کی کمی آخری مرحلہ پر پہنچ جائے گی، جب ظہر کا وقت گزرے گا تو سایہ مشرق کی طرف پلٹ جاتا ہے او رسورج جس قدر مغرب کی طرف بڑھے گا سایہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ اس بنا پر جب سایہ کم ہوتے ہوئے کمی کے آخری درجہ پر پہنچ جائے اور پھرسے بڑھنا شروع ہوجائے تو معلوم ہو تاہے کہ ظہر کا وقت ہے۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض شہروں جیسے مکہ مکرمہ میں ظہر کے وقت سایہ بالکل غائب ہوتاہے، ایسے شہروں میں سایہ کے دوبارہ نمودار ہونے پر ظہر کا وقت ہوتاہے۔
۳۔ سورج ڈوبنے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد مغرب ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد مشرق کی طرف رونماہونے والی سرخی غائب ہو جائے۔
۴۔ نصف شب ،شرعی ظہر کے بعدگیارہ گھنٹے اور پندرہ منٹ گزرنے کے بعد ہو تی ہے۔
۵۔ فجر کی اذان کے قریب مشرق کی طرف ایک سفیدی اوپر کی طرف بڑھتی ہے اسے فجر اول یا فجر کاذب کہتے ہیں۔ جب یہ سفیدی پھیل جاتی ہے، تو فجر دوم یعنی فجر صادق ہے اور صبح کی اذان کا وقت ہے ۔
۶۔ حمد وسورہ کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے کے روبرو بلند کرکے قنوت میں جو بھی ذکر چاہے کہے، مثلاً :''ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار''
۷۔ تشہد سے مراد یہ ہے کہ ان جملات کو کہے :''اشهد ان لا اله الا الله و حده لا شریک له واشهد ان محمد اً عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد''
۸۔ سلام کو اسطرح بجالائے:السلام علیک ایّها النَّبی و رحمة اللّٰه و برکاته، السَّلام علیناو علی عباد اللّٰه الصّالحین، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته .
نماز آیات
چارچیزوں کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے:
١۔ سورج گہن
٢۔ چاندگہن۔ چاہے کچھ حصے کو گہن لگا ہواو رکوئی اس سے خوفزدہ بھی نہ ہو۔
٣۔ زلزلہ۔ اگر چہ کوئی نہ ڈرے۔
٤۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اور سیاہ وسرخ آندھی وغیرہ، اس صورت میں کہ اکثر لوگ ڈر جائیں۔
نماز آیات پڑھنے کا طریقہ
نماز آیات دو رکعت ہے اور ہر رکعت میں پانچ رکوع ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کے بعد تکبیر کہے اور حمد او رایک مکمل سورہ پڑھے پھر رکوع میں جائے، پھر رکوع سے کھڑا ہوجائے، اور دوبارہ حمد اور ایک سورہ پڑھے پھر رکوع بجالائے یہاں تک کہ پانچ مرتبہ رکوع بجالائے اور پانچویں رکوع سے اٹھنے کے بعد دو سجدے بجالائے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت کو پہلی رکعت کے مانند بجالاکر تشہد اور سلام کے بعد نماز تمام کرے۔
نماز آیات کا دوسرا طریقہ :
انسان نیت اور تکبیر اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد ایک سورہ کی آیات کو پانچ حصوں میں تقسیم کرکے اس کے ایک حصہ کو پڑھ کررکوع میں جائے، رکوع سے اٹھ کر سورہ حمد پڑھے بغیر سورہ کا دوسرا حصہ پڑھے اور پھر رکوع بجالائے اور اسی طرح پانچویں رکوع سے پہلے سورہ کو ختم کرکے پھر رکوع بجالائے اس کے بعد دوسجدے بجالائے پھر دوسری رکعت کو پہلی رکعت کے مانند بجالاکے نماز کو ختم کرے۔
مسافر کی نماز
مسافر کو چھ شرائط کے ساتھ چاررکعتی نماز کو دو رکعت پڑھنا چاہئے:
١۔ اس کا سفر آٹھ فرسخ سے کم نہ ہو یا چار فرسخ جائے او رچارفرسخ واپس آئے۔
٢۔ ابتداء سے آٹھ فرسخ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔
٣۔ راستہ میں اپنے قصد کو نہ توڑے۔
٤۔ اس کا سفر گناہ کے لئے نہ ہو۔
٥۔ سفر اس کاپیشہ نہ ہو۔
پس اگر کسی کا پیشہ سفر ہو ( جیسے ڈرائیور) تو اسے نماز پوری پڑھنی چاہئے مگر یہ کہ دس روز اپنے گھر میں رہے، تو اس صورت میں تین با ر سفر کر نے پر نماز قصر پڑھے۔
٦۔ حد ترخص تک پہنچ جائے، یعنی اپنے وطن یادس دن تک قیام کی جگہ سے اس قدر دورچلاجائے کہ شہر کی دیواروں کونہ دیکھ سکے او راس شہر کی اذان کونہ سن سکے۔
نماز جماعت
مستحب ہے کہ مسلمان پنجگانہ نمازوں کو جماعت کی صورت میں پڑھے اور نماز جماعت کا ثواب فرادیٰ پڑھی جانے والی نماز کے کئی ہزار گناہے۔
نماز جماعت کی شرائط
١۔ امام جماعت بالغ، مؤمن، عادل اور حلال زادہ ہوناچاہئے ، نماز کو صحیح پڑھتاہو اور اگر ماموم مرد ہے تو امام کو بھی مرد ہوناچاہئے۔
٢۔ امام اور ماموم کے درمیان پردہ یا کوئی اور چیزحائل نہ ہو جو امام کو دیکھنے میں رکاوٹ بنے، لیکن اگر ماموم عورت ہو تو اس صورت میں پردہ یا اس کے مانند کسی چیز کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
٣۔ اما م کی جگہ ماموم کی جگہ سے بلندنہ ہو، لیکن اگر بہت کم (چارانگلیوں کے برابر یا اس سے کم ) بلند ہو تو کوہی حرج نہیں ہے۔
٤۔ ماموم کو اما م سے تھوڑا پیچھے یا اس کے برابر ہوناچاہئے۔
نماز جماعت کے احکام
١۔ ماموم حمد و سورہ کے علاوہ ساری چیزیں خود پڑھے، لیکن اگراس کی پہلی یادوسری رکعت ہو اور امام کی تیسری یا چوتھی رکعت ہوتو اسے حمد و سورہ کوبھی پڑھنا چاہئے اور اگرسورہ پڑھنے کی وجہ سے امام کے ساتھ رکوع میں نہ پہنچ سکے تو صرف حمد پڑھ کر خود کو رکوع میں امام کے ساتھ پہنچادے اور اگر نہ پہنچ سکاتو نماز کو فرادی کی نیت سے پڑھے۔
٢۔ ماموم کو رکوع، سجود اور نماز کے دوسرے افعال امام کے ساتھ یا اس سے تھوڑابعد انجام دینا چاہئے،لیکن تکبیرة الاحرام کو قطعاً امام کے بعد کہے۔
٣۔ اگر امام رکوع میں ہو اور اس کی اقتد ا ء کرے اور رکوع میں پہنچ جائے، تو اس کی نماز صحیح ہے اور ایک رکعت حساب ہوگی۔
روزہ
دین مقدس اسلام کے فروع دین میں سے ایک ''روزہ'' ہے۔ ہرمکلف پر واجب ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھے ۔یعنی پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے صبح کی اذان سے مغرب تک ،روزہ کو باطل کرنے والی چیزوں (مفطرات روزہ) سے پرہیز کرے۔
روزہ کو باطل کرنے والی چیزیں
چند چیزیں روزہ کو باطل کرتی ہیں ،وہ حسب ذیل ہیں :
١۔کھانااورپینا،اگرچہ اس چیز کاکھانااورپینا معمول نہ ہو،جیسے مٹی اور درخت رس۔
٢۔خدا،رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم اورآپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے جانشینوں (ائمہ ھدی) کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا۔
٣۔غلیظ غبار کوحلق تک پہنچانا ۔
٤۔پورے سر کوپانی میں ڈبودینا ۔
٥۔قے کرنااگرعمداً ہو۔
دوسرے مفطرات روزہ کے بارے میں مراجع کی توضیح المسائل کی طرف رجوع کیا جائے۔
اسلام میں جہاد
جہاد کے کلی مسائل
ہرمخلوق کا اپنی ذات کادفاع کرنا اوراسی طرح اپنے منافع کادفاع کرناایک عام قانون ہے جوعالم خلقت میں بلا چون وچراثابت ہے۔
انسان بھی اپنی حیثیت سے اپنی ہستی اور منافع کادفاع کرتا ہے اوردوسروں کے ماننددفاع کی توانائیوں سے مسلح ہے تاکہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرسکے ۔انسان اپنی خدادادجبّلت اورفطرت سے قائل ہے کہ اسے اپنادفاع کرناچاہئے اوراپنے اس دشمن کونابودکرد ینا چاہے جوکسی بھی وسیلہ سے اس کو نابود کرنے سے باز نہیں آرہا ہے۔اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے حیاتی منافع پرقبضہ کرنا چاہے تواسے دفاع کی غرض سے اٹھنا چاہئے اور ہر ممکن طریقے سے اس کو روکنا چاہئے ۔
یہ فطری موضوع جوایک انسان کی فطرت میں ثابت اورپائدارہے ،اسی طرح انسانی معاشروں میں بھی ثابت ومستحکم ہے۔یعنی جودشمن معاشرے کے افراد یامعاشرے کی آزادی کے لئے خطرہ ہو،وہ اس معاشرے کی نظرمیں سزائے موت کا مستحق ہے اور جب سے انسان اور انسانی معاشرے ہیں یہ فکران میں ثابت اوربرقرار ہے کہ ہرفرداورمعاشرہ اپنے جانی دشمن کے بارے میں ہرقسم کا فیصلہ کرسکتا ہے اورردعمل دکھا سکتا ہے ۔
اسلام بھی ۔جوایک اجتماعی دین ہے اور توحید کی بنیاد پر استوار ہے ۔حق اور عدالت کے سامنے تسلیم نہ ہونے والوں کواپنا جانی دشمن جانتا ہے اورانھیں نظام بشریت میں مخل جان کران کے لئے کسی قسم کی قدر وقیمت اوراحترام کا قائل نہیں ہے اور چونکہ خود کو عالمی دین جانتا ہے اس لئے اپنے پیروئوں کے لئے کسی ملک اور سرحدوں کی محدودیت کا قائل نہیںہے اور جو بھی شرک کے عقیدہ میں مبتلا ہو اور واضح منطق اور حکیمانہ پند و نصیحت کو قبول نہ کرتا ہو اور حق اوراحکام الہیٰ کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا ہو ،تو اسلام اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے تاکہ وہ حق وعدالت کے سامنے ہتھیار ڈال دے ۔
مختصر یہ کہ جہاد کے سلسلہ میں اسلام کے قوانین بھی یہی ہیں اور وہ مکمل طور پراس روش کے مطابق ہیں جوہرانسانی معاشرہ کی اپنی فطرت کے مطابق اپنے جانی دشمنوں کے بارے میں ہے ۔
اسلام ،بدخواہ دشمنوں کے پروپیگنڈوں کے باوجود،تلوار کا دین نہیں ہے،کیونکہ اسلام کی روش سلاطین کی روش نہیں ہے کہ جن کی دلیل ومنطق صرف تلواراورسیاسی حربے ہوتے ہیں ، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے،جس کابانی خدائے متعال ہے ،جواپنے آسمانی کلام میں لوگوں کے ساتھ منطق وعقل کی بنیاد پر بات کرتا ہے اوراپنی مخلوقات کو اس دین کی طرف دعوت دیتا ہے جوان کی فطرت کے مطابق ہے۔
جس دین کی عمومی تحےّت،سلام ہواور اس کا عمومی پروگرام قرآن مجید کے نص کے مطابق''والصلح خیر''(۱) ہو،وہ ہرگز تلوارکا دین نہیں ہوسکتا۔
پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ،جب اسلام کی نورانیت نے تمام حجازکو منور کررکھاتھا اور مسلمان اہم جنگوں اورسخت مقابلوں میں مبتلا تھے ، تو اس وقت قتل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد دوسوسے زیادہ نہ تھی اور قتل ہونے والے کفار کی تعداد ایک ہزارتک نہیں پہنچی تھی ۔کتنی بے انصافی ہے کہ ایسے دین کوتلوارکادین کہا جائے ۔
اسلام میں جنگ کے مواقع
اسلام ،جن کے ساتھ جنگ کرتا ہے ،وہ حسب ذیل چند گروہ ہیں :
١۔مشرکین :
مشرکین یعنی وہ لوگ جو توحید،نبوت اورمعاد کے قائل نہیں ہیں ۔ان کو پہلے اسلام لانے کی دعوت دیتا ہے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ اور بہانہ باقی نہ رہے،دین کے حقائق کو ان کیلئے واضح کرکے تشریح کرتا ہے ،پس اگرانہوں نے قبول کیا تودوسرے مسلمانوں کے بھائی اور نفع ونقصان میں برا بر ہوںگے ،اور اگر قبول نہ کیا اور حق وحقیقت کے واضح ہونے کے باوجودتسلیم نہ ہوئے تو اسلام ان کے مقابلہ میں اپنادینی فریضہ''جہاد''کو انجام دیتا ہے ۔
٢۔اہل کتاب:
اہل کتاب''یہود ،عیسائی اورمجوسی ہیں''اسلام ان کوصاحب دین اورصاحب کتاب آسمانی جانتا ہے۔یہ لوگ توحید ، نبو ت مطلقہ اورمعاد کے قائل ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی مشرکین جیسا سلوک کرنا چاہئے ،لیکن چونکہ اصل توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں ،لہذاجز یہ ادا کرکے اسلام کی پناہ میں آسکتے ہیں ،یعنی اسلام کی سرپرستی کو قبول کریں اوراپنی آزادی کی حفاظت کریں اوراپنے دینی احکام پر عمل کر یں ۔تو دوسرے مسلمانوں کی طرح ان کی جان ،مال اورعزت محترم ہوگی اور اسکے عوض میں اسلامی معاشر ہ کوکچھ مال ادا کریں گے ،لیکن ان کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے،دین کے دشمنوں کی مدد اوردوسرے ایسے کام انجام نہیں دینا چاہئے جو مسلمانوں کے نقصان میں ہو ۔
٣۔بغاوت اورفساد برپا کرنے والے :
بغاوت اور فسار برپا کرنے والے یعنی وہ مسلمان جواسلام ومسلمین کے خلاف مسلحانہ بغاوت کرکے خونریزی کریں ،اسلامی معاشرہ ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے تاکہ وہ ہتھیارڈال کرفساد اوربغاوت سے ہاتھ کھینچ لیں ۔
٤۔دین کے دشمن:
دین کے دشمن جودین کی بنیاد کو ویران کرنے یاحکومت اسلامی کو نابودکرنے کے لئے حملہ کریں ،تو تمام مسلمانوں پرواجب ہے کہ دفاع کریں اوران کے ساتھ کافرحربی کاسلوک کریں ۔
اگراسلام ا ورمسلمین کی مصلحت کاتقاضاہو تواسلامی معاشرہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ و قتی طور پر جنگ بندی کا معاہدہ کرسکتا ہے ،لیکن یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا دوستانہ رابطہ برقرار کرے کہ ان کے گفتاروکردارمسلمانوں کے افکارواعمال پر منفی اثرڈال کرانھیں خراب کر دیں ۔
جہاد کے بارے میں اسلام کا عام طریقہ
اسلامی معاشرہ پر فرض ہے کہ اگر جہادکے شرائط موجودہوں تو،اُن کفارسے راہ خدا میں جنگ کریں جن کی سرحد ملی ہوئی ہے، اورہرمسلمان بالغ،عاقل،صحت منداورجس کے ہاتھ پائوں اورآنکھ صحیح و سالم نہ ہوں،پرجہادواجب کفائی ہے۔
اسلام کے لشکرپر فرض ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ پر آئے ،تودینی حقائق کو ان کے لئے اس طرح بیان اورواضح کرے کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے اوران کو حق کی طرف دعوت دے اورصرف اس صورت میں جنگ کا اقدام کرے کہ حق کے واضح ہونے کے بعدبھی وہ دین کوقبول نہ کریں ۔
اسلام کے سپاہی کو دشمنوں پرپانی بندنہیں کرنا چاہئے اوردشمن پر شب خون نہیں مارناچاہئے دشمن کی عورتوں ،بچوں ،ناتواں بوڑھوں اوردفاع کی قدرت نہ رکھنے والوں کو قتل نہیں کرناچاہئے ،دشمن کے برابر یادوگنا ہونے کی صورت میں میدان جنگ سے فرارنہ کرے۔
اگرہم اسلام کے جنگی طریقہ کو ترقی یافتہ ملتوںکے جنگی طریقوںسے مواز نہ کریں، جوہرخشک وتر کوجلادیتے ہیں اورکسی کمزوراوربیچارہ کے حال پررحم نہیںکرتے،تو واضح ہو جائے گا کہ اسلام کس قدرانسانیت کے اصول کاپابند ہے ۔
حکومت،قضاوت اورجہاد کیوں مردوں سے مخصوص ہے ؟
معاشرے کے حساس ترین اجتماعی امور کہ ،جن کی باگ ڈورصرف عقل واستدلال کے سپردکی جانی چاہئے اوران میں جذبات واحساسات کی کسی صورت میں مداخلت نہیں ہونی چاہئے ، وہ حکومت،قضاوت اور جنگ کے شعبے ہیں ۔ کیوںکہ مملکت کے امور کو چلانے اور ،معاشرے میں پیداہونے والی دشمنیوں کو حل کرنے میں ہزاروں ناقابل برداشت واقعات اور طرح طرح کی چہ می گوئیوں اور جان ، مال،عزت و ابرو کی دھمکیوں جیسے گوناگوں مسائل سے دوچار ہوناپڑتا ہے کہ جس کو نہایت قوی اور مستقل مزاج افراد کے علاوہ کوئی طاقت برداشت نہیں کرسکتی کہ اوران تمام مسائل سے چشم پوشی کرکے صبر نہیں کیا جاسکتاہے،اورگوناگوںمخالفتوں کے درمیان اجتماعی عدالت کو نافذنہیں کیا جاسکتا ہے ،جو اس عہدہ کاحامل ہو اسے دوست ودشمن ،برُے اوربھلے،چاپلوس اوربد گو ئی کرنے والے اورعالم وجاہل کوایک نظرسے دیکھناچاہئے اوراپنے خواہشات نفساتی کے برعکس حکومت کرنی چاہئے اور فیصلہ دینا چاہئے ۔بدیہی ہے کہ جس کے وجودمیں جذبات کاغلبہ ہو تا ہے وہ اس کام کو انجام دینے کی توانائیاں نہیں رکھتا ہے ۔جب جذبات حکومت اورقضاوت سے عاجز ہوں گے تو جنگ کے شعبہ میں بدرجہ اولیٰ نامناسب ہوں گے کیونکہ دوسرے اجتماعی امورکے برعکس جنگ میں ہرخشک وتر کو جلا دیتے ہیں جنگی سپاہی اوردشمن کے شیر خوار بچے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اسلام کا جنگی طریقہ عدالت کی بنیاد پر استوار ہے، البتہ اس قسم کی کا طریقہ جذبات کے غلبہ سے عمل میں نہیں لایا جاسکتا ہے، کیونکہ اگر جنگ کے وقت جذبات اور ہمدردی کی بناپر قطب موافق کی طرف مائل ہوا تو ضرورت سے زیادہ نرمی اختیار کرکے شکست کھائے گا اور اگر قطب مخالف کی طرف مائل ہوا، تو حد سے تجاوز کرکے، گنہگاراور بے گناہ کویکسان سمجھ کر انسانی اصول و ضوابط کو پامال کرے گا۔
اس سلسلہ میں اسلام کے نظریہ کی حقانیت کی بہترین دلیل یہ ہے کہ مغربی ممالک نے مدتوں سے عورتوں کو معاشرے میں مردوں کے دوش بدوش قرار دیا ہے اور تعلیم و تربیت سے ان کی نشو نما کرتے ہیں او راب تک حکومت کے عہدوں ، عدلیہ کے عالی مقامات اور جنگی سرداروں کے عہدوں پر مردوں کے مقابلہ میں عورتوں نے کوئی قابل توجہ ترقی نہیں کی ہے۔ البتہ خانہ داری او ربچوں کی تربیت کے کاموں میں ، کہ جن کا سرچشمہ جذبات اور ہمدردی سے ہمیشہ پیش قدم رہی ہیں۔
امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک مختصر جملہ میں معاشرے میں عورت کی حیثیت و منزلت کو یوں بیان فرمایا ہے:
''فانّ المرة ریحانة و لیست بقہرمانة''(۲)
''بیشک عورت ایک خوشبودار پھول ہے نہ سورما''
اور یہ ایک بہترین جملہ ہے جو اسلامی معاشرے میں عورت کی اجتماعی منزلت کی نشاندہی کرتاہے۔
پیغمبر اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عورتوں کے بارے میں نصیحت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو آخری کلمہ فرمایا اور اس کے بعد آپصلىاللهعليهوآلهوسلم خاموش ہوگئے وہ یہ تھا:
''اللّہ اللّہ فی النسائ''(۳)
امربالمعروف اور نہی عن المنکر اور مختلف قسم کی سزائیں
اسلام کی حیات و بقا سے مربوط ضرورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے قوانین کی مخالفتوں کو روکاجائے۔ اس ضرورت کو دور کرنے کے لئے دو امور سے استفادہ کیا گیا ہے:
١۔ سزا کے لئے قوانین کاوضع کرنا،جن کو اسلامی حکومت کے ذریعہ نافذ ہونا چاہئے اور اس طرح شرعی احکام کی مخالفت کو روکا جاسکتا ہے۔
٢۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر،اسلام نے اپنے تمام پیرؤں پرواجب کیا ہے کہ جب دیکھیں کہ کسی قانون پر عمل نہیں ہورہاہے، تو وہ آرام سے نہ بیٹھیں بلکہ خلاف ورزی کرنے والے کو اطاعت پر مجبور کریں اور اسے نافرمانی کرنے سے روکیں۔
مسلمانوں کے عام افراد، بادشاہ و رعایا، طاقتو ر و کمزور، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے سب اس دینی فریضہ کو نافذ کرنے پرمامور ہیں اورخاص شرائط کے ساتھ اس کام (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کو انجام دیناچاہئے۔ یہ اسلام کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کو روکنے کے لئے ، دنیا کے مختلف کورٹ کچہری اور تھانوںسے بہتر اور قوی تر ہے۔
____________________
١۔ نسائ١٢٧۔
۲۔ وسائل الشیعہ ، ج ١٤، ص ١٢٠، باب ٨٧۔
۳۔ بحار الانوار، ج ٣٢، ص ٥٣٠۔
اسلام میں فیصلہ
مسائل عدلیہ کے کلیات
شرعی طور پر جو صفتیں قاضی میں ہونی چاہئیں ، حسب ذیل ہیں:
١۔ بالغ
٢۔عاقل
٣۔ اسلام
٤۔ عدالت، یعنی گناہان کبیرہ کو انجام نہ دے اور گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرے۔
٥۔ حلال زادہ
٦۔ علم، یعنی عدلیہ سے مربوط قوانین کو اپنے اجتہاد سے جانتاہو، اگر دوسرے کے فتوی کے مطابق سنائے تو کافی نہیں ہے۔
٧۔یادادشت۔ یعنی بھولنے والا فیصلہ نہیں دے سکتا ہے۔
٨۔بینائی۔ اکثر فقہا کی نظر میں نابینا جج نہیں بن سکتا ہے۔
اگر قاضی میں مذکورہ صفات میں سے کوئی ایک صفت نہیں پائی جاتی ہو تو وہ خو دبخودفیصلہ دینے کے منصب سے عزل ہوجاتاہے۔
قاضی (جج) کے فرائض
اسلام کی مقدس شریعت میں ، جو فیصلہ دینے کے منصب پر فائز ہو، اس کے لئے مندرجہ ذیل فرائض کا انجام دینا ضروری ہے:
١۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف دعووں کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں موجود قوانین کے مطابق فیصلہ دینا۔
٢۔ یتیموں او ردیوانوں کی سرپرستی کرنا، اگر ان کے باپ یا داد انے ان کے لئے کوئی سرپرست معین نہ کیا ہو۔
٣۔ عمومی اوقاف اور مجہول المالک اموال کی حفاظت کرنا۔
٤۔ احمقوں کے مال کی دیکھ بھال کرنا۔
٥۔ دیوانہ پن اور مفلس ہونے کا حکم جاری کرنا اور حکم جاری کرنے کے بعد مفلس کے مال کی حفاظت کرنا۔
٦۔ خیانت کرنے کی صورت میں وصی کو بدل دینا۔
٧۔ وصی کے ساتھ ایک امین کو بھی رکھنا، جب وصی اکیلے ہی ذمہ داری کو نبھانہ سکے۔
٨۔ اگر کوئی اپنا قرض ادانہ کرسکے تو اسے مہلت دینا۔
٩۔ممکن ہونے کے باوجود واجب نفقہ دینے سے اجتناب کرنے والوں پر ذمہ داری عائد کرنا۔
١٠۔ اس کے حوالہ کئے گئے اسناد اور امانتوں کا تحفظ کرنا۔
١١۔ شرعی حدود جاری کرنا۔
١٢۔ شرعاً معین شدہ افرا د کو جیل بھیجنے کا حکم جاری کرنا۔
فیصلہ کرنے کی اہمیت
اسلام میں ''قاضی''کے لئے معین کئے گئے فرائض کی تحقیقات سے فیصلہ کرنے کی اہمیت کااندازہ لگایا جاسکتا ہے ۔اسی لئے قاضی اپنے فیصلہ میں جذبات سے کام نہیں لے سکتا ہے اور رشوت لینے کا ، یہاں تک کہ بر حق افراد سے بھی ،سخت منع کیا گیا ہے ۔اس کے علاوہ اسے ان افراد کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہئے جو اس کے پاس رجوع کرتے ہیں ۔
امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلا م''مالک اشتر'' کے نام لکھے گئے ایک حکم نامہ میں فیصلہ کے بارے میں فرماتے ہیں :
''لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو دعویٰ دائر کرنے والوں کے رجوع کرنے سے تھک کر دل تنگ نہ ہو جائے اور کاموں کی رسیدگی میں مکمل طور پر صبروتحمل کا مظاہرہ کرتا ہو اورامور کے بارے میں فیصلہ دینااس کے لئے مشکل نہ ہو ۔دعوی ،کرنے والے اسے خواراورحقیرنہ سمجھیں امور کے مشکلات کے بارے میں تحقیقات اوردقت کرے اورکسی کام کو سر سری طورپر انجام نہ دے ،اگرکیس اس کے لئے واضح ہے تو لوگوں کی چاپلوسی ،دھمکی اورطمع و لالچ دلانے کے اثرمیں نہ آ ئے اورحکم الہیٰ کو کسی شک وشبہہ کے بغیر اظہار کرکے نافذ کرے اور لوگوں کے مال پر طمع کرنے سے پرہیز کرے ،چونکہ اس قسم کے لوگ کم پائے جاتے ہیں اسلئے ان کی اہم اورسنجیدہ ذمہ داری کے پیش نظرمناسب تنخواہ معین کرے تاکہ وہ اپنی آبرومند انہ زندگی میں دوسروں کے محتاج نہ رہیں اور رشوت لینے کے لئے کوئی بہانہ باقی نہ رہے اورانھیں فیصلہ سنانے کی آزادی دینا تاکہ دوسروں کی بد گوئی اورچالبازیوں سے محفوظ رہیں ۔''
گواہی
مرداورعورت کی گواہی
جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا کہ استدلال کی قدرت مرد میں اورجذبات کی قدرت عورت میں زیادہ ہوتی ہے،اس لئے اسلام میں دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابرہے ۔خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے :
(...واستشہدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل ومراتان ممّن ترضون من الشُّہداء ان تضلَّ احدٰ ہما فتذکر احدٰہما الاخری...) (بقرہ ٢٨٢)
''...اوراپنے مردوں میں سے دوگواہ بنائو اوردومردنہ ہوں توایک مرداوردوعورتیں تاکہ ایک بہکنے لگے تودوسری یاددلادے۔''
گواہی کے کلیات
تنہا وہ عام راستہ کہ جس کے ذریعہ تمام حالات میں حوادث پر قابو پایاجا سکتا ہے، گواہی کو برداشت کرنا اور اس کو انجام دیناہے اور دوسرے وسائل جیسے ''لکھنا'' اور ''فنی وسائل'' جو حوادث کو ضبط کرنے اور شکل و اعتراف کو استحکام بخشنے کے لئے فراہم کئے گئے ہیں، عام نہیں ہیں اور انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔
اس لئے، اسلام نے اس بہت سادہ اور طبیعی وسیلہ کو اہمیت دی ہے اورحکم دیا ہے کہ لوگ اس راستہ سے حوادث پر قابو حاصل کریں اور ضرورت کے وقت گواہی دیں۔
گواہ کی شرائط
١۔ بالغ ہو، اس بناپر نابالغ بچے کی گواہی قبول نہیں ہے، صرف جو بچہ دس سال کی عمر تک پہنچاہو، اگر اس نے گناہ نہ کیا ہو، تو وہ زخم لگانے کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے۔
٢۔ دیوانہ او راحمق نہ ہو۔
٣۔ مسلمان ہو، لیکن اگر وصیت کرتے وقت مسلمان گواہ تک رسائی ممکن نہ ہو تو کافرذمی (اہل کتاب جو اسلام کی پناہ میں ہو ) کی گواہی قابل قبول ہے۔
٤۔ عادل ہو، پس فاسق او رجھوٹی گواہی دینے والے کی گواہی قبول نہیںہے مگر یہ کہ وہ توبہ کرکے اس پر ثابت قدم رہے۔
٥۔ حلال زادہ ہو، اس لحاظ سے حرام زادہ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔
٦۔ اس پر الزام نہ ہو، اس بناپر اس شخص کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہے جو دعوے کے موضوع میں غرضمند ہو۔
٧۔ یقین رکھتا ہو ، اس بناپر جو حدس و یقین حس کے طریقہ سے حاصل نہ ہوا ہو، اس پرگواہی نہیں دی جاسکتی ہے اور اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کے نقصان میں کو ئی حکم جاری ہواہو، تو گواہ ضامن ہے اور اس کی تنبیہ کی جانی چاہئے او راس کے جھوٹ کو بھی لوگوں میں اعلان کرناچاہئے۔
اقرار
اقرار کی اہمیت
معاشرے میں پامال اور ضائع ہونے والے حقوق کو زندہ کرنے کے بارے میں ''اقرار'' کی اہمیت محتاج بیان نہیں ہے۔ کیونکہ عدلیہ جس کا کام انتہایی تلاش و کوشش، دلائل کو جمع کرنے کے لئے محنت و مشقت، قرائن، گواہوںکی گواہی او رحدس واندازہ سے انجام دیتی ہے،اسے''اقرار'' کے ذریعہ آسان ترین اور واضح ترین صورت میں دو جملوں میں انجام دیاجاتاہے۔
اسلام میں انفرادی نقطہ نظر سے بھی اقرار کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اقرار کا سرچشمہ وہ فطرت ہے کہ اسلام کی تمام سعی و کوشش اس کو زندہ کرنے اور اسے عملی جامہ پہنا نے میں صرف ہوتی ہے او روہ ایک ایسے انسان کی حق پرستی کی فطرت ہے جس کے مقابلہ میں ہوا و ہوس پرستی قرار پائی ہے۔
خدا ئے متعال اپنے کلام پاک میں پیرواں اسلام سے مخاطب ہو کر فرماتاہے:
( یا ایّها الّذین آمنوا کونوا قوّاّمین بالقسط شهداء للّه و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ) ( نسائ١٣٥)
''اے ایمان والو! عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو او راللہ کے لئے گواہ بنو چاہے اپنی ذات یا اپنے والدین او راقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو...''
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:
''حق بات کہو اگر چہ اپنے نقصان میں ہو۔''(۱)
اقرار کے معنی اور اس کی شرائط
''اقرار'' شرع وشریعت میں ایک ایساقول ہے کہ کہنے والا دوسرے کاحق اپنے اوپر ثابت کرتا ہے، جیسے کہتا ہے:''میں ایک ہزار رو پئے کا فلاں شخص کا مقروض ہوں''۔
اقرار کرنے والے کے لئے بالغ ، عاقل اور صاحب اختیار ہونا شرط ہے، اس بناء پر بچہ، دیوانہ، مست، بیہوش، سوئے ہوئے اور مجبور شخص کا اقرار صحیح نہیں ہے۔
شفعہ
اگر دوآدمی، دوگھریا کسی اور ملکیت کے مشترک مالک ہوں اور ان میں سے ایک اپنے حصہ کو کسی تیسرے شخص کے ہاتھ بیچ دے، تو اس کادوسرا شریک حق رکھتا ہے کہ اسی عقد اور اسی قیمت پر اس کے حصہ کولے لے، اس حق کو ''شفعہ'' کہتے ہیں۔
واضح ہے کہ اسلام میں یہ حق کمپنیوں کے تسویہ اور شرکاء کے تصرفات کی وجہ سے رونماہونے والے نقصانات اور خرابیوں کودور کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اکثر یہ اتفاق پیش آتاہے کہ ملکیت میں تازہ شریک کے تسلط سے صاحب شفعہ کو نقصان پہنچتا ہے، یا سلیقوں میں اختلاف کی وجہ سے اختلافات اور کشیدگیوں کا ایک سلسلہ وجود میں آتاہے، یا مالکیت میں آزادی (صاحب شفعہ) شریک کے لئے کوئی فائدہ رکھتی ہو بغیر اس کے کہ بیچنے والے شریک کے لئے کوئی نقصان ہو۔
شفعہ، زمین، گھر، باغ اور دیگر غیر منقولہ اموال کے لئے ثابت ہے اور منقولہ اموال میں شفعہ نہیںہے۔
مرد اور عورت کا طبقہ
خالق کائنات نے نوع بشر کو دوسرے جاندارمخلوقا ت کے مانند نرومادہ میں تقسیم کیا ہے اوراس طرح اس نوع کی بقاء کا تنہاضامن تناسل و توالد کا سلسلہ جاری رکھا ہے ۔
مرد اور عورت،اس کے باوجود کہ نسل پھیلانے کے لئے دو مختلف نظاموں سے مسلح ہیں ،ان میں سے ہرایک ،ایک انسان کی مکمل فطری توانائیاں رکھتا ہے اوریہ انسان کی ذاتی خصوصیتوں میں بھی برابرہیں۔ان دونوں صنفوںکی تنہا خصوصیت جوسماج میں جداگانہ امتیازات کاسرچشمہ ہوسکتی ہے ، وہ یہ ہے کہ:
مرد کی صنف میں غوروخوض کی خاصیت زیادہ قوی ہوتی ہے اور عورت کی صنف میں جذبات اور ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں ۔اورانہی خصو صیات کی وجہ سے،معاشرے میں ان دونوں میں سے ہر ایک نے مخصوص فرائض کو اپنے ذمہ لیکر معاشرہ کوچلاتے ہیں ۔اگر یہ اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ کھینچ لیں تو معاشرہ ٹھپ ہوکررہ جائے گا۔
اسلام نے جواحکام ان دو صنفوں کے لئے وضع کئے ہیں ،ان میں کلی طورپرہرایک کی صفتوں اورخصوصیتوں کو مدنظر رکھا گیا ہے اور مشترک قوانین میں اسی نوعی اشتراک کومدنظر رکھ کران دونوں صنفوں کو حتی الامکان نزدیک لایا گیاہے ۔
یہ جاننے کے لئے کہ اسلام نے اپنی حقیقت بینی کی بناپر ،ان دوصنفوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لئے کیسے موثر قدم اٹھائے ہیں اوربالخصوص عورتوں کے حالات میں بہتری اورآسودگی لانے کے لئے کیسے قوانین بنائے ہیں، ہمیں اسلام سے قبل عورتوں کے عام حالات سے آگاہ ہونا چاہئے اور اس سلسلہ میں ایک تحقیق کریں اورماضی کے ترقی یافتہ اورغیرترقی یافتہ معاشروں میں جو برتائوعورتوں کے ساتھ ہوتا تھا اسے مدنظر رکھیں پھر عورتوں کے بارے میں اسلام کے وضع کئے گئے قوانین کی تحقیق کریں ۔
اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت
الف:قبائلی معاشرے میں عورت
قدیم ملتوں میں جب ان کاطرز زندگی قانونی یادینی نہیں تھا اورصرف قومی آداب ورسوم کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے،توعورت،انسان شمارنہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک پالتوجانور جیسا سلوک کیا جاتا تھا ۔
انسان جب آغاز سے پالتوجانوروں کویکے بعددیگرے اپنااسیر بناکران کی تعلیم وتربیت کرتاتھا ،ان کی حفاظت اوران کی زندگی کے لئے بے پناہ محنت کرتااور رنج وتکلیف اٹھاتا تھا،تو یہ سب اسلئے نہیں تھا کہ انھیں انسانیت کی حیثیت سے پہچانے یا انھیں اپنے معاشرے کاایک عضوقراردے اوران کے لئے کچھ حقوق کا قائل ہو جائے ،بلکہ وہ ان کے گوشت ،کھال ،اون ،دودھ، سواری ، سامان ڈھونے اوردیگر فوائد سے بہرہ مندہونے کے لئے تھا۔
اس لئے ان جانوروں کی بقاء اورزندگی کے لئے ،کچھ وسائل جیسے خوراک اور رہائش وغیرہ فراہم کرتا تھا ،لیکن یہ محنت و مشقّت ان کے ساتھ ہمدردی کی بناپرنہیں ہوتی تھی بلکہ اپنے فائدے کے لئے ہوتی تھی۔
انسان ان جانوروں کا دفاع کرتاتھا اوراجازت نہیں دیتاتھاکہ کوئی انھیں مارڈالے یا انھیں اذیت پہنچائے اور اگرکوئی ان پر تجاوز کرتا،تووہ اس سے انتقام لیتا تھا ،لیکن یہ سب اس لئے تھا کہ خود کو ان کامالک جانتاتھا اوراپنے حقوق کی حفاظت کرنا چاہتاتھا نہ یہ کہ ان حیوانات کے لئے کسی حق کاقائل تھا ۔عورت کو بھی اسی طرح اپنے استفادہ کے لئے چاہتاتھا۔
عورت کی معاشرے میں رکھوالی کرتا تھا اوراس کادفاع کرتاتھا ،جواس پر تجاوزکرتا اسے سزادی جاتی تھی ،لیکن نہ اس لئے کہ وہ انسان ہے یامعاشرے کاعضوشمار ہوتی ہے یاکسی حق واحترام کی حقدارہے ،بلکہ اس لئے کہ زندہ رہے اورمرد کے جنسی خواہشات کا کھلونا بنی رہے اور اہل خانہ یعنی مردوں کے لئے کھانا پکائے اور تیار کرے ،ساحل نشیں قوموں کے لئے مچھلی پکڑے.سامان ڈھوئے ،گھر کاکام کرے اورضرورت کے وقت بالخصوص قحط سالی اورمہمان نوازی کے موقع پر اس کے گوشت سے غذا تیار کی جائے ۔
باپ کے گھر میں بھی عورت کی یہی حالت تھی یہاں تک کہ اسے شوہر کے حوالہ کیا جاتاتھا ،لیکن نہ اسکے اپنے اختیاروانتخاب سے،بلکہ ماں باپ کے حکم سے وہ بھی ایک قسم کا بیچناتھانہ کہ ازدواج عہدو پیمان۔
عورت،باپ کے گھر میں ،باپ کے ماتحت اورشوہر کے گھر میں ،شوہر کے ماتحت اور اس کی تابع ہوتی تھی اور ہر حالت میں صاحب خانہ کے زیرنظراور اسکی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی تھی ۔
صاحب خانہ اسے بیچ سکتاتھایااسے کسی کوبخش سکتا تھا یادوسرے مقاصدکے لئے جیسے عیاشی یابچہ پید اکرنے یاخدمت کرنے کے لئے عاریت،قرض یاکرایہ پردوسروں کو دے سکتا تھا اگراس سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہوتی تواسے ہر طرح کی سزا دینے کا حق تھا،یہاں تک کہ قتل تک کر سکتا تھا،اوراس کے بارے میں کسی بھی قسم کی ذمّہ داری کا احساس نہیں ہوتاتھا ۔
ب۔عورت،ترقی یافتہ سلطنتی معاشرے میں
ترقی یافتہ سلطنتی معاشرہ،جیسے،ایران،مصر،ہندوستان اورچین کہ جو و قت کے بادشاہوں کی مرضی پر چلتا تھا اوراسی طرح متمدن معاشرہ جیسے کلدہ ،روم اور یونان جہاں کے لوگ قانونی حکومت کی زندگی بسر کرتے تھے ،اگر چہ عورت کی حالت دوسرے معاشروں سے بہترتھی اورکلی طورپرمالکیت سے محروم قرارنہیں دی جاتی تھی ،لیکن پھر بھی مکمل آزادی نہیں رکھتی تھی جس گھر میں عورت زندگی گزارتی تھی اس کاسر پرست جیسے باپ ، بڑا بھائی یاشوہر اس پر مطلق حکومت کرتاتھا ۔یعنی اسے حق ہوتاتھا کہ جس کے ساتھ چاہے اس کا عقد کرے یاعاریت و کرایہ پر دیدے یاکسی کو بخش دے اورخاص کر (خطاسرزدہونے پر) اسے قتل کرسکتا تھا یاگھرسے نکال سکتا تھا ۔
بعض ملکوں میں عورت فطری رشتہ داری سے محروم تھی اورمرداپنی محرم عورتوں سے شادی کرسکتا تھا۔
بعض دوسرے ممالک میں ،عورت باضابطہ اورقانونی رشتہ دار شمارنہیں ہوتی تھی ،اور میراث کی حقدار نہیںہوتی تھی ۔
بعض جگہوں پر کئی مرد ایک عورت سے شادی کرتے تھے اورزمانہ جاہلیت میں بعض عرب قومیں اپنی بیٹیوںکوزندہ دفنا تے تھے ،عورت کو منحوس جانتے تھے ۔اگر اس پر کوئی زیادتی اورظلم ہوتا تواسے عدالت میں جاکر شکایت کرنے اوراپنادفاع کرنے کا حق نہیں تھا اوراسے گواہی دینے کا حق بھی نہیں تھا ۔
خلاصہ یہ کہ اس معاشرے میں عورت ایک کمزورعضوشمار ہوتی تھی جسے مرد کی سرپرستی میں زندگی بسرکرنا ہوتی تھی ۔اسے ہرگز اپنے ارادہ سے فیصلہ کرنے ،کام اورپیشہ کے انتخاب میں آزادی نہیں تھی ۔بلکہ ایک چھوٹے بچے کے مانندتھی جسے بالغ ہونے تک کسی کی سرپرستی میں زندگی بسرکرنا پڑتی ہے فرق صرف یہ تھا کہ یہ عورت کبھی بالغ نہیں ہوتی تھی !
عورت ایک جنگی اسیر کے مانندتھی کہ جب تک آزاد نہ ہوجائے دشمن کی غلامی میں رہتا ہے اور اس کے کام وکوشش سے استفادہ کیا جاتا ہے ،اس کے مکروفریب سے ہوشیار رہتے ہیں ،فرق یہ تھا کہ عورت کو اس اسیری سے آزادہونے کی کبھی امید نہیں ہوتی تھی ۔
ج:عورت دینی معاشرہ میں
دینی معاشروں میں بھی عورت پر جو کچھ دوسرے معاشروں میں گزرتی تھی۔کوئی خاص فرق نہیں ہوتا تھا اوراس کے لئے کسی قسم کے حق کے قائل نہ تھے ۔
یہودیوں کی موجودہ توریت نے عورت کوموت سے زیادہ تلخ بتایاہے اور کمال سے مایوس شمار کیا ہے ۔
رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے،فرانس میں عیسائی پادریوںکا ایک اجتماع منعقد ہوا،جس میں عیسائی پاد ریوںنے عورتوں کی حالت پرمفصل بحث وتحقیق کے بعد حکم صادرکیا کہ :
''عورت ایک انسان ہے لیکن مرد کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہے ۔!''
ان تمام معاشروں میں ،اولادباپ کی تابع ہوتی تھی نہ ماں کی اوران کے نسب کی بنیاد باپ سے تشکیل پاتی تھی نہ ماںسے ،صرف چین اورہندوستان کی چندجگہوں پرکئی شوہر کرنے کارواج تھا،بچے ماں کے تابع ہوتے تھے اوران کے نسب کی بنیاد مائیں تشکیل دیتی تھیں ۔
خلاصہ
اسلام سے پہلے،پوری دنیا میں تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانی معاشروں میں ، عورت کو معاشرے کاایک سر گرم عضوشمارنہیں کیا جاتا تھا اور وہ استقلال وآزادی کی مستحق نہیں تھی اور ہمیشہ ایک کمزوراورمحکوم مخلوق شمار ہوتی تھی اور وہ خود بھی زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انسانی خصلتوں کو کھوکرکے اپنے لئے کسی قسم کی اجتماعی شخصیت کو تصور نہیں کرسکتی تھی ۔
لفظ''عورت''ذلت،خواری ،پستی اور بیوقوفی کے معنی دیتا تھا ۔ہرزبان کے ادبیات کے نظم ونثر میں عورت کے بارے میں بہت سی نا شا یستہ باتیں اور خرافات پائے جاتے ہیں جو ماضی کے معاشروں میں عورت کے بارے میں روارکھے جانے والے نظریہ کی عکاسی کرتے ہیں ۔
____________________
١۔ میزان الحکمة ،ج ٢، ص ٤٦٨۔
عورت کے بارے میں اسلام کا نظریہ
جس دن اسلام کاسورج بشریت کے افق پر طلوع ہوا ، اس وقت عورت کی سماجی حالت وہی تھی جو خلاصہ کے طور پربیان کی گئی ۔
اس زمانہ کی دنیا میں عورت کے بارے میں چندغلط اور خرافات پر مشتمل افکار اورظالمانہ طرز عمل کے علاوہ کچھ نہیں تھا .لوگ(حتی خودعورت کاطبقہ )عورت کے لئے کسی مقا م یاحق کے قائل نہیں تھے اوراسے ایک پست مخلوق سمجھتے تھے جوشریف انسان (مرد)کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہے ۔
اسلام نے پوری طاقت کے ساتھ ان افکار کی مخالفت کی اورعورت کے لئے حسب ذیل حقوق مقررفرمائے :
١۔عورت ایک حقیقی انسان ہے اورانسان کے نرومادہ جوڑے سے پیداکی گئی ہے اورانسان کی ذاتی خصوصیات کی حامل ہے اورانسانیت کے مفہوم میں مرد کو اس پر کوئی امتیاز حاصل نہیںہے۔خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے :
( یایّها النّٰاس اِنّاخلقنکم من ذکرٍوانثی ) ...) (حجرات١٣)
''انسانو!ہم نے تم کوایک مرداورایک عورت سے پیداکیاہے ...''
کئی دوسری آیتوں میں فرماتا ہے :
( بعضکم من بعض ) (آل عمران ١٩٥)
''تم سب ہم جنس ہو ''
٢۔عورت،مرد کے مانندمعاشرہ کاعضو ہے اورقانونی شخصیت کی مالک ہے ۔
٣۔عورت چونکہ فطری رشتہ دارہے اسلئے سرکاری اورقانونی طورپربھی رشتہ دار ہے ۔
٤۔بیٹی ،اولادہے جس طرح بیٹااولادہے،اسلئے بیٹیاں ،بیٹوںکی طرح اولادہیں ،اس لحاظ سے عورت بھی مرد کی طرح اپنے سببی اور نسبی رشتہ داروں جیسے باپ اورماں سے میراث پاتی ہے ۔
٥۔عورت فکری آزادی کی مالک ہے اوراپنی زندگی میں ہرقسم کا فیصلہ کرسکتی ہے اورشر عی حدود میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے لئے شوہرمنتخب کرسکتی ہے اور باپ یاشوہرکی ولایت اورسر پرستی میں رہے بغیر آزادی کے ساتھ زندگی گزارسکتی ہے اورہر جائز پیشہ کو منتخب کرسکتی ہے ۔
عورت عمل کے میدان میں مستقل ہے اوراس کاکام اورکوشش محترم ہے اور وہ مالک بن سکتی ہے اوراپنی دولت وثروت کو مرد کی سر پرستی اورمداخلت کے بغیرتصرف کرسکتی ہے اوراپنے انفرادی واجتماعی مال اورحقوق کادفاع کرسکتی ہے اور دوسروں کے حق میں یاخلاف گواہی دے سکتی ہے ۔وہ جنسی آمیزش کے مسئلہ کے علاوہ (جس میں ازدواجی زندگی کے معاہدہ کے مطابق اپنے شوہر کی اطاعت کرناضروری ہے )اپنے شوہر کے لئے کوئی دوسرا کام انجام دے تو وہ قابل قدر ہے۔
٦۔مرد کو عورت پر حکم چلانے اورظلم کرنے کا کوئی حق نہیںہے اور ہرظلم جومردوں کے بارے میں مقدمہ چلا کرقابل سزا ہے وہ عورتوں کے بارے میں بھی مقدمہ چلانے اورسزا دینے کے قابل ہے۔
٧۔عورت معنوی دینی شخصیت کی مالک ہے اوراخروی سعادت سے محروم نہیں ہے ،وہ وایسی نہیں ہے جیساکہ اکثرادیان اورمذاہب عورت کو ایک شیطان کے مانند،رحمت خداوندی سے مایوس تصور کرتے ہیں ۔
خدائے متعال اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے :
( من عمل صٰلحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینَّه حیٰوة طیّبة ولنجزینَّهم اجرهم باَحسنِ ماکانوا یعملون ) (نحل٩٧)
''جوشخص بھی نیک عمل کرے گاوہ مرد ہو یاعورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہو ہم اسے پاکیزہ حیات عطاکریں گے اورانھیں ان اعمال سے بہترجزادیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے ہیں''
(...( انّی لااضیع عملَ عامل منکم من ذکر اوانثی ) ...)
(آل عمران ١٩٥)
''میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کوضائع نہیں کروں گا چاہے وہ مرد ہو یاعورت...''
درج ذیل آیہ شریفہ کے مطابق ممکن ہے ایک عورت تقوی اوردین کی بدولت ہزاروں مردوں پرامتیاز اور فوقیت حاصل کرے :
(یایّہا النّاس انّا خلقٰنکم من ذکر وانثی وجعلنٰکم شعوباً وقبائل لتعارفوا انَّ اکرمکم عند اللّٰہ اتقٰکم ...) (حجرات ١٣)
''انسانو! ہم نے تم کو ایک مرداورایک عورت سے پیدا کیاہے اورپھر تم میں شاخیں اورقبیلے قرار دیئے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جوزیادہ پرہیز گار ہے ...''
نکاح
(ازدواج)
نکاح کے مسائل اوراحکام
اسلامی تعلیمات میں نکاح اورازدواجی زندگی کے موضوع کو کافی اہمیت دی گئی ہے ۔اس کی اہمیت اس حدتک ہے کہ پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
نکاح میری سنت ہے اورجو بھی میری سنت پر عمل نہ کرے ،اسے اپنے آپ کو مجھ سے نسبت نہیں دینی چاہئے اوروہ اپنے آپ کومسلمان شمارنہ کرے۔(۱)
نکاح کے احکام
دین اسلام میں نکاح کی دوقسمیں ہیں :
١۔'' دائمی نکاح'':یہ وہ نکاح ہے کہ عقدجاری ہونے کے فوراًبعد میاں بیوی کارشتہ ہمیشہ کے لئے برقرار ہوجا تا ہے ۔یہ رشتہ صرف طلاق کے ذریعہ توڑاجاسکتا ہے ۔اس ازدواج میں مرد کو مہر کے علاوہ بیوی کی حیثیت کے مطابق اس کی زندگی کے اخراجات اداکرنے ہوتے ہیں اور کم از کم چار راتوں میں سے ایک رات کو اس کے ساتھ گذارے بیوی اس سلسلہ میں شوہر کے تقاضا کو مسترد نہیں کرسکتی ہے ۔
٢۔موقت نکاح جسے''متعہ''کہا جاتا ہے ۔یہ نکاح ،ایک محدود اورمعین مدت کے لئے میاں بیوی کے درمیاں رابطہ کو پیدا کر تاہے اورجوں ہی مدت ختم ہوئی یامرد نے باقی مدت کو بخش دیا تو طلاق کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ۔
اس ازدواج میں نکاح دائم کے احکام میں سے کوئی حکم نہیں پایا جاتا ہے ،مگر یہ کہ عقد کے وقت شرط کی گئی ہو ۔
نوٹ
نکاح موقت''متعہ''اسلام میں جائزہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھا ،یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ نے بعض وجوہات کی بنا پر اس پرپابندی لگادی ،اس لئے اہل سنت اسے جائز نہیں جانتے ،لیکن شیعوں کے نزدیک جائز ہے اوراسے اسلام کے شاہکاروں میں سے ایک جانتے ہیں ،کیونکہ معاشرے کی ضرورتوں کے ایک اہم حصہ کو۔جس کودوسرے راستہ سے روکنا ممکن نہیںہے دور کرتا ہے اورعمومی عفت کا بہترین حامی اورضامن ہے ۔
امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :
''اگرموقت نکاح کو ممنوع نہ قرار دیا گیا ہوتا تو شقی اوربدبخت کے علاوہ کوئی زنانہ کرتا''(۲)
جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے
اسلام میں بعض عورتوں کے ساتھ رشتہ داری اورنسبی رشتہ کی وجہ سے نکاح کرنا حرام اورممنوع ہے، اور وہ حسب ذیل ہیں :
١۔ماں ،دادی،نانی اور جتنا سلسلہ اوپرچلا جائے ۔
٢۔بیٹی،نواسی اورجتنا سلسلہ نیچے چلاجائے۔
٣۔پوتی اورجتنا سلسلہ نیچے چلاجائے۔
٤۔بہن،بھانجی اورجتنا سلسلہ نیچے چلاجائے۔
٥۔بھتیجی ،بھتیجی کی بیٹی اورجتنا سلسلہ نیچے چلا جائے ۔
٦۔پھوپھی
٧۔خالہ
نوٹ
جوعورتیں نسبی رشتہ کی وجہ سے مردپر حرام ہیں وہی عورتیں ایک شیرخواربچہ کو دودھ پلانے سے حرام ہوجاتی ہیں ۔
بعض عورتیں سببی رشتہ (دامادی )کی وجہ سے مردپر حرام ہوجا تی ہیں ،وہ حسب ذیل ہیں :
١۔بیوی کی ماں اوراسکی دادی ونانی اور جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے ۔
٢۔بیوی کی بیٹیاں ،اگرمردنے اس بیوی سے ہمبستری کی ہو۔
٣۔باپ کی بیوی ،اگرچہ باپ نے اس کے ساتھ ہمبستری بھی نہ کی ہو۔
٤۔بیٹے کی بیوی ،اگرچہ بیٹے نے اس کے ساتھ ہمبستری بھی نہ کی ہو۔
٥۔بیوی کی بہن ۔جب تک بیوی زندہ اور مردکے عقد میں ہو ۔
٦۔بیوی کی بھتیجی اور بھانجی ، جبکہ بیوی سے اجازت نہ لی ہو،لیکن بیوی کی اجازت سے حرام نہیں ہیں ۔بعض عورتیں دوسرے وجوہا ت سے مردپر حرام ہوجاتی ہیں :
١۔شادی شدہ عورت۔
٢۔پانچویں عورت ،جس مرد کے چار دائمی عقدوالی بیویاں ہوں ۔
٣۔کافر عورت،لیکن یہودی اورعیسائی کے مانند اہل کتاب ہو تو اس کے ساتھ موقت عقدکیا جا سکتا ہے ۔
عقد کاولی
دین اسلام میں ، مرداورعورت اگربالغ ہوں تواپنا شریک حیات انتخاب کرنے میں آزاد ومستقل ہیں ۔لیکن نابالغ بیٹی اور بیٹے کے ولی ان کے باپ ہیں ،اس معنی میں کہ باپ اپنی نابالغ بیٹی کاعقد کسی لڑکے سے کرسکتا ہے اوراپنے نابالغ بیٹے کا عقد کسی لڑکی سے کر سکتا ہے ۔
اولاد کے حقوق اورتبعیت
١۔اگرشادی شدہ عورت،سے کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ بچہ اس کے شوہر کاہے،چنانچہ وہ بچہ دائمی بیوی ہو تو شوہرا پنا بچہ ہونے سے ا نکار نہیں کرسکتا ہے۔
٢۔اگربچہ اپنی زندگی کا خرچ پورانہ کرسکتا ہو ،تو اسکے ماں باپ کو اس کے اخراجات کو پورا کرنا چاہئے اورچنانچہ ماں باپ اپنے اخراجات پو رے نہ کرسکتے ہو ں توان کے اخراجات ان کے فرزند کے ذمہ ہیں ۔
اسلام میں متعدد بیویاں
شریعت اسلام کے مسلمات میں سے ہے کہ مرد ایک ساتھ چار بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس حکم کے فلسفہ کو سمجھنے کے لئے درج ذیل نکات پر توجہ کرنا ضروری ہے :
١۔یہ حکم،اختیاری احکام میں سے ہے اور واجبی وحتمی حکم نہیں ہے، یعنی مسلمان مردپر واجب نہیں ہے کہ چاربیویاں رکھے بلکہ ایک ہی وقت میں دویاتین یاچاربیویاں رکھ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ،چونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے میں شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان عدالت کی رعایت کرے اور یہ کام بہت مشکل ہے اورہرایک کے بس کی بات نہیںہے ۔ اس لئے اس کام کے لئے قدم اٹھانا اپنے لئے استثناء حالت پیدا کرنا ہے ۔
٢۔بشر کی ضرورتوں میں سے ایک تناسل وتوالداورآبادی بڑھاناہے ۔ خالق کائنات نے اسی غرض سے انسان کو مرداورعورت میں تقسیم کیا ہے .اسلام بھی چونکہ دین فطرت ہے اس لئے اس نے انسان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا ہے اسی لئے ازدواج کا حکم دیا ہے اورچونکہ مرداورعورت میں تناسل اور توالد صلاحیت کے لحاظ سے ، فرق ہے ،اس لئے متعدد شادیاں جائز کی ہیں ۔
اب ہم اختلاف کی علتیں بیان کرتے ہیں :
الف:کلی طورپر عورت نوسال کی عمر میں ازدواج کی صلاحیت پیداکرتی ہے جبکہ مرد کے لئے یہ استعداد پندرہ سال میں پیدا ہوتی ہے۔
نتیجہ کے طورپر اگرہم کسی معین سال کو مدنظر رکھ کر لڑکے اورلڑکیوں کی ولادت کو (اکثرًلڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہیں )درج کریں گے اور بعد والے سالوں کی ولادتوں کو اس پر اضافہ کریں گے توسولہویں سال ہر لڑکا جوازدواج کی شرعی صلاحیت پیدا کرے گا اس کے مقابلہ میں سات لڑکیاں ازدواج کی صلاحیت پیدا کریںگی ۔اگرلڑکوں کے ازدواج کی عمر جو معمولاً بیس سال سے اوپر ہے، کو مدنظر رکھیں ،تواکیسویں سال میں ہرایک لڑ کے کے مقابلہ میں دولڑکیاں شا دی کے لا ئق ہوںگی اورپچیسویں سال میں کہ عام طور پر شادی اسی عمر میں کردی جاتی ہے ۔ہردس لڑکوں کے مقابلہ میں سولہ لڑکیاں شادی کے لائق ہو جائیں گی ۔
ب۔عورت غالباًپچاس سال کی عمرمیں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھودیتی ہے جبکہ مرداپنی طبیعی عمر کے آخری دنوں تک یہ صلاحیت رکھتا ہے ۔
ج۔اعدادوشمار کے مطابق نوزاد لڑکوں کی موتیں نوزادلڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہیں اورعورتوں کی اوسط عمرمردوں کی نسبت زیادہ ہے کیونکہ گوناگوں عوامل کی وجہ سے عورتوں کی نسبت مردوں میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں ۔اسی طرح(اعدادوشمار کے مطابق)مردکی عمرغالباًعورت کی عمرسے کم ہوتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ معاشرہ میں ہمیشہ بیوہ عورتیں ،بیوی کے بغیرمردوں سے زیادہ ہوتی ہیں ۔
اس بات کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں متعدد شادیوں کی رسم صدیوں تک باقی تھی اور باوجود اس کے کہ بعض لاابالی اورفاقد عدالت مردوں نے بھی یہ کام انجام دیا ہے ،لیکن کبھی کوئی مشکل یاعورتوں کی کمی کا مسئلہ پیش نہیں آیا ہے ۔
کہتے ہیں:چونکہ متعدد شادیوں کامسئلہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے،چوں کہ اس کے جذبات کو مجروح کرتا ہے یہا ں تک کہ بعض اوقات اسے انتقام لینے پر مجبور کرتا ہے اورمرد کی زندگی خطرہ میں پڑجاتی ہے ۔
ایسا سوچنے والوں نے اس حقیقت میں غفلت برتی ہے کیوںکہ مذکورہ مخالفت عادت سے مربوط ہے نہ اسکی فطرت اورطبیعت سے،کیونکہ اگراس کی بنیاد فطرت پر ہوتی تومتعدد شادیوں کا کام عملاًکبھی واقع ہی نہ ہوتا ۔کیونکہ جوعورتیں کسی مرد کی دوسری ،تیسری یا چوتھی بیوی بنتی ہیں ،وہ عورتوں کے اسی طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں جوکہ اپنی مرضی اوررغبت سے شادی شدہ کسی مردسے شادی کرنے پرآمادہ ہوتی ہیں۔اگریہ کام انکی فطری اورطبیعی جذبات کے خلاف ہوتا،توہرگزایسی چیز کوقبو ل نہ کرتیں ،چنانچہ اگرازدواج میں کسی عورت سے یہ شرط کی جائے کہ اسے تنہازندگی گزارناہوگی اورکسی سے بات نہیں کرے گی ،توچونکہ یہ کام اسکی فطرت کے خلاف ہے ،اس لئے ہرگز وہ اس شرط کوقبول نہیں کرے گی۔
اسکے علاوہ دین اسلام میں اس مشکل کوحل کر نے کے لئے ایک راستہ موجود ہے ،وہ یہ کہ عورت ازدواج کے وقت،عقدلازم کے ضمن میں شرط رکھ سکتی ہے کہ اس کاشوہردوسری شادی نہ کرے اورا س طرح اس کا سد باب کر سکتی ہے ۔
اولاد کی میراث کا مسئلہ بھی دوسری صورت میں منظم کیاجاسکتا ہے،مثلاًحکومت کو مردکاوارث قراردیں اورمعاشرے کے فرزندوں اورنوزاد بچوں کی تربیت حکومت کے ذمہ چھوڑکربچوں کو پرورش گاہ اورنرسریوں میں پالا جائے ۔
اگرچہ یہ طریقہ انسانی معاشروں میں استثنائی طورپر انجام پاتا ہے ،لیکن ایک ناقابل تغیرقانون کی حیثیت سے جاری رہنے کی ہرگز صلاحیت نہیں رکھتا،کیونکہ،یہ طرزعمل،مختصر زمانہ میں ،انسانی جذبات،غمخواری ،مہرومحبت اورقوی خاندانی ہمدردی۔جونسل کی ایجاد کے لئے انسان کااصلی محرک ہے کونابود کرکے رکھدیتاہے اورنتیجہ کے طورپرنسل بڑھانے کے موضوع کولوگوں میں خاص کرعورتوں میں کہ واقعاً ایام حمل کے دوران ناقابل برداشت تکلیفیںاٹھاتی ہیں ایک بیہودہ عمل دکھاتا ہے اورمہرومحبت والے خاندان کوایک تاریک زندان میں تبدیل کردیتا ہے ۔
ایسے حالات کے رونماہونے کی وجہ سے تناسل وتوالدکاراستہ بالکل بندہوجاتا ہے اورخاندان جوحقیقت میں شہری معاشرہ کو تشکیل دیتاہے نابود ہوکررہ جاتاہے،اورخاندان کی تشکیل اورتناسل وتوالدفنی وسائل اورسیاسی فریب کاریوں کے ذریعہ انجام پاتے ہیں،جیسے بچہ پیداکرنے والوں کے لئے بڑے بڑے انعامات کااعلان کرنایاسخت قوانین نافذ کرناوغیرہ ۔بدیہی ہے کہ اس قسم کی حالت،جوفطرت کے ساتھ ساز گار نہیں ہوتی،پائدارنہیں ہے ۔
اس کے علاوہ واضح ہے کہ اس صورت میں ،انسان کی زندگی ایک وحشتناک شکل میں تبدیل ہوکرخشک وبے لذت ہوگی اورحقیقت میں ،انسان کی زندگی کاماحول مویشیوں سے زیادہ پست اوردرندوں کے ماحول سے زیادہ خطرناک ہوگا۔
____________________
١۔بحارالانوار.ج١٠٣،ص٢٢٠ح٢٣۔
۲۔وسائل الشیعہ ،ج١٤،ص٤٣٦،باب متعہ ۔
طلاق
(میاں بیوی کی جدائی)
میاں بیوی کے شرعی رابطہ کے ختم ہونے کے بعد،ایک دوسرے سے جدا ہوکرازدواجی حقوق کے قوانین کی پابندی سے آزاد ہونے کو''طلاق''کہتے ہیں ۔
طلاق کاقانون اسلام کا ایک ناقابل انکارامتیاز ہے جو وہ مسیحیت اورچند دیگرادیان پر رکھتا ہے اورانسانی معاشرے کی ایک ضرورت کوپورا کرتا ہے ،کیونکہ بے شمار ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ میاں اوربیوی کے اخلاق آپس میں سازگارنہیں ہوتے اورپیارومحبت کا ماحول ایک میدان جنگ میں تبدیل ہوجاتا ہے اوران کے درمیان مصالحت ممکن نہیں ہوتی ،اس صورت میں اگر میاں بیوی کارشتہ توڑنے کے قابل نہ ہوتا تو میاں بیوی کوعمر بھرایک بدبختانہ زندگی گزارنا پڑتی جو کہ در حقیقت ایک شعلہ ورجہنم ہے اورتلخی و محرومیت کے ساتھ نامناسب جسمانی اذیتیں برداشت کرناپڑتیں اور اس مطلب کی بہترین مثال یہ ہے کہ عیسائی حکومتیں بھی عام ضرورتوں کے پیش نظر آخر کار''طلاق'' کوقانونی حیثیت دینے پر مجبورہوئیں ۔
اسلام میں طلاق کا اختیارمرد کو دیاگیا ہے،البتہ اس حکم میں مرداورعورت کی فطری حالت کومدنظر رکھا گیا ہے ،کیوںکہ اگرطلاق کا اختیار عو رت کے ہاتھ میں ہوتا ،چونکہ عورت مردسے زیادہ جذبات کی اسیر ہوتی ہے ،اسلئے میاں بیوی کارابطہ ہمیشہ کمزور پڑتا اور تشکیل پایاہوا خاندان متزلزل ہوکرآسانی کے ساتھ بکھر جاتا ۔اسکے باوجوددین اسلام میں ایسی راہیں موجود ہیں کہ عورت بھی طلاق کے حق سے استفادہ کرسکتی ہے ،اپنے شوہرسے معاشرت کے ضمن میں دوراندیشی کے پیش نظر عقدنکاح کے وقت شرط رکھے کہ اگراحتمالی مشکلات میں سے کوئی مشکل پیش آئے تو طلاق جاری کرنے کی وکا لت کا حق ہوگا یایہ شرط رکھے کہ اگرشوہر بلاوجہ اسے طلاق دے تواس پراس کے مشکلات کوحل کرنے کی ذمہ داری ہوگی ۔
اسلامی شریعت نے اگرچہ طلاق کوقانونی حیثیت دی ہے ،لیکن اس کی غیر معمولی اورزبردست مذمت کی ہے اوربہت نصیحت کی ہے کہ اگرمسئلہ اضطرار کی حدتک نہ پہنچے تومرد اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اورازدواجی رشتہ کونہ توڑے۔پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :
''خدائے متعال کے نزدیک ناپسند ومنفورترین چیزوں میں سے ایک طلاق ہے''(۱)
اسی لئے اسلام میں طلاق کے لئے چند مشکل قوانین وضع کئے گئے ہیں،جیسے طلاق دوعادل افرادکے سامنے انجام پانا چاہئے اوران دنوں میں ہو کہ عورت اپنی عادت کے ایام میں نہ ہواور مردنے ان دنوںاس سے ہمبستری نہ کی ہو۔
اسی طرح مقرر ہوا ہے کہ اگرطرفین کے درمیان کوئی اختلاف یانزاع پیدا ہوجائے تودوافراد کوحُکُم قراردیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان مصالحت کرائیں اورصرف اس صورت میں طلاق دی جائے کہ جب مصالحت کی تمام کوششیں نا کام ہوجائیں ۔
طلاق صحیح ہونے کی شرائط
اپنی بیوی کو طلاق دینے والے مرد میں درج ذیل شرائط ہونی چاہئیے :
١۔بالغ ہو۔
٢۔عاقل ہو ۔
٣۔اپنی اختیار سے طلاق د ے ۔
٤۔طلاق دینے کاقصدرکھتاہو ۔
اس بنا پر نابالغ،دیوانہ یاطلاق دینے پر مجبورشخص یامذاق میں صیغۂ طلاق پڑھنے والے کا طلاق صحیح نہیں ہے ۔
٥۔طلاق کے وقت،عورت خون حیض کو سے پاک ہونا چاہئے اور پاک ہونے کے بعد شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو ۔
٦۔طلاق اپنے مخصوص صیغوں میں پڑھا جائے اوردو عادل کے سامنے انجام پائے ۔
طلاق کی قسمیں
طلاق کی دوقسمیں ہیں :
١۔طلاق رجعی :یہ وہ طلاق ہے کہ مرد اپنی اس بیوی کو طلاق دے کہ جس کے ساتھ ہم بستری کی ہو ۔اس صورت میں مرد طلاق کا عدہ تمام ہونے سے پہلے رجوع کرکے نئے عقد کے بغیر ازدواجی رابطہ کو پھرسے بر قرارکرسکتا ہے ۔
٢۔طلاق بائن :یہ وہ طلاق ہے ، کہ جس میں طلاق جاری ہونے کے بعد مرد رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے ۔اس کی چند قسمیں ہیں :
الف:عورت کے ساتھ مرد کے ہمبستری ہونے سے پہلے دیاجانے والاطلاق ۔
ب:یائسہ عورت کی طلاق،یعنی وہ عورت جس میں بچہ پید اکرنے کی صلاحیت موجودنہ ہو ۔
ج:اس عورت کی طلاق جس کی عمرابھی نوسال تمام نہ ہوئی ہو ۔
مذکورہ تین قسم کے طلاقوں میں عدہ نہیں ہے ۔
د:اس عورت کی طلاق جس کو تین مرتبہ طلاق دی گئی ہو۔اس طلاق میں اس کے علاوہ کہ مرد رجوع نہیں کرسکتا ہے،اسے پھرسے اپنے عقدمیں بھی نہیں لاسکتا ہے مگر یہ کہ یہ عورت کسی دوسرے مردکے عقد دائمی میں آجائے اوراس سے ہم بستری کی جائے پھر وہ مرداسے طلاق دیدے یامرجائے تواس صورت میں عدہ تمام ہونے کے بعدپہلا شوہر اس کے ساتھ پھرسے عقد کرسکتا ہے۔
ھ۔طلاق خلع:اس عورت کی طلاق جو اپنے شوہرکو پسند نہیں کرتی ہے اوراپنامہر یاکوئی اورمال اسے بخش کر اس سے طلاق حاصل کرے ،اس کو''خلع''کہتے ہیں ۔اس طلاق میں جب تک بیوی اپنے شوہر کو بخش دئے گئے مال کامطالبہ نہ کرے ،اس وقت تک مرد رجوع نہیں کرسکتا ہے ۔
طلاق مبارات:یہ وہ طلاق ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوںاور بیوی مرد کو کچھ مال دے اوراس کے مقابلہ میں وہ اسے طلاق دے ۔اس طلاق میں بھی جب تک بیو ی ا پنے اداکئے ہوئے مال کا مطالبہ نہ کرے،مرد رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے ۔
ز۔نواں طلاق:ان شرائط کے ساتھ جو فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اس طلاق کے بعدعورت مرد پرہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے اورکسی صورت میں اس کے ساتھ دوبارہ ازدواجی رشتہ برقرارنہیں کرسکتا ہے ۔
عدت کے احکام اور اس کی قسمیں
جس عورت نے اپنے شو ہر کے ساتھ ہم بستری کی ہو اورازدواج کے رشتہ کو مستحکم کیا ہو، اگر اس کاشوہراسے طلاق دیدے ،تو اسے ایک معین مدت تک عدہ رکھناچاہئے،یعنی اس مدت میں ازدواج کرنے سے پرہیز کرے ۔اس کام کے دواہم نتائج ہیں :
اول یہ کہ:نطفوںکے مخلوط ہونے سے بچایا جاسکتا ہے ۔
دوسرے یہ کہ:ممکن ہے اس مدت کے دوران میاں بیوی اپنی جدائی سے پشیمان ہوکر رجوع کریں ۔
عدہ کی مدت کے دوران مرد کو بیوی کے اخراجات کو اداکرناچاہئے اوراسے اپنے گھرسے نہ نکالے ۔اوراگریہ چوتھی بیوی تھی تو عدہ تمام ہونے تک دوسری عورت سے عقدنہ کرے۔اگرطلاق مرد کی مہلک بیماری کے دوران انجام پائے تو اس کے ایک سال کے اندرمرنے کی صورت میں بیوی اس کے ترکہ سے میراث لینے کی حقدار ہے ۔
عدت کی قسمیں
عدہ کی تین قسمیں :
١۔حاملہ عورت کا عدہ
٢۔غیرحاملہ عورت کاعدہ
٣۔عدہ وفات
ان کی تفصیل حسب ذیل ہے :
١۔اگرحاملہ عورت کو طلاق دی جائے تواس کاعدہ بچہ کی پیدائش یا اسکے سا قط ہونے تک ہے۔اس بناپر اگرطلاق دینے کے ایک گھنٹہ بعداسکابچہ پیداہو جائے تو وہ دوسراشوہر کرسکتی ہے۔
٢۔جوعورت حاملہ نہ ہواوراس کی عمر پورے نوسال ہو یا یائسہ نہ ہو،جبکہ اس کے شوہرنے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو اور حیض کے علاوہ دنوں میں طلاق دی ہوتواسے اتنا انتظار کرناچاہئے کہ دوبارحیض دیکھے اور پاک ہوجائے اور جوںہی تیسرے حیض کودیکھے گی اس کا عدہ تمام ہو جائے گا۔
٣۔جس عورت کا شوہر مر جائے اوروہ حاملہ نہ ہوتواسے چار مہینے دس دن عدہ رکھنا چاہئے۔اگرحاملہ ہو تو اسے بچے کی پیدائش تک عدہ رکھنا چاہئے لیکن اگر چار مہینے دس دن گزرنے سے پہلے، بچہ پیدا ہوجائے تواسے اپنے شوہرکے مرنے کے دن سے چارمہینے دس دن تک انتظار کرنا چاہئے اوراسے''عدہ وفات''کہتے ہیں ۔
____________________
۱۔وسائل الشیعہ ،ج١٥ ص٢٦٦ باب ۔
اسلام میں غلامی
شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے انسان پیداہوا ہے یہ فکر اس کے ہمراہ تھی کہ انسان کو بھی دوسری اشیاء کے ماننداپنی ملکیت قراردے سکتا ہے ۔
قدیم مصر،ھندوستان ،ایران ،عربستان ،روم ،یونان ،یورپ اور امریکہ کے تمام ممالک میں غلام بنانے کارواج تھا اوریہ رواج یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی عام تھا اسلام نے بھی اس میں کچھ تبدیلیاں لاکراسے جائز قراردیا ہے ۔
برطانیہ کی حکومت،پہلی حکومت تھی جس نے غلامی کی روش کی مخالفت کی اور١٨٣٣ئ میں سرکاری طورپر غلامی کے طرز عمل کو منسوخ کیا ۔اسکے بعدیکے بعددیگرے دوسرے ممالک نے بھی اس روش کی پیروی کی ۔یہاں تک کہ سنہ ١٨٩٠ء میں ''بروکسل''میں منعقد ایک مٹینگ میں ایک عمومی قانون کی حیثیت سے غلامی ممنوع قراردی گئی اورا س طرح دنیاسے غلام کی خریدو فروخت ختم ہوگئی ۔
غلام بنانے کے طریقے
ایسا لگتا ہے کہ یہ قدیم رسم انسان میں من مانی اوربے حساب رائج نہیں تھی کہ جوبھی چاہتا کسی دوسرے کو اپنی ملکیت میں لے لیتا ،بلکہ غلامی مندرجہ ذیل راہوں میں سے کسی ایک راہ سے انجام پاتی تھی:
١۔جنگ وفتح:قدیم الایام سے اگردوجانی دشمنوںمیں سے ایک،دوسرے پر فتح پاکر بعض افراد کو اسیر بناتا تھا ،تو وہ ان جنگی اسیروں کے لئے کسی انسانی احترام کا قائل نہیںہو تاتھابلکہ اپنے لئے ان کے ساتھ ہر طرح کابرتائو کرنے کاحق سمجھتا تھا۔یعنی قتل کرڈالے یا بخش دے یاآزاد کرے یاغلاموں کی حیثیت سے اپنے پاس رکھے اور ان سے استفادہ کرے ۔
٢۔تولید وتربیت :خاندان کے باپ ،خاندان کے سر پرست ہوتے تھے اور اپنی اولاد کو اجتماعی شخصیت کے مالک نہیں جانتے تھے بلکہ انھیں خاندان کے تابع اورمحض اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور خود کو ان کے بارے میں ہرقسم کا فیصلہ کرنے کامستحق سمجھتے تھے ۔اس لحاظ سے ضرورت کے وقت اپنی اولادکو بیچ دیتے تھے اوراسی اصل کی بنیاد پرکبھی عورتوں کو بھی بیچ دیتے تھے ۔
٣۔طاقت ور لوگ جواپنے آپ کودوسروں سے بلند سمجھتے تھے :ایسے افراداپنے حکم کولوگوں کانظم ونسق چلانے میں نافذ العمل جانتے ہوئے انھیں اپنا غلام شمارکرتے تھے۔ یہاں تک کہ بہت سے قدرتمند بادشاہ اپنے کو خدائی کے قابل جان کر لوگوں کواپنی پرستش کرنے پر مجبور کرتے تھے ،یہ افراد لوگوں کو اپنا غلام بنانے میں مطلق العنان تھے اوراپنے ماتحتوں میں سے جس کو بھی چاہتے،اسے اپنا غلام بناتے تھے۔
غلامی کے بارے میں اسلام کا نظریہ
اسلام نے اپنی اولاد اور عورتوں کو بیچنے کے ذریعہ اورزبردستی اورغنڈہ گردی کے ذریعہ غلا م بنانے سے منع کیا ہے ۔اسلام کی نظرمیں ہرانسان جوانسانیت کے راستہ پرگامزن ہے اورکم از کم انسانیت کے اصول کا دشمن نہ ہو،وہ آزاد ہے اور کوئی شخص اسے اپناغلام نہیں بنا سکتا ۔
لیکن جوانسانیت کا جانی دشمن ہے اور جان بوجھ کر انسانیت کے اصول کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا ہے اوراپنی پوری طاقت سے اسے نابود کرنے پر تلا ہوا ہے ،وہ ہرگز انسانی احترام کامستحق نہیں ہے اوراسے اپنے ارادہ وعمل میں آزاد نہیں ہونا چاہئے اورغلامی اس کے سواکچھ نہیںہے کہ انسان کے عمل وارادہ کی آزادی اس سے سلب کی جائے اوردوسرے کا ارادہ اس پر حکومت کرے اسی عالمی اصول پرجو ہمیشہ دنیا والوں کی طرف سے مورد تائید قرار پایا ہے کفارحربی سے لئے گئے جنگی اسیروں کو غلامی ،یعنی انھیں ارادہ وعمل کی آزادی سلب کرنے کی سزا دیتا ہے کیونکہ وہ انسانیت کے حقیقی دشمن ہیں۔
اسلام جو سلوک جنگی اسیروں کے ساتھ روا رکھتا تھا ، وہ وہی سلوک ہے جسے دوسرے بھی روا رکھتے ہیں ۔جب کوئی ملت جنگ کے بعدفاتح ملت کے سامنے کسی قید وشرط کے بغیرہتھیار ڈالتی ہے ،تو جب تک ان کے درمیان باقاعدہ صلح بر قرار نہ ہوتب تک اسے ارادہ وعمل کی آزادی سے محروم کرنے کی سزادی جاتی ہے ۔
ان ملتوں کا اسلام کے ساتھ جوتنہا اختلاف ہے،وہ یہ ہے کہ اسلام اسے''غلامی''کے نام پر یاد کرتا ہے اور یہ قومیں اس لفظ کو استعمال کرنے سے پہلوتہی کرتی ہیں ۔البتہ جس روش کووہ زندہ اور معاشرے کے لئے راہنما جانتے ہیں اپنی تعلیمات کی بنیاد کو نام گزاری کی بنیادپر استوارنہیں کرنا چاہئے ۔
اسلام اور دوسرے نظریات کی تحقیق
گزشتہ بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کو منسوخ کرنے والی عام قراردادنے بجائے اس کے کہ اسلام کے کام میں کوئی گرہ لگا ئے ،ایک گرہ کو کھول دیاہے ۔حقیقت میں یہ قرار داد دین اسلام کے قوانین کی ایک دفعہ کا نفاذہے کیونکہ اس طرح عورتوں اوربچوں کو بیچنے کا موضوع ختم ہوا ہے ،اوریہ وہی چیز ہے جسے چودہ سو سال پہلے اسلام نے منسوخ کیا تھا۔اسلام نے جنگی اسیروں کی غلامی کا جو راستہ کھلا رکھا ہے ،وہ اس لئے ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس حکم کی ضرورت ہے ،اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا .تنہا چیز جسے اسلام نے ''غلامی''کا نام دیا ہے وہ یہی جنگی اسراء ہیں ۔لیکن دوسرے لوگ ''غلامی '' کے نام کو زبان پر لائے بغیر عملاً''غلامی''کی رسم کو مستحکم کررہے ہیں ،اور جواستفادہ صدراسلام میں مسلمان (جنگی اسیروں )غلاموںسے کرتے تھے وہی استفادہ آج کی حکومتیں جنگی قیدیوں اور جنگ میں شکست کھائی ملتوں سے کرتے ہیں ۔
غلاموں کے ساتھ اسلام کاسلوک
اسلامی قوانین کے تحت،اسیر کئے گئے کفار حربی ،ممکن ہے مسلمانوں کے سرپرست اورحاکم کے حکم سے آزاد کئے جائیں یابطور غلام رکھے جائیں ۔
جنگ ہوازن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ہزار عورتوں اور بچوں کو ایک ساتھ آزاد کیا ۔جنگ بنی المصطلق میں مسلمانوں نے کئی ہزاراسیروں کو آزاد کیا ۔
اسلام میں ،غلام ،گھر کے اعضاء کے مانند ہیں ،گھر کے دوسرے اعضاء کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا ہے ویساہی برتائوان کے ساتھ بھی کیا جانا چاہئے ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے ۔
امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام دو کرُتے خریدتے تھے،ان میں سے بہتراپنے غلام کودیتے تھے اورمعمولی کرُتے کو خودپہنتے تھے ۔
حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے غلاموں اورکنیزوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے ۔
اسلام حکم دیتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں ،ان کے ساتھ سختی نہ کریں ، گالیاں نہ دیں اور جسمانی اذیتیں نہ پہنچائیں اورضرورت کے وقت ان کے ازدواج کے وسائل فراہم کریں یاخود ان کے ساتھ ازدواج کریں ۔خدائے متعال اس سلسلہ میں فرماتا ہے :
(...( بعضکم من بعض ) ...) (نساء ٢٥)
''سب ایک پیکر کے اعضاء ہیں''
اسلام میں ،غلام،اپنے مالک کی اجازت سے یادوسرے راستہ سے،مالک بن سکتے ہیں اور جس مال کے وہ مالک بن جائیں ،آزادی کے بعدان کے لئے کسی قسم کا ننگ و عار نہیں ہے ،جیسے کہ غلامی کے زمانہ میں بھی نہیں تھا .کیونکہ اسلام میں بزرگی اورفضیلت کا معیارصرف تقویٰ ہے لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کو سب سے بہتر جانتا ہے۔اسلام کی نظرمیں ایک باتقوی غلام ہزاربے تقوی آزاد لوگوں سے بہتر ہے ۔
اسلام کی بعض عظیم شخصیتیں جیسے سلمان فارسی اوربلال حبشی آزاد کئے گئے غلام تھے .اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کے مسئلہ کو ہمیشہ مد نظر رکھاہے اور اس کام کے لئے مختلف راستے کھولے ہیں منجملہ جرمانہ اور بعض گناہوں کا کفارہ غلاموں کی آزادی کے لئے قراردیا ہے ،اس کے علاوہ غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اسے اہم مستحبات میں قراردیا ہے تاکہ اس طرح ہرسال بہت سے غلام آزادہو کرآزاد معاشرے کے عضوبن سکیں ۔
نتیجہ یہ تھا کہ اسلام حتی الامکان غیراسلامی معاشروں (کفار حربی) سے ایک گروہ کو جنگی اسیروں کی صورت میں پکڑتاتھا اور انھیں حق وعدالت کے معاشرے میں داخل کرتاتھا ،ان کی تعلیم وتربیت کرتا تھا ،پھر مختلف راستوں سے آزاد کرکے اسلامی معاشرے کا حصہ بناتا تھا ۔
اس لحاظ سے جوشخص بھی جنگی اسیرہوتاتھا ،آزاد ہونے تک غلام رہتا تھا۔اگر وہ مسلمان ہونے کے فوراًبعدآزاد ہوتا ،تواس صورت میں ممکن تھا ہراسیر ہونے والا کافر، ظاہراً مسلمان ہوجاتا، اوراس طرح اپنے آپ کونجات دلاتا اورتھوڑی ہی دیر کے بعدپھرسے اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹ جاتا۔
غصب
جو شخص کسی کے مال کو زبردستی اس سے چھین کر،مالکیت کے اسباب میں سے کسی سبب کے بغیراسے اپنامال قراردے یاکسی دوسرے کے مال پرزبردستی قبضہ کرکے استفادہ کرے ،اگرچہ اسے اپنا مال قرارنہ دے ،اس عمل کو شرعاً''غصب''کہتے ہیں ۔
لہذا،تسلط جمانے کے کسی جائز سبب جیسے :بیع ،اجارہ اور اجازت کے بغیرکسی دوسرے کے مال پرقبضہ جمانے کو غصب کہتے ہیں ۔یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ غصب، ایک نامناسب کام ہے جو مالکیت کی خصوصیت کی بنیاد کو پامال کرتا ہے۔جس قدرمالکیت کی خصوصیت کی بنیادمعاشرے کے زندہ اورپائیدار رہنے میں موثرہے اسی قدرغصب معاشرے کو برباد کرکے اس کی ترقی کو روکتا ہے ۔
اگریہ طے پاجائے کہ معاشرے کے اثرو رسوخ رکھنے والے افراد قانون کی اجازت کے بغیرکمزوروں اوراپنے ماتحتوں کی کمائی پر قبضہ جمائیں توخصوصیت اورمالکیت اپنے اعتبارکو کھودے گی۔ہرایک اپنے سے کمزورلوگوں کے خصوصی حقوق کے بارے میں اسی طرز فکر پر عمل کرے گااورماتحت اورکمزورلوگ بھی اپنی محنت و مشقت کی کمائی کی حفاظت کے لئے ہرممکن اقدام کرکے عزت وشرافت فروشی پر مجبور ہوں گے۔اور نتیجہ میں انسانی معاشرہ غلاموں کے خریدو فروخت کے ایک بازار میں تبدیل ہو کر رہ جائے گا اورقوانین و ضوابط اپنے اعتبار سے گر جائیں گے اور ان کی جگہ پر ظلم وستم جانشین ہوگا ۔
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غاصب کے لئے سخت قوانین وضع کئے ہیں اورغصب کو گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔
قرآن وسنت کی نص کے مطابق،شرک کے علاوہ ہرقسم کے گناہ کو خدا کی طرف سے بخش دئے جانے کا احتمال ہے ۔اورہرگناہ حتی شرک بھی توبہ کے ذریعہ قابل عفو وبخشش ہے ۔لیکن جس کی زندگی کے ریکارڈمیں دوسروں کے حقوق کے بارے میں غصب اورظلم وستم درج ہو،تواس کے لئے کسی بھی صورت میں حقدار سے بخشش حاصل کئے بغیر خدا کی پوچھ گچھ اورسزا سے بچنے کی اُمید نہیں ہے ۔
غصب کے بعض احکام
١۔ غاصب پر واجب فوری ہے کہ غصب کیاگیا مال ،مالک کو لوٹادے ،اوراگروہ زندہ نہ ہوتواسے اس کے وارثوں کے حوالہ کردے ،اگرچہ اس مال کا واپس کرنا غاصب کے لئے کافی نقصان کاسبب بنے ۔مثال کے طور پر کسی کاپتھریا لوہے کا ایک ٹکڑاغصب کر کے اپنے مکان کی بناء میں نصب کرے جواس کے لاکھوں برابرقیمت پر تعمیرہوئی ہو ،تو مکان کوگراکر اس پتھر اورلوہے کے ٹکڑے کو نکال کراس کے مالک کو لوٹادے ،مگر یہ کہ اس کا مالک اس کی قیمت حاصل کرنے پر راضی ہو جائے ۔یااس کے مانند کسی نے دس من گندم غصب کرکے دس خروارجوسے مخلوط کیا ہو ،اگر گندم کامالک اس کی قیمت لینے پرراضی نہ ہو جائے تواسے عین گندم کو جوسے جداکرکے مالک کو واپس کرنا چاہئے ۔
٢۔اگرغصب کئے گئے مال میں کوئی نقص پیدا ہوجائے ،توعین مال کو واپس کرنے کے علاوہ نقصان کی تلافی بھی کرنا چاہئے ۔
٣۔اگرغضب کیاگیا مال تلف ہو جائے تواس کی قیمت اداکی جانی چاہئے۔
٤۔اگرغاصب ، غصب کئے گئے مال کے کسی حصہ کو ضائع کردے ، تو چاہے اس نے خوداس سے استفادہ نہ کیا ہو تو بھی وہ اس مال کے منافع کا ضامن ہے،جیسے،کسی نے کرایہ کی گاڑی کو غصب کرکے کئی دن تک اسے گیرج میں رکھاہو ۔
اسی طرح اگرغاصب ،غصب کئے گئے مال میں اضافہ کردے،جیسے ایک بھیڑکو غصب کرنے کے بعداسے اچھی گھاس کھلا کرفربہ بنادے تواس اضافہ میں کوئی حق نہیں رکھتا ہے البتہ اگرمذکورہ اضافہ منفصل ہو،یعنی ایک زمین کوغصب کرکے اس میں کا شتکاری کرکے زراعت حاصل کرے توغصب کیاہوامال اجرت کے ساتھ مالک کولوٹادے اورزراعت غاصب کی ہوگی ۔
لُقطہ
جوبھی مال پایا جائے اوراسکا مالک معلوم نہ ہواسے ''لُقطہ''کہتے ہیں :
١۔جومال پایا جائے اوراس کا مالک معلوم نہ ہو،اگراس کی قیمت ایک مثقال(۱) چاندی سے کم ہو،تواسے اٹھاکر خرچ کیا جاسکتا ہے اوراگراس کی قیمت ایک مثقال چاندی سے زیادہ ہو تواسے نہیں اٹھاناچاہئے اوراٹھانے کی صورت میں عادی راہوں سے ایک سال تک اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہئے اورمالک کو ڈھونڈلینے کی صورت میں اس کے حوالہ کرنا چاہئے اوراس کامالک نہ ملاتواس مال کواسکی طرف سے کسی فقیر کوصدقہ دینا چاہئے ۔
٢۔اگرکسی مال کوایک ایسی ویران جگہ میں پایاجائے جس کے باشندے نابود ہوچکے ہوں یاغاراور اس بنجر زمین میں پایاجائے کہ جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ تو پایاگیا مال پانے والے کا ہے ،اوراگرمال ایسی زمین میں ملے جو کسی کی ملکیت ہو تو اس کے گزشتہ مالکوں سے دریافت کیا جانا چاہئے ،اگرانہوں نے اس کو چھپایاہو توعلامت ونشانی بتانے کی صورت میں دیا جائے ورنہ یہ مال پانے والے کا ہے ۔
بنجر زمینوں کوآباد کرن
ایسی زمین کوآباد کرنا جس سے استفادہ نہیں ہوتاتھا (خواہ وہ زمین کبھی آبادنہیں تھی ،یاکبھی آبادتھی لیکن وہاں کے باشندوں کے معدوم ہونے کی وجہ سے غیرآ باداوربے فائدہ رہی ہو یامرغ زاروں یانرسل زاروں کے مانند)۔بہر حال زمینوں کوآباد کرنااسلام میں نیک کام شمارہوتا ہے اور مالکیت کاسبب بننے کے علاوہ اخروی ثواب بھی رکھتا ہے۔
پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ :
''جو کوئی شخض کسی بنجرزمین کوآباد کرے ،وہ زمین اس کی ہے۔''(۲)
حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ:
''اگر کوئی گروہ کسی بنجر زمین کوآباد کرے ،تووہ اولویت کاحق رکھتا ہے اوروہ اس زمیں کا مالک ہے ۔''(۳)
اسلام میں بنجر زمینوں کا مالک خدا،رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم اورامام ہے ( اسلامی حکومت سے مربوط ہیں)اورانفال میں شمار ہوتی ہیں ۔بنجرزمینوں کو مندرجہ ذیل شرائط سے آبادکرکے ان کامالک بن سکتے ہیں ،اوراگرکئی افرادملکیت کاقصد کریں توجو پیش قدمی کرے گا وہ اولویت کاحق رکھتاہے:
١۔امام یاان کے نائب کی اجازت سے۔
٢۔کسی دوسرے شخص نے پہلے اس کی پتھروں سے نشاندہی یاحدبندی نہ کی ہو۔
٣۔دوسروں کی ملکیت کے حدود سے متصل نہ ہو،جیسے نہر کے اطراف کنویں کے پشتے میں اورکھیت کی سرحد سے ملی نہ ہو۔
٤۔خالی زمین ،جیسے خراب شدہ مسجدیا اوقاف ، عام مسلمانوں کی زمین جیسے کوچے اورسڑکیں نہ ہوں۔
نوٹ
تعمیر اور آباد کرنا ایک عرفی مفہوم ہے ،اس لئے جب عرف کہے:''ایک شخص نے فلاں زمین آ باد کی ہے'' مالکیت تحقق پاتی ہے ۔البتہ آباد کرنا بھی مختلف مقاصدکے پیش نظر مختلف ہے ۔چنانچہ کھیتی باڑی میں ہل چلانے سے آباد کرنا عمل میں آ تا ہے اور عمارت بنانے میں دیواربنانے سے ثابت ہوتا ہے ،یہاں تک کہ حاضرلوگوں میں سے ہرایک کھدائی اوراستخراج کے بغیر اس سے استفادہ کرسکتا ہے،ہرایک کے لئے جائزہے کہ ضرورت کے مطابق اس سے استفادہ کرے اور اگران کااستفادہ کرنا کھدائی اوراستخراج اوردیگر فنی کاموں پر منحصرہو ،جیسے سونا اورتانباوغیرہ تو جو محنت ومشقت سے کھدائی وغیرہ کرکے استخراج کرے وہی مالک ہوگا۔
بڑی نہریں مسلمانوں میں مشترک ہیں اسی طرح دریا اور برف وباران کاپانی جو پہاڑوں سے بہہ کر نیچے آتا ہے ،جو بھی ان کے نزدیک اورآگے ہو وہ دوسروں پر مقدم ہے ۔
تخصیص اور مالکیت کی اصل
یہی عقیدہ کہ انسان زمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے ،اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے مظاہر سے آ سانی کے ساتھ استفادہ کرے ۔مثلاًاس کازلال پانی پئے ،میٹھے میوے اورحیوانوں کا گوشت کھا ئے ،پہاڑوں کے درّوں میں درختوں کے سائے میں آ رام کرے ،یاصنعت ۔یعنی مادہ پرانجام دی سر گرمیوں کواپنی مرضی کے مطابق استعمال میں لائے ۔
البتہ اگرصرف چند افراد زمین پرایسی زندگی گزارتے کہ آ پس میں کوئی ٹکراو نہ ہوتا توہرگز کوئی مشکل پیش نہ آتی ،لیکن افراد کا جمع ہونا اور ان کا باہم زندگی گزارنا جوانسان کی اجتماعی شہری زندگی کی بنیاد ہے ،کہ ہرفرد زمین اوراس کے مظاہرکو اپنی ملکیت سمجھ لے تو،قدرتی طورپر لوگوں کے درمیان ٹکرائواورشدید تصادم کاسبب بن جائے گا ،جب ہر شخص اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی تلاش وکوشش کرے گا،تودوسرے اسے اپنی آزادی وآسائش میں مخل سمجھتے ہوئے اس کے لئے رکاوٹ ایجاد کریں گے،کیونکہ انسان اپنی زندگی کو ہرقیمت پر جاری رکھنے کے لئے مجبور ہے۔
اس لئے پہلے''اصل تخصیص'' کے نام پر ایک اصل وقانون وضع کیاگیا،تاکہ اجتماعی ٹکرائواورتصادم کو روکا جائے ۔اس اصل کوقابل احترام سمجھا گیا ہے ۔اس اصل و قانون کے مطابق،انسان جس چیز کواپنی سعی وکوشش سے حاصل کرے وہ ا س کا مالک ہے اوردوسروں کواس پر طمع ولالچ کرکے اس کے لئے رکاوٹ پیدا کرنے کاحق نہیں ہے۔ اس کے بعد''اصل مالکیت''کے نام پرایک اوراصل وضع کرکے اسے قابل احترام سمجھا گیا ہے کہ اس کے مطابق انسان اپنی کوششوں سے حاصل کی گئی چیزوں پراپنی مرضی سے تصرف کرسکتا ہے ۔
یہ اصل حقیقت میں ''اصل تخصیص'' کو مکمل کرنے والی ہے ۔کیونکہ''اصل تخصیص''دوسروں کی خلل اندازی کوروکتی ہے اوریہ اصل اس چیز کی مالکیت کے لئے ہر قسم کے تصرف کو جائز بنادیتی ہے ۔
اسلام نے مالکیت کی اصل کومحترم جاناہے اورپیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معروف حدیث (الناس مسلطون علی اموالهم )(۴) میں مالک کے اپنے مال پرمکمل تسلط کی تائید فرمائی ہے ۔
اس قانون کے مطابق انسان جس طرح چاہے اپنے مال کو استعمال کرسکتا ہے ،اس کی حفاظت کرسکتا ہے ،کھاسکتا ہے ،پی سکتا ہے ،بخش سکتا ہے ،بیچ سکتا ہے اوراسی طرح دوسرے جائز تصرفات انجام دے سکتا ہے ،لیکن جوتصرفات ممنوع اور معاشرہ کی مصلحت کے خلاف ہیں مالک کوان کاہرگزاختیارنہیں ہے ۔
مالک اپنے مال پروہ تصرف نہیں کرسکتا ہے جواسلام ومسلمین کے نقصان میں ہو یااسراف اور فضول خرچی سے اپنے مال کونابود نہیں کرسکتا ہے،یا اپنے سونے اورچاندی کے سکّوں کوجاری نہ رکھ کر خزانہ کے طورپر جمع نہیں کرسکتا ہے ۔
اصل مالکیت ،اہم ترین اصل ہے جوانسان کواپنی آرزوتک پہنچاتی ہے اورقوانین کی رعایت کے سایہ میں انفرادی آزادی کوامکان کی آخری حد تک فراہم کرتی ہے ۔
جتنامال کی نسبت انسان کاتسلط یا اس کے کار وکوشش کے بارے میں اسکا اختیارکم ہوجائے گااتنی اس کی آزادی سلب ہو جائے گی اور اس کا استقلال نابود ہوجائے گا اور اگراصل تسلط بالکل نابودہو جائے ،توحقیقت میں ایک زندہ مخلوق سے اس کی اصل آزادی چھین لی جائے گی۔
اصل مالکیت کے دوتتمے
مالک کا اپنی ملکیت پر مکمل تسلط اور اس کے ہر جائز تصرف میں مطلوب آزادی ،ممکن ہے دوراستوں سے خطرہ میں پڑ جائے :
١۔دوسروں کی طرف سے تجاوز کی وجہ سے،جیسے کوئی اس کی ملکیت پر قبضہ کرکے اس کے لئے استفادہ کے راستہ کو مسدود کر دے۔
٢۔اس راستہ سے کہ دوسرے ایسا کام انجام دیں جس سے مالک کونقصان پہنچے۔
دین اسلام نے مذکورہ خطرات کو روکنے کے لئے دومزیداصلوں کووضع کیا ہے کہ اصل مالکیت خودبخودحاصل ہوتی ہے کہ حقیقت میں یہ دواصلیں اسکے نفاذاورحفاظت کی ضامن ہیں :
الف:اصل ضمان :اسلام اس اصل کے مطابق حکم دیتا ہے کہ جو بھی دوسرے کے مال کوپائے ،وہ اسکاضامن ہے ،یعنی اس کو وہ مال مالک کو لوٹادیناچاہئے اوراگر ضائع ہوجائے تو اسکے مانند یاقیمت اداکرے اس حکم کی دلیل ،پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حد یث ہے:
''علی الید مااخذت حتی تؤد''
ب:قائدہ لاضرر: اس قائدہ کو حدیث نبوی (لاضررولاضرار فی الاسلام)سے استدلال کیا جاتاہے ۔اس قائدے کے مطابق اگر اسلام کا کوئی بھی حکم جاری کرنے میں کسی شخص کوبعض مواقع پرمالی یاجانی نقصان پہنچائے،تو وہ حکم اس مورد میں ، جاری نہیں ہوگا۔
جن چیزوںکو ملکیت بنایاجاسکتا ہے
دین مقدس اسلام میں ان چیزوںکوملکیت بنایا جاسکتیں ہے :
١۔قابل توجہ فائدہ ہو،مثال کے طور پرحشرات قابل ملکیت نہیں ہیں ۔
٢۔مذکورہ فائدہ حلال ہو،اس بناء پرجوئے کے وسائل،موسیقی کے آلات اوران کے مانند،جن کاحلال فائدہ نہیں ہے،کسی کی ملکیت نہیں ہوسکتے۔
١۔احکام ضمان کے دوحکم:
الف:اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ملکیت کوغصب کرے،یعنی مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے قبضہ میں لے لے یا مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے نہ دے ،اسلام کے حکم کے مطابق فوراًاسے مالک کوواپس کرے اوراگر یہ ملکیت ضائع ہو جائے تو اسکے مانند یا اس کی قیمت اداکرے اور اگر غصب کرنے کی وجہ سے مال کے مالک کو کوئی نقصان پہنچے توغاصب اس کاذمہ دار ہے ۔
ب:اگر کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرے ،لیکن مالک کو بھی تصرف کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔تو خود مال اگرتلف ہوجا ئے تو اس کے مانندیاقیمت مالک کودے، ضمان کے احکام ومسائل بہت زیادہ ہیں ،تفصیلات جاننے کیلئے فقہی کتابوںکی طرف رجوع کریں ۔
٣۔مذکورہ حلال فائدہ کسی فردیاچندافراد کی تخصیص کے قابل ہو ۔اس بناء پرمساجد،عام سڑکیں اور ان کے مانند چیزیں ،جو معاشرے کے تمام لوگوں سے مربوط ہوتی ہیں ،کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں بن سکتی ہیں ۔
جن چیزوں سے انسان مالک بن سکتا ہے
ما لک بننے کے لئے،انسانی معاشرے میں بہت سے وسائل موجود ہیں ،لیکن ان میں سے بعض جیسے جوا ،شرط لگانا،سودخواری اور رشوت ،چونکہ معاشرے کیلئے مضر ہیں ،اس لئے اسلام نے ممنوع فرمایا ہے ۔لیکن دوسرے وسائل مانند:بیع،اجارہ ،ھبہ اورجعالہ، جومعاشرے کے لئے مفید ہیں ،ان میں کچھ اصلاح کر کے انھیں قبول کیاہے اور کلّی طورپر اسلام کی نظر میں مالک بننے کے دو وسیلے ہیں :
١۔وہ جس کے انجام دینے میں کوئی لازم ہو جیسے :خرید وفروخت کہ اس کوانجام دینے کے لئے عقدبیع پڑھنایا لین دین کا ہونا ضروری ہے۔
٢۔وہ جس میں کسی عمل کی ضرورت نہیںہے ،جیسے:وفات کہ اس کے ذریعہ مالک کا مال وارثوں کو منتقل ہو تا ہے اور اس میں کسی لفظ یاعمل کی ضرورت نہیں ہے ۔
میراث اورنکاح کے احکام کی اہمیت کے پیش نظر ہم ان سے مربوط کلی مسائل بیان کرتے ہیں۔
____________________
١۔تقریباًساڑھے تین گرام۔
۲،۳۔میزان الحکمة،ج١،ص٩٤ ۔
۴۔عوالی اللئالی،ج١،ص٤٥٧ ۔
کھانا پینا
دین مقدس اسلام میں ،ہر وہ چیزجو کھانے اورپینے کے قابل ہو،حلال ہے لیکن چند استثنائی چیزوں کے علاوہ ،کہ ان میں سے بعض قرآن مجید میں اوربعض احادیث پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئی ہیں۔
مذکورہ استثنائی چیزیں جن کا کھانا اور پینا حرام ہے ،دوقسم کی ہیں :
جان دار اور بے جان ۔
پہلی قسم :حیوانات
حیوانات تین قسم کے ہیں :دریائی ،خشکی ،اورپرند ے۔
الف۔ دریائی حیوانات:
پانی میں رہنے و الے حیوانوں میں صرف آبی پرندے اور چھلکے دار مچھلیاں حلال گوشت ہیں اور باقی جیسے سانپ مچھلی ،سگ مچھلی ،مگرمچھ ،سمندری کتا اورسور وغیرہ حرام ہیں ۔
ب۔خشکی کے حیوانات:
خشکی کے حیوانات دوقسم کے ہیں :(پالتواورجنگلی)
پالتو جانوروں میں ،بھیڑ،بکری ،گائے اوراونٹ حلال گوشت ہیں ۔اسی طرح گھوڑا،خچر اورگدھاحلال ہیں ،لیکن ان کاگوشت کھانا مکروہ ہے اور ان کے علاوہ جیسے کتااو بلی حرام ہیں ۔
جنگلی حہوانوںمیں گائے،مینڈھا،جنگلی بکری ،جنگلی گدھااورہرن حلال گوشت ہیں اورباقی درندے اور ناخن دار حیوانات ،جیسے :شیر ،چیتا ،بھیڑیا ،لومڑی ،گیڈر اور خرگوش ،حرام گوشت ہیں۔
ج۔پرندے:
پرندوں میں سے جن کے پوٹا اور ،سنگ دانہ ہو یا اڑتے وقت پر مارتے ہوں اورناخن نہ رکھتے ہوں ، جیسے پالتومرغی ،کبوتر ،فاختہ ،اورتیترحلال گوشت ہیں اور باقی حرام گوشت ہیں اورٹڈی کی ایک خاص قسم حلال گوشت ہے ان کی تفصیلات کے لئے توضیح المسائل کی طرف رجوع کیا جائے۔
نوٹ
گوشت کے حلال ہونے کے بارے میں جن حیوانوں کانام لیاگیا ،اس میں تزکیہ کی شرط ہے یعنی توضیح المسائل میں دی گئی تفصیل اور طریقہ سے ذبح کرنا۔
دوسری قسم :بے جان اشیائ
بے جان چیزیں دوقسم کی ہیں :
الف۔جامد(ٹھوس)
ب۔سیال چیزیں
الف :جامد چیزیں
١۔ہر حیوان کامردارخواہ حرام گوشت ہو یاحلال گوشت،اس کا کھاناحرام ہے ۔
اسی طرح نجس چیزیں ،جیسے:حرام گوشت حیوانوں کا فضلہ اور وہ کھانے کی چیزیں جونجاست کے ملنے سے نجس ہوگئی ہوں کا کھانا حرام ہے۔
٢۔مٹی
٣۔مہلک زہر
٤۔وہ چیزیں جن سے انسان فطری طورپرمتنفرہو،جیسے حلال گوشت حیوان کافضلہ اور اس کی ناک کاپانی اورجوکچھ اس کی انتڑیوںسے نکلتا ہے ۔اسی طرح حلال گوشت حیوان کے بدن کے اجزاء میں سے پندرہ چیزیں حرام ہیں (تفصیل کے لئے توضیح المسائل کی طرف رجوع کیا جائے)
ب: سیال چیزیں
١۔مست کر نے والی ہر رقیق چیز،اگرچہ کم ہی ہو اس کاپینا حرام ہے۔
٢۔حرام گوشت حیوانات کادودھ ،جیسے سور ،بلی اور کتّا۔
٣۔خون جہندہ رکھنے والے حیوان کاخون ۔
٤۔نجس مائعات،جیسے خون جہندہ رکھنے والے حیوانوںکا پیشاب اور منی وغیرہ ۔
٥۔وہ مائعات جن میں نجاستوں میں سے کوئی ایک مل گئی ہو۔
نوٹ
کھانے پینے کی حرام چیزیںاس وقت حرام ہیں جب اضطرارنہ ہو اوراضطرار کی صورت میں (جیسے:اگرکوئی شخص حرام غذا نہ کھائے تو بھوک سے مر جائے گا ، بیمارپڑنے یابیماری کے شدید ہونے سے ڈرتا ہو یاکمزور ہوکر سفر میں اپنے ہمسفروں سے پیچھے رہ کر ہلاک ہوجائے گا)کھانے پینے کی حرام چیزوںمیں سے اس قدر کھانا جائز ہے ،کہ اس کااضطرار دور ہوجائے .لیکن جوچوری کے لئے یا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے وطن سے باہر آکرمضطر ہوجائے تو اس کیلئے جائز نہیںہے ۔
ایک اہم یاد دہانی
حفظان صحت کی رعایت ،انسان کے بنیادی فرائض میں سے ہے کہ ہرانسان خداداد شعور کے ذریعہ تھوڑی توجہ سے اس کے بارے میں معلوم کرسکتا ہے ۔
حفظان صحت پر مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزوں کے اثرات بھی بالکل واضح ہیں ۔اس کے علاوہ یہ چیزیں انسان کی روح واخلاق اور اسی طرح اس کے اجتماعی میل ملاپ پر بھی قابل توجہ اثرات ڈالتی ہیں ۔
ہمیں ہر گزاس میں شک وشبہ نہیں ہے کہ مست انسان کی نفسیاتی حالت اور اس انسان کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی جو ہوش میں ہے۔ اور ان کی اجتماعی گردش بھی ایک جیسی نہیں ہے ۔
یا اگر کوئی شخص مثلاًنفرت آمیزچیزوں کو کھانے کی عادت کرے ،اور اس عادت سے جواثراس کی انفرادی اوراجتماعی زندگی میں پیدا ہوگا ،وہ عام افرادکے لئے قابل برداشت نہیں ہے ۔
یہاں پر انسان اپنی خدادادفطرت سے سمجھتا ہے کہ اسے اپنے کھانے پینے میں کم وبیش محدودیت کا قائل ہوناچاہئے ،ہر کھانے والی چیز کو نہ کھالے اور ہر پینے والی چیز کو نہ پی لے ۔آخر کارہرنگلنے والی چیز کونہ نگل لے۔
خدائے متعال نے اپنے کلام پاک کی نص کے مطابق زمین پرموجود ہرچیز کوانسان کے لئے خلق کیا ہے اور خدائی متعال خود ،انسان اورانسان کی ضروریات زندگی کی چیزوں کامحتاج نہیں ہے اوراپنی مخلو قات کے فائدہ ونقصان کے بارے میں سب سے زیادہ دانااور بیناہے۔انسان کی خیروسعادت کے لئے کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے بعض کوحلال اوربعض کو حرام قراردیا ہے ۔
بعض ان محرمات کوحرام قراردینے کا فلسفہ ،سادہ اوربے لاگ سوچ رکھنے والوں کے لئے واضح ہے اوربعض حکمتیں علمی بحثوں کے ذریعہ تدریجا ًواضح ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے حرام ہونے کافلسفہ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہوسکا ہے،ان کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہرگزہمارے لئے واضح نہیں ہوں گی اور اگرواضح بھی نہ ہو ں تب بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ان میں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔بلکہ اس کے پیش نظرکہ قوانین کا سرچشمہ خدائے متعال کا بے انتہا علم ہے ،اس لئے کہنا چاہئے کہ اس میں بہترین اورموثر ترین حکمت ومصلحت ہوگی اگرچہ ہم اپنی تنگ نظری اورمحدود علم کی وجہ سے اس کودرک کرنے سے عاجزاوربے بس ہیں ۔
میراث کے کلی مسائل
عالم طبیعت میں میراث کاموضوع،ایک کلی قانون ہے جوتخلیق کی توجہ کامرکز رہاہے اورہر ایک نسل اپنے اسلاف کی ذاتی خصوصیتوں کو میراث کے طور پر حاصل کرتی ہے ،''گندم ازگندم برویدجوازجو''۔
انسان بھی کسی حدتک اپنے اجدادکے اخلاق،صفات اور ان کے وجودی اوصاف کو میراث میں حاصل کرتے ہیں اسی ذاتی میل میلاپ اور ہما ہنگی کا سبب ہے کہ انسان عام حالت میں اپنے رشتہ داروں کی نسبت ایک خاص دلچسپی کو محسوس کرتا ہے اوربالخصوص اپنی اولادکو اپنا جانشین سمجھ کران کی بقاکو بالکل اپنی بقاجانتا ہے اور قدرتی طورپرجو کچھ اس کی ملکیت ہے،جسے اس نے محنت وزحمت اور کام وکوشش کرکے حاصل کیا ہے اوراپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے ،اسے اپنی اولاد کی ملکیت جانتا ہے بلکہ اپنے رشتہ داروں کی ملکیت جانتا ہے ۔
اسلام بھی اسی فطری درک واحساس کے لحاظ اوراحترام کے پیش نظر انسان کے مال کواس کے مرنے کے بعد اس کے زندہ رشتہ داروں سے متعلق جانتا ہے اور میاں بیوی کوبھی جونسب اور ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہونے کے بانی ہیں رشتہ داروں میں شامل کرتا ہے ۔پہلے طبقہ کونسبی وارث اوردوسرے طبقہ کوسببی وارث جانتا ہے ۔
اس بناپر، مرنے والے کا مال ،اس کے نسبی اورسببی وارثوں میں ایک معین قانون کے مطابق تقسیم ہوگا ،لیکن کچھ افرادایسے ہیں جو میراث سے محروم ہیں ،یہاں پر ان میں سے دوافراد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:
١۔کافرکومسلمان کی میراث نہیں مل سکتی ہے ۔اس کے علاوہ اگر کوئی کافر مرجائے اوراس کے وارثوں میں کوئی مسلمان ہوتو اس کے کافر رشتہ دارمیراث نہیں پائیں گے۔
٢۔قاتل،اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو قتل کردے تو قاتل اس کی میراث نہیں پائے گا،لیکن قاتل کی اولاد میراث سے محروم نہیں ہیں ۔
نسبی وارث(رشتہ دار)
نسبی وارث،رشتہ کے نزدیک اوردور ہونے اور رشتہ کارابطہ ہونے یانہ ہونے کے سبب ،تین طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں ،کہ ہرطبقہ کے ہوتے ہوئے بعد والاطبقہ میراث نہیں پائے گا اوران تین طبقوں میں سے کسی ایک کے نہ ہونے کی صورت میں ،میراث ایک خاص ضابطہ کے تحت تقسیم ہوتی ہے ،جس کابعد میں ذکر کیا جائے گا۔
خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے :
( (...و اولواالار حام بعضهم اولی ببعض ) ...) (انفال٧٥)
''...بعض رشتہ داربعض دوسروں پر زیادہ اولویت رکھتے ہیں ''
نیز اپنے کلام میں آٹھ آیتوں کے ضمن میں وارثوں کے طبقوں اور ان کے حصوںکو بیان فرمایا ہے:
پہلاطبقہ
مرنے والے کے باپ،ماں ،بیٹا اوربیٹی ،جو مرنے والے کے براہ راست رشتہ دار ہیں،مرنے والے کے کوئی بیٹااوربیٹی نہ ہونے کی صورت میں ان کاحصہ ان کی اولاد کو ملے گا ،لیکن جب تک مرنے والے کی اولادمیں سے کوئی ایک بھی ہوتو مرنے والے کی اولاد کی اولاملے گی ۔ مثلاًاگرمرنے والے کے باپ ،ماں اوراس کے بیٹے کاایک بیٹااوربیٹی ہوتو،مرنے والے کے بیٹے کا حصہ مرنے والے کے بیٹے کے بیٹے اوربیٹی کو ملے گا اور ان میں تقسیم ہوگا اور اگرمرنے والے کے بیٹے کے بیٹے اوربیٹی کی کوئی اولادہوتو اسے کچھ نہیں ملے گا ۔
دوسراطبقہ
مرنے والے کے دادا،دادی ،نانا ،نانی اور بھائی اوربہن ہیں ،جو ایک واسطہ سے (باپ یاماں کے واسطہ سے) مرنے والے کے رشتہ دار ہیں ۔
اس طبقہ میں بھی بھائی یابہن کی اولاد کو،ان کے ماں باپ کاحصہ،اگر وہ مرگئے ہوں،تومرنے والے کے طورپر ملے گا۔ اور جب تک بھائی اور بہن کی کوئی اولادزندہ ہو تو اولاد کی اولادکومیراث نہیں ملتی ہے۔
نوٹ
مرنے والے کے اگرپدری بھائی بہن بھی زندہ ہوںاورپدری ومادری بھائی بہن بھی زندہ ہوں تواس کی میراث پدری بھائی بہنوں کو نہیں ملے گی ۔
تیسراطبقہ
چچا، پھوپھی ،ماموں اورخالہ ہیں ،جو دوواسطوں سے(باپ یاماں یادادا یادادی) مرنے والے کے رشتہ دارہوتے ہیں ۔اس طبقہ میں بھی اولاداپنے ماں باپ کی جگہ پر ہیں اورجب تک مرنے والے کے ماں باپ کی طرف سے ایک شخص بھی زندہ ہوتوباپ کے رشتہ داروں کو میراث نہیں ملتی ۔
میراث کے حصے
اسلام میں مذکورہ وارثوں میں سے ہر ایک کے میراث کے حصے،علم ریاضی کے مطابق نہایت توجہ اور دقت کے ساتھ منظم ومر تّب کئے گئے ہیں اورتمام حصے تین قسم کے ہیں :
١۔وہ ورثا ورء جن کی میراث کاحصہ نصف ،ایک تہائی اور اس کے مانند ہے ان کی عددی نسبت معین ہے ۔فقہ میں ان حصوں میں سے ہرایک کو ''فرض''کہتے ہیں اور یہ مجموعاًچھ ہیں :
نصف ،ایک چوتھائی ،آٹھواں حصہ ،دوتہائی ،ایک تہائی اورچھٹاحصہ۔(۱)
٢۔جولوگ رشتہ داری کی وجہ سے میراث پا تے ہیں ،لیکن ان کاحصہ نسبت کے مطابق معین نہیں ہے ۔
میراث کے فرض
١۔نصف (١٢ )یہ تین وراثوں کے لئے ہے ۔
الف:شوہر،جبکہ اسکی بیوی مرگئی ہواوراس کے کوئی اولاد نہ ہو ۔
ب:بیٹی ،اگر مرنے والے کی تنہا اولاد ہو ۔
ج:بہن ،مادری وپدری یاصرف پدری ہو،جب کہ میت کا کوئی اور وارث نہ ہو۔
٢۔ایک چوتھائی(١٤)یہ دو وارثوں کے لئے ہے :
الف:شوہر،جب کہ اس کی بیوی مرگئی ہواوراس کے اولادہو۔
ب:بیوی،جب کہ اس کاشوہرمرگیاہواوراس کے اولادنہ ہو۔
٣۔آٹھواں حصہ(١٨)یہ بیوی یا متعدد بیو یوں کی میراث ہے ،جبکہ مرنے والے کے اولاد ہو۔
٤۔دوتہائی (٢٣)یہ دووارثوں کے لئے ہے:
الف:دوبیٹیاں یااس سے زیادہ ،جبکہ مرنے والے کے کوئی بیٹانہ ہو۔
ب:دو یا اس سے زیادہ پدری ومادری بہنیں یاصرف پدری بہن ہو،جبکہ مرنے والے کے کوئی بھائی نہ ہو۔
٥۔ایک تہائی (١٣)یہ بھی دو وارثوں کے لئے ہے ۔
الف:ماں ،جبکہ مرنے والی اولاد کے اولاداورمتعدد بھائی نہ ہوں۔
ب:مادری بہن اوربھائی جبکہ ایک سے زیادہ ہوں ۔
٦۔چھٹاحصہ(١٦)اوریہ تین وارثوں کے لئے ہے:
الف:باپ،اگرمیت کی اولاد زندہ ہو۔
ب:ماں،اگرمرنے والے کی اولادزندہ ہو۔
ج:مادری بہن یابھائی جبکہ منحصر بہ فردہو۔
ماں باپ کی میراث
١۔اگرمرنے والے کاوارث صرف اس کاباپ یاماں ہوتو میت کا تمام ترکہ اس کی ماں یاباپ کی میراث ہے ۔
٢۔اگرمرنے والے کے وارث اس کے ماں باپ اوراس کی اولادہوں تو اس کے ماں باپ میں سے ہرایک ،چھٹاحصہ(١٦)لیںگے اورباقی اس کی اولادکا ہوگا۔
٣۔اگرمرنے والے کے وارث باپ اورماں ہوں ،اوراسکی کوئی اولادنہ ہوتواگرمرنے والے کے چندبھائی ہوں تو،اگر چہ اس کے بھائی میراث نہیں پاتے،لیکن اس صورت میں چھٹاحصہ (١٦)ماں کااورباقی مرنے والے کے باپ کاہوگا۔اوراگرمرنے والے کے کوئی بھائی نہ ہو تواس صورت میں ماں کاحصہ ایک تہائی (١٣)اور باپ کاحصہ دوتہائی(٢٣)ہوگا ۔
اولاد
١۔اگرمرنے والے کاوارث ایک بیٹایاایک بیٹی ہوتوتمام ترکہ اسی کا ہے اوراگرکئی بیٹے یا کئی بیٹیاںہوں تومال مساوی طورپران کے درمیان تقسیم ہوگااوراگر مرنے والے کے بیٹے اوربیٹیاںہوں توہربیٹے کوبیٹی کے دوبرابرحصہ ملے گا۔
دادا،دادی اورنانا،نانی
٢۔اگرمیت کے وارث دادااوردادی ہوں،تودوحصے دادااورایک حصہ دادی کو ملی گا۔اوراگرمیت کے وارث نانااورنانی ہوں تو ان کے درمیان میت کامال مساوی طورپرتقسیم ہوگا۔اوراگر میت کے وارث دادا،دادی اورنانا،نانی ہوںتو مال کوتین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ان میں سے دوحصے دادا ،دادی کواسطرح کہ دادا کودادی کے دوبرابردیا جائے گا۔اورایک حصہ نانااورنانی کو مساوی طورپرتقسیم کرکے دیاجائے گا۔
٣۔اگرمرنے والے کے وارث اجداداوربھائی بہن ہوں ،چنانچہ وہ بھائی یابہن مادری یاپدری یاپدری ومادری ہوں توایک تہائی اجداد کواورباقی دوتہائی بھائی بہنوںکو ملے گا۔
لیکن اگربھائی بہن میں بعض پدری ومادری اوربعض دوسرے صرف پدری ہوں تومادری بھائی یابہن کوکچھ نہیں ملیگااور باقی ماندہ دوحصے پدری ومادری یاپدری بھائی اوربہن کوملے گا ۔
چچا اور پھوپھی
١۔اگرمرنے والے کے وارث چچا یا پھوپھی ہوں توسب مال ان کو ملے گا اوراگرکئی چچایا کئی پھوپھیاںہوں تو ان میں مساوی طورپر مال تقسیم ہوگااوراگرچچااورپھوپھی ہوں اورسب پدری ومادری یاپدری یامادری ہوں تو چچا کودوحصے اورپھوپھی کوایک حصہ ملے گا اوراگربعض پدری ومادری ہوں اوربعض پدری اوربعض مادری ہوں،تواس صوت میں اگرچچااورپھوپھی مادری ہوں تو ایک تہائی (١٣)مال اوراگرزیادہ ہوں تو دوحصے اس کو ملیں گے اور باقی پدری ومادری چچااور پھوپھی کو ملے گا اورپدری چچاوپھو پھی کومیراث نہیں ملے گی ۔
٢۔اگرمرنے والے کے وارث ،پدرومادری چچایا پھوپھی اورپدری چچایاپھوپھی ہوںتوپدری چچایا پھوپھی کو میراث نہیں ملے گی اورتمام مال پدری ومادری چچاوپھوپھی کو ملے گا۔
ماموں اورخالہ
ماموں اورخالہ جبکہ سب پدری ومادری ہوں ،اگرچہ بعض لڑ کے اوربعض لڑکیاں ہوں،تو مال ان میں مساوی طور پر تقسیم ہوگااوراگربعض پدری ومادری یاپدری اوربعض مادری ہوں،تومادری ماموں اورخالہ کاحصہ ١٦ہے جو ان میں مساوی طور پرتقسیم ہوگا اورباقی مال پدری ومادری یاپدری ماموں اورخالہ کو ملے گا کہ ہرلڑ کے کو لڑکی کے دوبرابرحصہ ملے گا ۔
میاں بیوی کی میراث
جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ شوہر کی میراث جبکہ اس کی بیوی کے کوئی اولادنہ ہوتونصف ہے اوراگراس(فوت شدہ)بیوی یادوسری بیوی سے اولاد ہوتوایک چوتھائی ہے۔ اوربیوی کی میراث،اگر(فوت شدہ)شوہر سے کوئی اولادنہ ہو تو ایک چوتھائی اوراگراس(فوت شدہ)شوہریادوسرے شوہرسے اولادہوتو اس کو١٨میراث ملے گی۔
لیکن جانناچاہئے کہ بیوی زمین سے میراث نہیں پاتی ،بلکہ ١٤یا١٨منقولہ اموال اوراعیان زمین ،جیسے عمارت،تعمیر اوردرختوں سے میراث پاتی ہے ،لیکن شوہربیوی کے تمام اموال سے میراث پاتاہے ۔
____________________
١۔ ترتیب وار ١٢، ١٤،١٨،٢٣،١٣اور١٦ ۔
ولاء
اگرکسی مرنے والے کامذکورہ وارثوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتواس کی میراث''ولائ''کے ذریعہ انجام پائے گی ۔اور ولاء کی تین قسمیں ہیں کہ جو بالترتیب میراث حاصل کرتے ہیں :
١۔ولائے عتق
وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے غلام کوآزاد کرے ،چنانچہ وہ غلام مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کامالک اورمولااسکے تمام ترکہ کاوارث بن جاتا ہے ۔
٢۔ولا ئے ضمان جریرہ
اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ عہد کرے کہ''کسی کو قتل کرنے یا زخمی کرنے کی صورت میں جو جرمانہ اس پر کیا جائے گا،وہ اسے اس شرط پر اداکرے گا کہ اگراس کے مرنے کے بعداس کا کوئی وارث نہ ہوتواس کے ترکہ کولے لے گا ''اس صورت میں وہ اس کے تمام ترکہ کاوارث بنتا ہے ۔
٣۔ولائے امامت
یہ امام کی سرپرستی ہے ۔امام،تمام مسلمانوں کا سر پرست ہے اوراگرکسی شخص کا کوئی وارث نہ ہو،تواس کاترکہ امام کواورامام کی غیبت میں ان کے نائب کو پہنچتا ہے۔ امیرالمومنین حضرت علی علیہ السلام ،لا وارثوں کے ترکہ کوان کے ہم شہریوں اورہمسایوں میں تقسیم فرماتے تھے۔
میراث کے احکام
١۔باپ کے رشتہ داراورماںباپ کے رشتہ دارمیراث کو کچھ فرق کے ساتھ تقسیم کرتیں ہیں ،یعنی ہرمردعورت کے دوبرابرلیتا ہے ،لیکن ماں کے رشتہ داروں میں میراث مساوی طورپر تقسیم ہوتی ہے ۔
٢۔وارثوں کے ہرطبقہ میں اولاد ،باپ اورماں کی جگہ ہوتی ہے ،یعنی اگرماں باپ نہ ہوں توان کی میراث کاحصہ ان کی اولاد لیتی ہے ،مثلاًاگرمرنے والے کے ماں باپ اوراس کی پوتی اورنواسہ ہو، توماں باپ میں سے ہرایک کو مال کا١٦حصہ ملے گا اور باقی مال تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اوران میں سے دوحصے پوتے کواورایک حصہ نواسے کو ملے گا ۔
٣۔اگرمرنے والے کے ایک بیٹااورایک پوتاہوتو تمام میراث بیٹے کوملے گی اورپوتے کو کچھ نہیں ملے گا۔
٤۔اگروارثوں کے حصے اور فرض اصل ترکہ سے زیادہ ہوتو،کمی کو بیٹیاں اور باپ کے رشتہ داربرداشت کریں گے ۔مثلاًاگرمرنے والے کے وارث شوہر،باپ ،ماں اورکئی بیٹیاں ہوں توچونکہ شوہر کاحصہ ١٤ اورماںباپ میں سے ہرایک کاحصہ ١٦اور بیٹیوں کاحصہ٢٣ہے اور یہ مجموعاً١١٤ ہوتا ہے اسطرح ١٤تمام ترکہ سے یعنی عددواحدزیادہ ہوتا ہے ۔اس صورت میں شوہر ،باپ اور ماں کا پوراحصہ ادا کرنے کے بعدباقی بچے مال کو بیٹیوں میں مساوی طورپرتقسیم کیا جاناچاہئے ۔اور کمی ان سے متعلق ہوتی ہے ۔
اہل سنت اس صورت میں کمی کو ہرایک حصہ دارکے حصہ سے کم کرتے ہیں اوراسے ''عول''کہتے ہیں ۔
٥۔اگرتمام حصے اصل مال سے کم ہوں ،یعنی عددواحد کم ہو اس طرح کہ فرض اورحصوں کو ادا کرنے کے بعد کچھ مال بچے تو باقی ماندہ مال کو بیٹی یاباپ کے رشتہ داروں ،یعنی کمی کا خسارہ برداشت کرنے والے رشتہ داروں کے حصہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلاًاگرمرنے والے کی وارث ماں اورایک بیٹی ہوتوماں کاحصہ ١٣ہے اوربیٹی کاحصہ ١٢اور اس صورت میں ١٦حصہ مال باقی بچتا ہے اسے بیٹی کودیاجاتا ہے ۔لیکن اہل سنت اس بچے ہوئے مال کوباپ کے رشتہ داروں ۔جوبعدوالاطبقہ ہے۔ کو دیتے ہیں اور اسے '' تعصیب'' کہتے ہیں۔
مر د وعورت کے حصوں میں جزئی فرق
اسلام کی نظر میں مردوعورت انسانی طبیعت اورحقوق ومعنویت کے لحاظ سے مساوی ہیں۔لیکن ان دونوں صنفوں میں سے ہرایک میں اپنی مخصوص خصوصیات کی بنا پر کچھ فرق بھی ہے ۔جیسے میراث میں عورت کاحصہ مرد کے حصہ کا نصف ہے اور دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے اور مرد ایک وقت میں چاربیویاں رکھ سکتا ہے لیکن عورت کو ایک شوہرسے زیادہ کاحق نہیںہے اورطلاق کا حق مرد کو ہے اورحکومت،فیصلہ اور جہادمردوں سے مخصوص ہے اور عورت کے اخراجات مرد کے ذمہ ہیں ۔
البتہ یہ جزئی فرق جواسلام میں مرداورعورت کے درمیان پایا جاتا ہے ، اس کا سبب ان کی مخصوص فطرت اورجذ بات ہیں۔کیونکہ دونوں صنفوں میں انسانیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔
مرد اورعورت میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں جذبات اورہمدردیاں مرد کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں ۔
یہ بات ناقابل انکار ہے کہ تمام ناموس کی طرح اس حکم کے بھی استثنائی مواقع بھی ہیں، یعنی دنیا میں ایسی عورتیں بھی پیدا ہوئی ہیں کہ ان کی عقلی توانائی بہت سے مردوں سے کہیںزیادہ تھی ،لیکن عام طور پر مردوں کی اکثریت میں عقل وفکر کی توانائی زیادہ رہی ہے اورجذبات واحساسات عورتوں میں زیادہ رہے ہیں ۔
یہ بات طولانی تجربوںاورآزمائشوں کے بعدثابت ہوئی ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق میں جو فرق پایا جاتا ہے ،اس کی علت یہی فکراورجذبات اوردیگرطبیعی اسباب ہیں ۔ہم یہاں پراجمالی طور پران میں سے بعض فرق کو بیان کرتے ہیں ۔
مرد اور عورت کی میراث میں فرق
اسلامی نقطۂ نظر سے ،میراث میں عورت کاحصہ ،مرد کے حصہ کا نصف ہے۔لیکن دقیق تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کادوسرا حکم، یعنی عورت کے اخراجات کومرد برداشت کرے،اس کمی کی تلافی کرتا ہے ۔کیونکہ ہم جانتے ہیںکہ روئے زمین پرموجود تمام مال و دولت ہرزمانہ میں نسل حاضر کی ملکیت ہوتی ہے اور میراث کے ذریعہ دوسری نسل پہنچتی ہے اور وہ اس سے استفادہ کرتی ہے۔
اس لئے،مرد اورعورت کے ایک حصہ اور دوحصہ لینے(جواعداد وشمار سے تقریباًمساوی ہے)کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی پوری دولت کا دوتہائی حصہ مرد کا ہے اورایک تہائی حصہ عورت کا ہے۔
لیکن چونکہ اسلام میں عورت کے اخرا جات اور اس کی زندگی کے لوازم عدالت ومساوات کی بنا پر مرد کے ذمہ ہے ،لہذا مال کانصف حصہ مرد کو جوزیادہ دیاگیا ہے وہ عورت پر خرچ ہوتا ہے اور وہ عورت اپنے حصہ کو بھی اپنے اختیار سے خرچ کرسکتی ہے ۔
پس روئے زمین کی دولت کا دوتہائی حصہ اگر چہ ہر زمانہ میں مرد کا اور ایک تہائی حصہ عورت کا رہا ہے ،لیکن اخراجات کے لحاظ سے مسئلہ برعکس ہے ۔
پس حقیقت میں اسلام نے ملکیت کے لحاظ سے دنیا کے مال کا دوتہائی حصہ تدبیر، فکر وعقل نظام چلانے والے کے ہاتھ میں دیا ہے اور اس کاایک تہائی حصہ جذبات اوراحساسات کے سپردکیاہے ۔لیکن اخراجات کے لحاظ سے اس کا دوتہائی حصہ جذبات واحساسات کے سپرد کیا گیا ہے اور ایک تہائی حصہ فکر و عقل کے سپرد کیا گیاہے ۔
بدیہی ہے کہ مال و دولت کے سلسلہ میں عقل کی توانائی جذبات اور احساسات سے زیادہ ہے اورجذبات اوراحساسات مال کو خرچ کرنے میں عقل کی زیادہ محتاج ہیں کیوںکہ یہ ایک نہایت عادلانہ و عاقلانہ طریقہ ہے کہ دنیا کی دولت کودو مختلف طاقتوں یعنی عقل وجذبات میں تقسیم کردیا جائے تا کہ یہ دونوں طاقتیںراضی رہیں جو زندگی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں ۔
بیع
( خرید و فروخت)
بیع کیا ہے ؟
''بیع''کے معنی کسی مال کوبیچنے یاکسی مال کو دوسرے مال سے بدلنے کے ہیں،اس صورت میں کہ مال کا مالک جسے''بیچنے والا''کہتے ہیں ،اپنے مال کی ملکیت سے ان پیسوں کے عوض دست بردار ہوجاتا ہے جو کہ ،دوسرا شخص ،یعنی ''خریدار''ادا کرتا ہے۔اور''خریدار''بھی مال کے عوض بیچنے والے کو اپنے پیسے دیدیتا ہے ۔
واضح رہے کہ''بیع''ایک عقد ہے اور اپنے وجود میں طرفین (بیچنے والے اورخریدنے والے)کا محتاج ہے ۔اس لئے اس میں عقود کے عام شرائط جیسے بلوغ،عقل، قصد اوراختیار ہونا چاہئے ۔
بیع عقد لازم ہے
بیع،عقود لازمہ میں سے ہے ،یعنی عقد کے منعقد ہونے کے بعد متعاقدین ( بیچنے والے یاخریدار) میں سے کوئی اسے توڑ نہیں سکتا ۔لیکن چو نکہ کبھی بیع کے منعقد ہو جانے کے بعد غفلت یا غلطی سے بیچنے والے یا خریدار کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ قابل اعتنا نقصان سے دوچار ہوتا ہے، لہذاایسے مواقع پر بیع کا انجام عام مصلحتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اس خرابی سے بچنے کے لئے دواقدام کئے ہیں :
اول:''اقالہ''وہ یہ ہے کہ بیع انجام دینے والے طرفین میں سے ایک پشیمان ہوجائے اورمد مقابل سے معاملہ توڑنے کی درخواست کرے تومستحب ہے اسے قبول کرکے معاملہ کو توڑدیا جائے ۔
دوم :''خیار'' یہ ایک خاص اختیار ہے جس کے تحت معاملہ کرنے والا معاملہ کو توڑ سکتا ہے ۔
مشہور''خیارات'' حسب ذیل ہیں :
١۔خیار مجلس: جب تک عقد کی مجلس برخاست نہ ہوجائے معاملہ کے طرفین معا ملہ کو توڑ سکتے ہیں ۔
٢۔خیارغبن : یہ ہے کہ عقد کے طرفین میں سے کسی ایک نے دھوکہ کھایا ہو اورمعاملہ میں نقصان اٹھایا ہو۔مثلاًمال اس کی اصل قیمت سے کم میں بیچ دیاگیاہو یااصل قیمت سے زیادہ میں خریدا گیا ہو ۔تواس صورت میں طرفین میں سے جس کو نقصان ہوا ہے وہ فوراً معا ملہ کو توڑ سکتا ہے ۔
٣۔خیار عیب: اگر معا ملہ طے پانے کے بعد،خریدار مال میں کوئی عیب پائے تو وہ معاملہ کوتوڑ سکتا ہے ۔یا قیمت کے تفاوت کو حاصل کرسکتا ہے ۔
٤۔خیار حیوان :حیوانوں ،جیسے بھیڑ اورگھوڑے وغیرہ میں خریدار تین دن تک معاملہ توڑنے کا حق رکھتا ہے ۔
٥۔خیارشرط: اگر بیچنے والا یاخریدار یادونوں اپنے معاملہ میں کوئی شرط رکھیں ،تو وہ شرط کی خلاف ورزی کی صورت میں معاملہ کو توڑ سکتے ہیں ۔
نقد،ادھار،اور سلم
پیسہ لینے اور مال دینے کے لحاظ سے''بیع''کی چار قسمیں ہیں :
١۔معاملہ انجام پانے کے ساتھ ہی خودمال اورپیسے اداکئے جائیں تواس بیع کو''نقد''کہتے ہیں۔
٢۔معاملہ انجام پانے کے وقت مال خریدار کے حوالہ کردیاجائے لیکن اس کی قیمت تاخیرسے اداہونا قرار پائے ،تو اس معاملہ کو''ادھار'' کہتے ہیں ۔
٣۔دوسری قسم کے برعکس پیسے نقداداکئے جائیں لیکن مال کوبعد میں دیناقرارپائے تواس بیع کو''سلم ''کہتے ہیں ۔
٤۔پہلی قسم کے برعکس معاملہ طے ہونے کے بعدمال اور پیسے دونوں بعد میں ادا کرناقرارپائے تواس بیع کو''کالی بہ کالی ''کہتے ہیں ۔
مذکورہ چار قسموں میں سے بیع کی پہلی تین قسمیں صحیح اورچوتھی قسم باطل ہے۔
منابع ومآخذ کی فہرست
١۔قرآن مجید
الف:
٢۔احقاق الحق،قاضی سید نوراللہ الحسینی المرعشی التستری ،طبع، الخیام ،قم ۔
٣۔اصول کافی ،مرحوم کلینی ،دارالکتب الاسلا میہ ،تہران ۔
٤۔امالی ،شیخ مفید،دفترانتشارات اسلامی ،قم ۔
ب:
٥۔بحارالانور،علامہ مجلسی ،دار احیاء التراث العربی،بیروت،لبنان۔
ت:
٦۔تاریخ طبری ،محمدبن جریر طبری،دارالمعارف،مصر۔
٧۔تحف العقول ،ابو محمدحسن بن علی بن حسین شعبئہ حرافی،دفتر انتشارات اسلامی قم ۔
س:
٨۔سفینتہ البحار،شیخ عباس قمی ،انتشارات فراہان ،تہران۔
ش:
٩۔شرح غررالحکم ،جمال الدین محمدخوانساری،مئوسسئہ انتشارات وچاپ،تہران۔
ع:
١٠۔عوالی اللئالی،محمدبن علی بن ابراھیم احسائی،مطبعئہ سیدالشہداء علیہ السلام دانشگاہ قم،ایران۔
غ :
١١۔غایةالمرام،صمیری بحرانی،دارالھادی،قم۔
١٢۔الغدیر،علامہ امینی،دارالکتب العربی،بیروت،لبنان۔
١٣۔غررالحکم،متر جم محمدعلی انصاری،مئوسسئہ صحافی خلیج،ایران ،قم۔
ک:
١٤۔کنزالعمال،علامہ علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین الھندی، مؤسسة الرسالة،بیروت۔
م:
١٥۔محجة البیضا،ملا محسن کاشان،دفترانتشارات اسلامی ،قم ۔
١٦۔مستدرک الوسائل ،حسین نوری طبرسی ،افست مطبعة الاسلا میہ۔
١٧۔مسنداحمدبن حنبل،مکتب اسلامی دار صادر،بیروت۔
١٨۔میزان الحکمة،محمدری شہری،مکتب العلوم الاسلا می ،قم۔
ن:
١٩۔نہج البلاغہ صبحی صالح۔
٢٠۔نہج البلاغہ فیض الاسلام۔
٢١۔نہج الفصاحہ ،مترجم ،ابوالقاسم پایندہ،سازمان انتشارات جاویدان۔
و:
٢٢۔وسا ئل الشیعہ،شیخ حرعاملی ،مکتبة الاسلامیة ،تہران۔
ی:
٢٣۔ینابیع المودہ،قندوزی، موسسئہ اعلمی۔
فہرست
حرف اول ۵
دینی معلومات ۷
نتیجہ ۸
خداکے قانون سے رابط کا اچھا اثر ۸
١۔عقائد ۹
٢۔اخلاق ۱۰
٣۔عمل ۱۰
دین کافطری ہون ۱۲
دین کے فائدے ۱۳
تاریخ ادیان کا ایک خلاصہ ۱۴
دین اسلام اور اس کی آسمانی کتاب ۱۵
دین ،قرآن مجید کی نظر میں ۱۷
معاشرے میں دین کا کردار ۱۹
معاشرے کو قوانین کی ضرورت ۱۹
قوانین کے مقابلہ میں انسان کاآزاد ہونا ۲۰
قوانین کی ترقی میں کمزوریاں ۲۰
قانون میں خامی کااصلی سر چشمہ ۲۱
تمام قوانین پردین کی ترجیح ۲۲
نتیجہ ۲۲
دوسروں کی کوشش ۲۳
انسان کے آرام وآسائش میں اسلام کی اہمیت ۲۴
اسلام کا دوسرے ادیان سے موازنہ ۲۴
سماج کے رسم ورواج سے اسلام کا موازنہ ۲۵
نتیجہ ۲۶
طبیعی وسائل سے اسلام کی ترقی ۲۷
تبلیغ اور دعوت اسلام ۲۷
تبلیغ کا طریقہ ۲۸
اسلام میں تعلیم و تربیت ۲۹
اسلامی تعلیمات کے دواہم شاہکار ۲۹
آزادی فکر اور حق پوشی ۳۰
نتیجہ ۳۱
سماجی زندگی میں اسلام کی خدمات ۳۲
افراد کے منافع کاتحفظ اوررفع اختلاف ۳۲
اسلام کا طریقہ کار اور اس کی بنیاد ۳۲
سماجی اختلافات ۳۳
عداوت و اختلاف سے اسلام کا مقا بلہ ۳۵
رفع اختلاف کے لئے ایک عام وسیلہ ۳۶
نماز،روزہ اورحج یارفع اختلافات کا وسیلہ ۳۷
عقائد ۴۰
١۔توحید ۴۰
اثبات صانع ۴۰
ابتدائے خلقت کی بحث ۴۱
معرفت خدا اور ملتیں ۴۲
انسان کی زندگی میں تجسس کا اثر ۴۳
توحید کے بارے میں قرآن مجید کا اسلوب ۴۴
مثال اورو ضاحت ۴۵
قرآن مجید کی نظر میں خداشناسی کا طریقہ ۴۷
کمال کیا ہے؟ ۴۸
توحید اور یکتائی ۴۹
وضاحت ۵۰
خدائے متعال کا وجود،قدرت اور علم ۵۰
خدا کی قدرت ۵۱
وضاحت ۵۱
خدا کا علم ۵۱
وضاحت ۵۱
خداکی رحمت ۵۲
تمام صفات کمالیہ ۵۲
وضاحت ۵۲
٢۔نبوت ۵۳
انسان کوپیغمبر کی ضرورت ۵۳
انبیاء کی تبلیغ ۵۴
معاشرے میں قوانین و قواعد کی ضرورت ۵۵
قواعدوضوابط کی تکوینی بنیاد ۵۵
زندگی کے قوانین کی طرف تکو ینی ہدایت ۵۵
نتیجہ ۵۶
انسان اور دوسری مخلو قات کی ہدایت میں فرق ۵۷
انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق ۵۸
پیغمبر کی صفات ۶۰
انبیاء ،انسانوں کے درمیان ۶۰
صاحب شریعت انبیائ ۶۱
اولوالعزم پیغمبر اور دوسرے انبیائ ۶۱
١۔حضرت نوح علیہ السلام ۶۲
٢۔حضرت ابراہیم علیہ السلام ۶۳
٣۔حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلام ۶۴
٤۔حضرت عیسی مسیح علیہ السلام ۶۵
٥۔خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۶۷
بحیرا راہب کا قصہ ۶۸
نسطورا راہب کا قصہ ۷۰
حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ۷۱
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کی طرف سفر ۷۴
مدینہ کے یہودیوں کی بشارت ۷۵
نبی کی بشارتوں کی طرف قرآن مجید کااشارہ ۷۵
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں ورود ۷۶
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی جنگوںکاایک مختصرجائزہ ۷۸
١۔جنگ بدر ۷۸
٢۔جنگ احد ۷۸
٣۔جنگ خندق ۷۹
٤۔جنگ خیبر ۸۰
بادشاہوں اور سلاطین کو دعوت اسلام ۸۰
٥۔جنگ حنین ۸۱
٦۔جنگ تبوک ۸۱
اسلام کی دوسری جنگیں ۸۲
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنوی شخصیت کاا یک جائزہ ۸۳
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی معنوی شخصیت ۸۵
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ۸۵
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چند نکات ۸۸
مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ۹۰
پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور جانشینی کا مسئلہ ۹۰
قرآن مجید، نبوت کی سند ۹۲
قرآن مجید کی اہمیت ۹۴
قرآن مجید کا معجز ہ ۹۴
قرآن مجید کی مشرکین کو مناظرہ کی دعوت ۹۷
قرآن مجید کی تعلیمات ۱۰۰
قرآن مجید کی نظر میں علم وجہل ۱۰۰
وضاحت ۱۰۲
قرآن مجید کا احترام ۱۰۳
راہ خدا میں جہاد او رفداکاری کے متعلق قرآن کا دستور ۱۰۳
بحث کا خاتمہ ۱۰۴
٣۔ معاد یا قیامت ۱۰۵
٣۔ معاد یا قیامت ۱۰۵
ادیان و ملل کی نظر میں معاد ۱۰۵
قرآن مجیدکی نظر میں معاد ۱۰۶
موت سے قیامت تک ۱۰۷
بدن مرتا ہے نہ کہ روح ۱۰۷
اسلام کی نظر میں موت کے معنی ۱۰۸
برزخ ۱۰۸
قیامت یقینی ہے ۱۰۸
٤۔عدل ۱۱۱
٥۔امامت اور امت کی رہبری ۱۱۳
امام کی ضرورت پر ایک نقلی دلیل ۱۱۴
ولایت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ۱۱۵
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ جانشین کا تقرر ۱۱۶
امامت کی ضرورت پر ایک دلیل ۱۱۶
امام کی ضرورت ۱۱۷
امام کی عصمت ۱۱۸
امام کے اخلاقی فضائل ۱۱۸
امام کا علم ۱۱۸
ائمہ ھدیٰ علیہم السلام ۱۱۹
ائمہ علیہم السلام کے اسمائے گرامی ۱۱۹
ائمۂ اطہار علیہم السلام کی عام سیر ت ۱۱۹
پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام ۱۲۰
اہل بیت علیہم السلام کی عام سیرت ۱۲۱
وقت کے حکّام کے ساتھ ائمہ اطہار کے اختلافات کا اصلی سبب ۱۲۳
خلاصہ اور نتیجہ ۱۲۵
اہل بیت علیہم السلام کے کردار میں ایک استشنائی نکتہ ۱۲۵
اہل بیت علیہم السلام کے فضائل ۱۲۶
ائمہ علیہم السلام کی تقرری ۱۲۸
ائمہ معصو مین علیہم السلام کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ ۱۲۹
حضرت امام علی علیہ السلام ۱۲۹
(مسلمانوں کے پہلے امام ) ۱۲۹
امام علی علیہ السلام کے فضائل کا خلاصہ ۱۳۲
حضرت امیرالمؤ منین کا طریقہ ۱۳۳
حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ۱۳۵
(دوسرے امام) ۱۳۵
حضرت امام حسین علیہ السلام ۱۳۶
(تیسرے امام) ۱۳۶
کیاامام حسن اورامام حسین علیہما السلام کی روش مختلف تھی ؟ ۱۳۷
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ۱۴۰
(چوتھے امام) ۱۴۰
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ۱۴۱
(پانچویں امام) ۱۴۱
حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ۱۴۱
(چھٹے امام) ۱۴۱
امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہماالسلام کی تحریک ۱۴۲
حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ۱۴۳
(ساتویں امام) ۱۴۳
حضرت امام رضا علیہ السلام ۱۴۳
(آٹھویں امام) ۱۴۳
حضرت امام محمدتقی علیہ السلام ۱۴۵
(نویں امام) ۱۴۵
حضرت امام علی نقی علیہ السلام ۱۴۵
(دسویںامام) ۱۴۵
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ۱۴۵
(گیارہویں امام) ۱۴۵
حضرت امام مہدی موعودعجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ۱۴۶
(بارہویںامام) ۱۴۶
ائمہ دین کی روش کااخلاقی نتیجہ ۱۴۷
ائمہ معصومین علیہم السلام کے اجمالی حالات ۱۴۸
پہلے امام ۱۴۸
دوسرے امام ۱۴۸
تیسرے امام ۱۴۹
چوتھے امام ۱۴۹
پانچویں امام ۱۴۹
چھٹے امام ۱۵۰
ساتویں امام ۱۵۰
آٹھویںامام ۱۵۱
نویں امام ۱۵۱
دسویں امام ۱۵۲
گیارہویں امام ۱۵۲
بارہویں امام ۱۵۲
اخلاق واحکام کے چند سبق ۱۵۴
١۔اخلاق کے چند سبق ۱۵۴
خدا کے بارے میں انسان کافریضہ ۱۵۴
خدا پرستی ۱۵۵
اپنے بارے میں انسان کافریضہ ۱۵۶
بدن کی صفائی ۱۵۷
صفائی کاخیال ۱۵۷
کُلّی اور مسواک ۱۵۸
استنشا ق(ناک میں پانی ڈالنا) ۱۵۸
تہذیب اخلاق ۱۵۹
حصول علم ۱۵۹
اسلام کی نظرمیں طالب علم کی اہمیت ۱۶۰
معلم اورمربی کی اہمیت ۱۶۱
معلم اور شاگرد کا فریضہ ۱۶۱
ماں باپ کے بارے میں انسان کا فریضہ ۱۶۲
بزر گوں کا احترام ۱۶۳
اپنے رشتہ داروںکے بارے میں انسان کافریضہ ۱۶۳
ہمسایوں کے بارے میں انسان کافریضہ ۱۶۳
ماتحتوں اور بیچاروں کے بارے میں انسان کا فریضہ ۱۶۴
معاشرے کے بارے میں انسان کا فریضہ ۱۶۵
عدالت ۱۶۸
انفرادی عدالت ۱۶۸
اجتماعی عدالت ۱۶۸
سچائی ۱۶۹
جھو ٹ ۱۶۹
جھوٹ کے نقصانات ۱۷۰
غیبت وتہمت ۱۷۰
لوگوں کی عزت پر تجاوز ۱۷۱
رشوت ۱۷۱
حسن معاشرت ۱۷۲
نیکوں کی مصاحبت ۱۷۴
بروں کی مصاحبت ۱۷۵
ماں باپ پر اولاد کے حقوق ۱۷۵
اولاد پر ماں باپ کے حقوق ۱۷۷
بھائیوںاور بہنوں کے باہمی حقوق ۱۷۷
عاق والدین ۱۷۸
عزت نفس اور کامیابی ۱۷۸
احسان اور محتاجوں کی مدد ۱۷۹
تعاون ۱۸۰
خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت کرن ۱۸۰
یتیم کامال کھان ۱۸۱
کسی کوقتل کرن ۱۸۱
رحمتِ خدا سے مایوسی ۱۸۱
جہاد اور دفاع سے فرارکی سزا ۱۸۲
وطن کادفاع ۱۸۳
حق کا دفاع ۱۸۳
غیظ وغضب ۱۸۳
کام کا واجب ہونا اور صنعت و حرفت کی اہمیت ۱۸۴
بیکاری کے نقصانات ۱۸۵
خود اعتمادی ۱۸۵
کھیتی باڑی اور اس کے فائدے ۱۸۶
دوسروںکے سہارے زندگی گزارنے کے نقصانات ۱۸۶
ناپ تول میں کمی کی سزا ۱۸۶
ظلم و ستم کی برائی ۱۸۷
مردم آزاری اور شرارت حرام ہے ۱۸۷
چوری ۱۸۸
فرض شناسی ۱۸۹
فرض شناسی ۱۸۹
فریضہ کی تعیین میں مختلف روشوں کا اختلاف ۱۹۰
دفاع کی اہمیت ۱۹۱
بخش دین ۱۹۲
مال کی ز کواة ۱۹۳
علم کی زکواة ۱۹۴
معاشرے کے اندرونی دشمنوں سے مقابلہ ۱۹۵
اسلام میں گناہان کبیرہ کی عام سزا ۱۹۶
احکام کے بارے میں چندسبق ۱۹۷
اجتہاد اورتقلید ۱۹۷
نجاسات ۱۹۸
نجاسات(نجس چیزیں )چند چیزیں ہیں : ۱۹۸
١و٢:پیشاپ اورپاخانہ۔(۱) ۱۹۸
مطہّرات ۱۹۸
(پاک کرنے والی چیزیں ) ۱۹۸
١۔پانی، ۱۹۹
٢۔زمین ، ۱۹۹
٣۔آفتاب ، ۱۹۹
٤۔استحالہ ، ۱۹۹
٥۔انتقال ، ۱۹۹
٦۔عین نجاست کازائل ہوجانا، ۱۹۹
٧۔تبعیّت، ۲۰۰
٨۔کم ہونا، ۲۰۰
غسل ۲۰۰
وضو اور اس کے احکام ۲۰۲
وضو کی کیفیت اوراس کے شرائط ۲۰۲
مبطلات وضو ۲۰۲
تیمم ۲۰۳
تیمم کا طریقہ ۲۰۳
تیمم کے احکام ۲۰۴
نماز ۲۰۵
واجب نمازیں ۲۰۶
مقدمات نماز ۲۰۶
١۔ طہارت ۲۰۷
٢۔ وقت ۲۰۷
٣۔ لباس ۲۰۸
٤۔مکان ۲۰۸
٥۔ قبلہ ۲۰۸
واجبات نماز ۲۰۹
ارکان نماز ۲۰۹
١۔نیت ۲۱۰
٢۔تکبیر ة الاحرام ۲۱۰
٣۔قیام ۲۱۰
٤۔رکو ع ۲۱۰
٥۔سجدہ ۲۱۱
تشہد وسلام ۲۱۱
نماز آیات ۲۱۳
نماز آیات پڑھنے کا طریقہ ۲۱۳
نماز آیات کا دوسرا طریقہ : ۲۱۳
مسافر کی نماز ۲۱۳
نماز جماعت ۲۱۴
نماز جماعت کی شرائط ۲۱۴
نماز جماعت کے احکام ۲۱۴
روزہ ۲۱۶
روزہ کو باطل کرنے والی چیزیں ۲۱۶
اسلام میں جہاد ۲۱۶
جہاد کے کلی مسائل ۲۱۶
اسلام میں جنگ کے مواقع ۲۱۷
١۔مشرکین : ۲۱۸
٢۔اہل کتاب: ۲۱۸
٣۔بغاوت اورفساد برپا کرنے والے : ۲۱۸
٤۔دین کے دشمن: ۲۱۸
جہاد کے بارے میں اسلام کا عام طریقہ ۲۱۹
حکومت،قضاوت اورجہاد کیوں مردوں سے مخصوص ہے ؟ ۲۱۹
اسلام میں فیصلہ ۲۲۲
مسائل عدلیہ کے کلیات ۲۲۲
قاضی (جج) کے فرائض ۲۲۲
فیصلہ کرنے کی اہمیت ۲۲۳
گواہی ۲۲۴
مرداورعورت کی گواہی ۲۲۴
گواہی کے کلیات ۲۲۴
گواہ کی شرائط ۲۲۴
اقرار ۲۲۶
اقرار کی اہمیت ۲۲۶
اقرار کے معنی اور اس کی شرائط ۲۲۶
شفعہ ۲۲۷
مرد اور عورت کا طبقہ ۲۲۷
اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت ۲۲۸
الف:قبائلی معاشرے میں عورت ۲۲۸
ب۔عورت،ترقی یافتہ سلطنتی معاشرے میں ۲۲۹
ج:عورت دینی معاشرہ میں ۲۳۰
خلاصہ ۲۳۰
عورت کے بارے میں اسلام کا نظریہ ۲۳۱
عورت کے بارے میں اسلام کا نظریہ ۲۳۱
نکاح ۲۳۳
(ازدواج) ۲۳۳
نکاح کے مسائل اوراحکام ۲۳۳
نکاح کے احکام ۲۳۳
نوٹ ۲۳۳
نوٹ ۲۳۴
عقد کاولی ۲۳۵
اولاد کے حقوق اورتبعیت ۲۳۵
اسلام میں متعدد بیویاں ۲۳۵
طلاق ۲۳۸
(میاں بیوی کی جدائی) ۲۳۸
طلاق صحیح ہونے کی شرائط ۲۳۹
عدت کے احکام اور اس کی قسمیں ۲۴۰
عدت کی قسمیں ۲۴۱
اسلام میں غلامی ۲۴۲
اسلام میں غلامی ۲۴۲
غلام بنانے کے طریقے ۲۴۲
غلامی کے بارے میں اسلام کا نظریہ ۲۴۳
اسلام اور دوسرے نظریات کی تحقیق ۲۴۴
غلاموں کے ساتھ اسلام کاسلوک ۲۴۴
غصب ۲۴۶
غصب کے بعض احکام ۲۴۶
لُقطہ ۲۴۷
بنجر زمینوں کوآباد کرن ۲۴۸
نوٹ ۲۴۸
تخصیص اور مالکیت کی اصل ۲۴۹
اصل مالکیت کے دوتتمے ۲۵۰
١۔احکام ضمان کے دوحکم: ۲۵۱
جن چیزوں سے انسان مالک بن سکتا ہے ۲۵۱
کھانا پینا ۲۵۳
جان دار اور بے جان ۔ ۲۵۳
پہلی قسم :حیوانات ۲۵۳
الف۔ دریائی حیوانات: ۲۵۳
ب۔خشکی کے حیوانات: ۲۵۳
ج۔پرندے: ۲۵۴
نوٹ ۲۵۴
دوسری قسم :بے جان اشیائ ۲۵۴
ب: سیال چیزیں ۲۵۵
نوٹ ۲۵۵
ایک اہم یاد دہانی ۲۵۵
میراث کے کلی مسائل ۲۵۶
نسبی وارث(رشتہ دار) ۲۵۸
پہلاطبقہ ۲۵۸
دوسراطبقہ ۲۵۸
نوٹ ۲۵۹
تیسراطبقہ ۲۵۹
میراث کے حصے ۲۵۹
میراث کے فرض ۲۵۹
ماں باپ کی میراث ۲۶۰
اولاد ۲۶۱
دادا،دادی اورنانا،نانی ۲۶۱
چچا اور پھوپھی ۲۶۱
ماموں اورخالہ ۲۶۲
میاں بیوی کی میراث ۲۶۲
ولاء ۲۶۳
١۔ولائے عتق ۲۶۳
٢۔ولا ئے ضمان جریرہ ۲۶۳
٣۔ولائے امامت ۲۶۳
میراث کے احکام ۲۶۳
مر د وعورت کے حصوں میں جزئی فرق ۲۶۴
مرد اور عورت کی میراث میں فرق ۲۶۵
بیع ۲۶۶
( خرید و فروخت) ۲۶۶
بیع کیا ہے ؟ ۲۶۶
بیع عقد لازم ہے ۲۶۶
نقد،ادھار،اور سلم ۲۶۷
منابع ومآخذ کی فہرست ۲۶۸