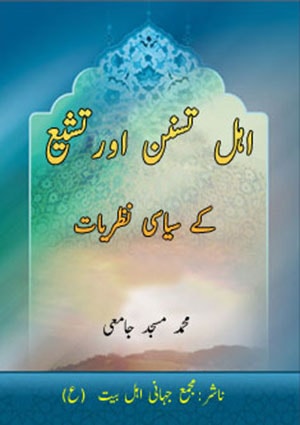یہ کتاب برقی شکل میں نشرہوئی ہے اور شبکہ الامامین الحسنین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں تنظیم ہوئی ہے
اہل تسنن اور تشیع کے سیاسی نظریات
محمد مسجد جامعی
مترجم: ضمیر حسین بھاولپوری
مجمع جہانی اہل بیت (ع)
مقدمہ ناشر
یقینا اہل بیت(ع) کی وہ میراث جسے ان کے مکتب نے ذخیرہ کیا اور اس کے ماننے والوں نے برباد ہونے سے بچایا، اسے ایک ایسے مکتب سے تعبیر کیا جاتا ہے جو اسلامی معارف کے تمام اصول و فروع کو حاوی ہے۔ لہٰذا اس مذہب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے افراد کی تربیت کرے جو اس کے صاف و شفاف چشمہ سے کچھ گھونٹ نوش کرسیکں اور امت اسلامیہ کو فیض پہنچانے کے لئے ایسے اکابر علما کو پیش کرے جو اہل بیت(ع) کے نقش قدم پر گامزن رہتے ہوئے تمام اعتراضات نیز مختلف مذاہب کے مسائل اور اسلام کے داخلی اور خارجی گوناگوںمکاتب فکر کا بہتر سے بہتر جواب دیتے ہوئے، صدیوں کے اعتراضات کا حل پیش کریں۔ چنانچہ اسی مقصد کی تکمیل کے لئے اہل بیت(ع) کی تأسی میں مجمع جہانی اہل البیت(ع) نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور حریم رسالت نیز ان کے ایسے حقوق کے دفاع کرنے کے لئے پیش قدمی کی جن پر ارباب فرق و مذاہب نیز اسلام دشمن عناصر اعتراضات کی بوچھار کررہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مکتب اہل بیت(ع) ہمیشہ ہونے والے اعتراض کا جواب دیتا اور اس کی رد پیش کرتا آرہا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی کوشش کرتاآرہا ہے کہ دشمن کے سامنے اپنے استقلال اور ثبات قدمی کا مظاہرہ کرے اور ہر دور میں اپنی مراد کو پہنچے۔
بیشک علمائے اہل بیت(ع) کی کتابوں میں موجود تجربے اپنی نوعیت میں بے نظیر اور انوکھے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسے علمی ذخیرے ہیں جن کی تائید عقل و برہان کرتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے دور رہ کر مذموم تعصب سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے فن میں متبحر اور ماہر علما، مفکرین اور دانشوروں کوایسے جالب انداز اور جاذب خطاب کے ذریعہ فکر و نظر کی دعوت دیتا ہے، جسے عقل اور فطرت سلیم قبول کرتی ہے۔ مجمع جہانی اہل البیت(ع) کی بھی یہی کوشش رہی ہے کہ حقیقت کے طالب افراد کے لئے انھیں تالیفات اور بحثوں سے حاصل شدہ بے نیاز تجربوں کے ذریعہ ایک نئے مرحلہ کا آغاز کرے، گذشتہ اکابر علمائے شیعہ کی تالیفات، تصنیفات اور تحقیقات نیز ان کے دیگر آثار کی بھی نشرو اشاعت کرے تاکہ حق کے تشنہ افراد کے لئے یہ تالیفات اور کتابیں ایک شیریں اور خوشگوار چشمہ کے مانند ثابت ہوں، مکتب اہل بیت(ع) نے جن حقائق کو بیان کیا ہے انھیں ایتمام آل محمد کے لئے آشکار کر یں، وہ بھی ایک ایسے دور میں جبکہ عقلیں منزل کمال تک پہونچ رہی ہوں اور انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بڑی تیزی اور آسانی سے بڑھتا جارہا ہو۔
محترم قارئین سے امید ہے کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی نظریات اور گرانقدر مشوروں سے نوازتے ہوئے تعمیری نظریات اور تنقید کا اظہار کریں گے۔
جس طرح ہم ان تمام اہمیت کے حامل مراکز، علما، مؤلفین اور مترجمین سے اسلام محمدیصلىاللهعليهوآلهوسلم کی اصل تہذیب اور بنیادی ثقافت کے تحفظ کی درخواست کرتے ہیں۔
اسی طرح خداوندعالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول کرتے ہوئے اپنی خاص عنایت کے زیر سایہ اپنے خلیفہ حضرت مہدی (عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف) کا اتباع کرنے کی روز افزوں توفیق سے نوازے۔
اب ہم اس کتاب کے مؤلف جناب محمد مسجد جامعی اور اس کے مترجم جناب ضمیر حسین کے بے حد ممنون اور شکرگزار ہیں کہ انھوں نے اس کتاب کو تالیف اور ترجمہ کیا، اسی طرح ہم اپنے ان تمام ساتھیوں کے شکرگزار ہیں جنھوں نے اس اثر کی تکمیل میں حصہ لیا، بالخصوص ان حضرات کا جو اس ادارہ ترجمہ میں کام کرتے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔
ثقافتی ادارہ، مجمع جہانی اہل البیت(ع)
بسم اللہ الرحمن الرحیم
مقدمہ مؤلف
آئندہ کی تاریخ اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ موجودہ صدی کی ۷۰ئ اور ۸۰ئ کی دہائیاں ، اسلام اور مسلمانوں کے سیاسی افکار و نظریات کی تاریخ میں اہم ترین موڑ ہیں، اب یہ کہ یہ موڑ کس طرح کے مستقبل کی صورت میں سامنے آئے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے؛ اہم بات یہ ہے کہ ایک بڑی تبدیلی آگئی ہے اور طرح طرح کے تجربات اسلامی دنیا میں بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس تبدیلی کے پشت پناہ ہیں۔
ا ن نکات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کا آنے والا زمانہ ،چاہے ایک دین کے عنوان سے ہو یا ایک مستقل تاریخی ثقافتی اور معاشرتی حقیقت کے عنوان سے ، پوری طرح یقینا موجودہ صورت حال سے وابستہ ہے اور یہ موجودہ صورت حال بھی اس دین کی گذشتہ تاریخ، خاص طور سے اس کے دورِجدید میں وارد ہونے کی کیفیت ، اس کے باہمی عمل اور ردعمل ، نیز اس کی اپنی درونی توانائیوں اور وسعتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ ان تین اسباب،ٍ خاص طور سے آخری سبب کا موجودہ حالت کے وجود میںبڑا کردار رہا ہے اور رہے گا۔ یہاں،اہم بات یہ ہے کہ ایک انقلاب آفرین محرک کے عنوان سے خود اسلام کے بنیادی اور فیصلہ کن کردار کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ ایسے لوگ بہت ہیں جو خود اسلام کی ذاتی توانائیوں اور صلاحیتوں اور بالواسطہ یا بلاواسطہ اثرات پر توجہ دیئے بغیر تاریخ اسلام میں رونما ہونے والے تغیرات اور موجودہ اسلام کی تحقیق میں مشغول ہوجاتے ہیں اور اس کو ایک ایسی تاریخی، ثقافتی اور معاشرتی حقیقت کے عنوان سے دیکھتے ہیں جو محض عصری تبدیلیوں پر مشتمل ہے، ایک ایسی حقیقت کے عنوان سے نہیں دیکھتے مذکورہ خصوصیات کے علاوہ مستقل طور پر خود اپنی فعالیت اور خلاقیت کا بھی حامل ہے۔ حالانکہ ادیان الٰہی اور ان میں سرفہرست اسلام، میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کااس آخری نکتہ کی طرف توجہ دیئے بغیر تحقیق وجایزہ ناممکن ہے۔
اس بات میں کہ دین، اپنے ماننے والوںکا ایمان و اعتقاد ہونے اور ان ہی کے ذریعہ معاشرے میں وارد ہونے کے سبب اور خود تاریخی اور معاشرتی قوانین پر مشتمل ہے،کسی کو کوئی کلا م نہیں ہے۔ کلام تو اس میں ہے کہ آیا اس کی ما ورائے تاریخ کوئی حقیقت ہے یا نہیںہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ دین کی تاریخ سے ماورا ایک مستقل حقیقت ہے اور ایک طرح سے اسے تاریخ کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس خصوصیت کی طرف توجہ کئے بغیر اس کو صرف ایک ایسے عامل کی حیثیت سے دیکھنا کہ جس کو تاریخ وجود میں لاتی ہو ، ہم کو غلط نتائج کی طرف لے جائے گا،اب اگر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں تو منطقی طور پرسے ہمیں بھی یہ قبول کرلینا چاہیے کہ دین کے تاریخ سے ماورا ہونے کا یہ عنصر بھی مختلف معاشرتی، فکری اور سیاسی حوادث کے مقابلے میں کارفرما رہا ہے اور اپنے اصول اور خصوصیات کے مطابق اس نے مختلف عکس العمل ظاہر کئے ہیں اور اس رد عمل کو جاننے کے لئے جس طرح سے تاریخی، معاشرتی ،اقتصادی اور ثقافتی حالات کا جاننا ضروری ہے ، اسی طرح اس عنصر کی انقلاب آفریں خصوصیتوں، اس کی توانائیوں کے سر چشموںاور حالات کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیتوں پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔
ادھر دو تین دہائیوں کے دوران اسلامی حلقوں اور مسلمان نشین ملک میں حقیقی اسلام پسندی کی ایک نئی لہر اٹھی ہے جس نے شیعوں اور سُنیوں دونوں کو متاثر کیا ہے۔ ان دونوں، خاص طورپر انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد اسلام پسندی کی یہ لہرجب اپنے کمال تک پہنچ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں(مکاتب فکر) ایک دوسرے کے مانند جدید واقعات کے سلسلہ میں بھی ردعمل ظاہر کریں گے۔ لیکن بعد میں جب احساسات کا یہ طوفان ٹھنڈا پڑ گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں اپنے اپنے تاریخی تجربوں، فقہی و کلامی اصولوں اور نفسیاتی و معاشرتی ڈھانچوں کے مطابق دو الگ الگ طریقوںسے نئے مرحلوں کو طے کریں گے اور یہ فرق جس طرح دو مختلف تاریخی تجربوں کا مرہون منت ہے، ٹھیک اسی طرح دو مختلف فقہی اور کلامی نظام کا بھی مرہون منت ہے۔ اس رہ گزر میں دونوں کی موجودہ صورت حال جو یہاں تک پہونچی ہے جدید مرحلہ کے جس قدر اپنے تاریخی تجربے سے ہماہنگی رکھتی اسی قدر اپنے اعتقادی نظام اور اصولوں سے بھی ہماہنگ ہے۔
موجودہ حالت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں نکات کاپوری یکجہتی اور دقت کے ساتھ جائزہ لیا جائے؛ خاص طور سے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ان دونوں فرقوں نے اپنی جامعیت اور تمامیت کیساتھ اپنے پیروؤں میں دینی، سماجی اور روحانی ڈھانچہ کوکس طرح تشکیل دیا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے یہاں زمانہ کے تغیرات، دباؤ اور خود پر عائد شدہ فرائض سے مقابلہ کرنے کے تین وسائل اور قابلیتیں پائی جاتی ہیں؟ یہ نکتہ اس سے قطع نظر کہ موجودہ حالات کے سمجھنے میں بہتر مدد کر سکتا ہے، کسی حدتک آئندہ کے حالات کی بھی نشاندہی کرسکتا ہے۔
یہاں ہماری بحث کا مقصدنہ تو مناظرانہ اور اپنی اہمیت جتاناہے کہ اسلام سے متعلق کونسا تجربہ اور کون سی تفسیر صحیح اور کونسی غلط ہے، نہ ہی اختلا ف آمیز مسائل کو چھیڑنا مقصود ہے کہ اسلامی اتحاد و بھائی چارگی میں خلل واقع ہو ؛ یقینی طور پر دونوں مکاتب فکر کے روحانی، تاریخی،اعتقادی اور فکری امتیازات کو غیر جانب داری کے ساتھ علمی پیرائے میں بیان کرنااور بتاناکہ ان امتیازات کے اسباب و علل کیا تھے اور ان کے نتائج اور اثرات کیا پڑے؟ چونکہ زیادہ گہرائی سے صحیح شناخت میں مددگار ثابت ہوںگے، ان کے چھپانے سے کہیں زیادہ ،اخوت اور اتحاد کے استحکام میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کی اس کھلی ہوئی، مواصلاتی ذرائع سے بھری دنیا میں نہ تو ہی ممکن ہے اور نہ ہی مناسب ہے کہ حقیقتیں خصوصاً جہاں وہ دین کی قوتوں اور گہرائیوں کی حامل ہوں لوگوں سے چھپائی جائیں۔ کسی بھی مکتب فکر کے مامنے والوں کی طرف سے اس کی حقیقت کا چھپایا جانا ہی اس بات کا سبب بنتاہے گا کہ دوسرے افراد اس کی تحریف شدہ شکل دنیا کے سامنے پیش کریں اور اپنے انداز میں اس کی تفسیر کریں ۔
تفاہم، ہماہنگی ، ہمفکری اور ایک دوسرے کے تئیں ذمہ داریوں کا احساس اور تقدیر ساز مشترکہ مسائل میں مشارکت اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب دونوں اخلاص اور شجاعت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھیں اور خود کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں کہ ہیں۔یہ امور آج کی دنیا میں ایک دوسرے کو کھل کر سمجھنے کے علاوہ اور ایک دوسرے کے احترام کی رعایت کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔
اس شناخت کا معمولی ترین نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے ان کے محدود وسائل اور اصول و نظریات کے دائروں سے زیادہ امیدیں اور توقعات نہیں رکھیں گے، (افسوس کہ یہی وہ مشکل ہے مسلمان جس سے ہمیشہ روبرو رہے ہیں اور آج بھی ہیں)انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کون ہیں اور ان کے مدمقابل کون ہے؟ اور وہ کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مقاصد اور ان مقصد کی تکمیل کے بارے میں دونوں کے تصور اور نطریات کیاہیں؟ اور کس طرح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مشارکت اور تعاون کر سکتے ہیں۔
یہ کتاب جوآپ کے سامنے ہے اُن چار تقریروںکی ذرا تکمیل و تفصیل کے ساتھ ترتیب شدہ شکل ہے جو ۱۹۸۷ء کے موسم خزاں میں عصر حاضرکے فن پاروں کے موزیم ہال میں کی گئی تھیں۔ اس زمانہ میں ان تقریروں کے اہتمام کا واحد مقصد یہ تھا کہ شیعوں ا ور سنیوں کے سیاسی افکار کے بنیادی میدانوں پر کھل کے گفتگو کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ میدان کیوں اور کس طرح وجود میں آئے؟ کن اسباب و عوامل سے متاثر ہیں؟ کس طرح ان دونوں کے سیاسی افکار میں مؤثر ہوئے ہیں؟ اور یہ کہ ان دونوں طرزتفکر نے موجودہ زمانے کے تیزی سے بدلتے ہوئے عجیب و غریب تغیرات نیز اس کی ضرورتوں اور تقاضوںکے مقابلہ میں کیا عمل و ردعمل ظاہر کیا ہے اور ظاہر کررہے ہیں۔ اور ایک آخری اور بنیادی ہدف یہ تھا کہ شیعہ ا ور سنی دونوں فریق ایک دوسرے کی صاف و شفاف اورحقیقی صورت کو بہتر طور پرپہچان لیں، ایک دوسرے کی فقہی اور کلامی حدبند یوں اور ضرورتوں کو نیز ایک دوسرے کے تاریخی تجربوں اور اعتقادی ڈھانچوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ایک دوسرے کی توقعات اور امیدیں ان ہی اصول و معیار ات اور قابلیتوں کے مطابق ہوں۔
اس کے باوجود کہ بیان شدہ موضوعات و مباحث کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا تھا، اس کے زیور تحریر سے آراستہ ہونے میں تاخیر ہوئی۔
یہاںجسبات کی یاد دہانی ضروری ہے وہ یہ کہ اس کتاب کی چاروں فصلیں ان ہی تقریروں کے محور پر نظم و ترتیب دی گئی ہیں۔ اگر یہ کتاب مستقل طورپر ان تقریروں پر توجہ کئے بغیر مرتب کی جاتی تو اس کے ابواب قائم کرنے میں تبدیلی نظر آجاتی اور بہت سی بحثیں ایک مستقل باب کی شکل میں پیش کی جاتیں، لیکن بعض اسباب و عوامل کہ جن میں سب سے اہم وقت کی تنگی مباحث کی وسعت اور دور حاضر کے مختلف مسائل کی پیچیدگی ہے کہ جن کے تحت یہ کام نہیں ہو سکا۔یہ واقعات اسی طرح ،سبب بنے کہ حوالے زیادہ اور بعض وقت طولانی ہو جائیں اور اس بات کے لئے ضروری ہوگیا کہ ہم اپنے محترم قارئین سے معذرت چاہیں۔
آخر میں مَیں اپنے اوپر لازم جانتا ہوں کہ ادارۂ تحقیقاتی امام صادقـ کے سربراہ حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی دام ظلہ کا شکر گذار ہوں، جنھوں نے اس کتاب کی نظم و ترتیب میں اپنے ادارے کے تمام وسائل خصوصاً اس (ادارہ) کے کتب خانہ کو میرے اختیار میں دے دیا تھااور میں نے پوری طرح اس سے استفادہ کیا، اسی طرح جناب بہاء الدین خرمشاہی زید توفیقاتہ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، جنھوں نے اس کتاب کی نظر ثانی کی ذمہ داری قبول کی اور جناب مصطفےٰ تاج زادہ کا ممنون ہوںجنھوں نے ان تقریروں کے انعقاد کے اہتمام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔
اسی طرح لازم ہے کہ جناب محمد باقری لنکرانی صاحب کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے ان تقریروں کے کیسٹوں کو زیور تحریر سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور یہ کتاب سب سے پہلے مرحلہ میں ان ہی کی زحمتوں، مشقتوں اور انتھک کوششوں کی مرہون منت ہے؛ اسی طرح جناب علی رضا بہشتی صاحب، جناب کیومرث امیری صاحب، جناب محمد باری دامت عزہم اور دوسرے بھا ئیوں کا بھی شکر یہ ادا کرتاہوں جن میں سے ہر ایک نے الگ الگ اس کتاب کے منظر عام تک پہونچنے میں لانے میں خاص اہتمام برتا ہے خدا ان سب کو ان کی زحمتوں کا اجر عطا کرے۔
محمد مسجد جامعی
موسم سرما۔۱۹۸۹ئ
پہلی فصل
دور حاضر کی دینی تحریکیں
آخری دس سال کے دوران اسلامی دنیا،عالمی سطح پر سب سے زیادہ بے چینی کا شکار، خبروں میں پیش پیش رہی ہے اور یہ مسئلہ صرف ایران تک محدود نہیں رہا ہے اور نہ ہے، بلکہ پوری اسلامی دنیا کا یہی حال ہے۔ اگرچہ اس مدت میں ایران اسلام پسندی کا مرکز، بلکہ اس تحریک کا روح رواں اور جوش و خروش کا محوررہا ہے۔
آج کل جس چیز کو اسلام کے احیا اور اسلامی اصول پسندی سے تعبیر کیا جارہا ہے، اس وقت اسلامی دنیا کے آخری مغربی حصے یعنی ''تیونس''اورمراکش تک اور مشرق میں اس کے آخری حصہ یعنی انڈونیشیا اور مسلمان نشین بستیوں پر مشتمل فیلپاین تک پھیل چکی ہے۔ بے شک ان تمام اسلامی ممالک بلکہ مسلمان نشیں ان ملکوں میں بھی جہاں وہ ملک کی آبادی کی نسبت اقلیت میں ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ مقامی باشندے ہیں یا غیرمقامی مہاجر، اس نئی اسلامی لہرسے متاثر ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کے اثر کو قبول کرنے کی کیفیت اور میزان یکساں نہیں ہے ، حالات کے اعتبار سے ان میں فرق پایا جاتا ہے۔
البتہ یہ انقلابات اور بے چینیاں صرف ان آخری دس سالوںسے مخصوص نہیں ہیں۔ شایداسلامی دنیا میں موجودہ اضطراب اور بے چینی اس صدی کے دوران دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلہ میں کچھ زیادہ اور نسبةً زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ کم سے کم یہ تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ موجودہ ادیان کے درمیان ،اسلام جس نے ایک دین کی حیثیت سے اور ایک تہذیب اور تمدن کے عنوان سے ،ایک مستقل تہذیب اور تمدن خود خلق کی ہے اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا رکھی ہے، دیگر تمام ادیان سے کہیں زیادہ اس دوران انقلابی ، ثابت قدم اور بر سر پیکار رہاہے۔ کسی بھی دوسرے دین نے اس حدتک نئی تہذیب و تمدن کی ہمہ گیر توسیع پسندی کے خلاف اپنا ردعمل نہیں دکھایا ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ انہوں نے ایک زمانہ میں کچھ عرصہ کے لئے کسی مثبت یا منفی پہلو سے انقلابی اقدام اور مقابلہ سے کام لیا ہو، لیکن بالآخر یا تو انہوں نے اس تہذیب کے تسلط کو قبول کرلیا یا پھر اس ایک طرح کی مفاہمت کے ساتھ صلح آمیز زندگی بسر کرنے کے لئے جھک گئے۔ یعنی اپنے اصول اور معیارات کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو موجودہ حالات کے سانچے میں ڈھال لیا ۔ کیونکہ اس کے علاوہ اپنے تحفظ کے لئے ان کے پاس نہ تو کوئی اور چارۂ کار تھا اور نہ ہی وہ کسی اور طرح سے اپنی اولاد اور پیرووںکے انحراف کو روک سکتے تھے۔(۱)
مختلف ادیان کے درمیان صرف اور صرف اسلام ایک ایسا دین تھاجو اپنے اصول و قوانین اور مذہبی حقائق پر ثابت قدم رہ کرنئی تہذیب وتمدن میں ضم نہیں ہوا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر برابر سے مقابلہ کیا اورکم سے کم اپنی سرزمینوں میں، اپنی حاکمیت اوربقا کی جنگ لڑتارہا۔ وہ حکمرانی جو نئی تہذیب و ثقافت اور اس کے علم بردار وں کے ذریعہ یا تو ناقابل قبول تھی یا پھر وہ اس کو محدود کردینا چاہتے تھے۔ اس آخری دہائی بلکہ صدی کے دوران اس دین کی استقامت اور مقابلہ آرائی کے واقعات اور کوششوں کی داستانیں ان کے سیاسی اور معاشرتی وجود کے تحقق اور مجاہدت و مقابلے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور یہ سب چیزیں خود اسی دین کی بدولت ہیں۔ اس دین کی اندرونی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنے پیرووں کو خود اپنے آپ کو ثابت کرنے اور غیروں کو ٹھکرا دینے کی کوشش کرتے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک مسلمان جب تک مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کے اصول و قوانین کی پابندی کرے۔ یہ اس کے اعتقاد نیز اس کی اخروی فلاح و نجات اور دنیوی عزت و سربلندی کا لازمہ ہے۔ یہ ایک دینی اور اعتقادی ضرورت اور ایک ناقابل تبدیل فریضہ ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کسی مختصر یا طویل زمانہ میں کسی سبب کے تحت مثلاً ضعف ایمان، یا پھر سماج اور معاشرہ کے نامناسب حالات کی بناپر اور عملی طور پر یہ فریضہ انجام نہ پائے لیکن ہمیشہ کے لئے اس کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک اسلام ہے اور مسلمان باقی ہے، یہ فریضہ بھی رہے گا اور اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ دین (یعنی دین اسلام) موجودہ حالات کے خلاف موقف اپنائے اور صورت حال کو اسلام سے ہماہنگ کرنے کے ارادہ سے حالات کے خلاف اُٹھ کھڑا ہو۔
مختصر یہ کہ اس دین کا ہربیگانہ چیز سے مقابلہ اور پیکار خود اس کی ذات اور حقیقت کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ مقابلہ آرائی کسی وقتی ابال یا جوش و جذبات کا نتیجہ اور مختصر مدت میں ختم ہوجانے والی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ مجموعی طورپر بیرونی اسباب و عوامل اس کے وجود و ظہور، اور وجود و ظہور کی کیفیت میں اہم کردار رکھتے ہیں، لیکن اصل سبب خود اسی دین کے اندر موجود ہے بیرونی اسباب و عوامل صرف حالات کو سزاوار و ہموار کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام ''سنت'' و ''بدعت'' کے درمیان ایک مسلسل اور کبھی ختم نہ ہونے والی جنگ کی تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام سنت کو قائم کرنے اور بدعت کو ختم کرنے کی ایک مسلسل تلاش اور کوشش ہے۔(۲)
اب یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ اس بدعت کی شکل اور اس کے پہلو کیا ہیں۔ جب تک بدعت کا وجود رہے گا جنگ بھی جاری رہے گی اور یقینا بدعت کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے لہٰذا قدرتی طورپر یہ جنگ و مقابلہ بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اگرچہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ یہ مقابلہ گرماگرم سیاسی انداز کا نہ ہو۔ مبارزہ کی شکل کیا ہو درحقیقت حالات طئے کرتے ہیں۔ لیکن اس کو ایک اصول کے طور پر جاری رہنا دین طئے کرتا ہے۔(۳)
اسلام کی پوری تاریخ خصوصاً آخری صدی اور دہائی کے دوران شیعہ اور سنی دونوں فرقوں میں ہم نے اس طرح کی جہادی کوششوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اسلامی احکام و قوانین کے نفاذ و استحکام اور اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تمام چیزوں کو ٹھکرا دینے کے سلسلے میں شیعوں اور سنیوں دونوں نے برابر سے ایک ہی انداز اور ایک ہی جذبے کے تحت جدوجہد کی ہے۔ درحقیقت اس مقابلہ آرائی کی بازگشت خود اسلام کی طرف ہے اور یہ مقابلے دو طرح کے نہیں ہوسکتے یہی وجہ ہے ایران کی مانند مذہبی ملکوں کے مقابلے اور پیکار کی داستانیں دوسرے اسلامی ممالک مثلاً عراق، شام، مصر اور پاکستان وغیرہ کے واقعات سے بنیادی قسم کا فرق نہیں رکھتیں اور اسی لئے دور حاضر کی تاریخ نے ان داستانوں کو یکساں طورپر بیان کیا ہے۔(۴) لیکن ان سب کے باوجود قبول کرنا ہوگا کہ ان کے درمیان کچھ فرق بھی پائے جاتے ہیں اور اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو بہت سی مشکلات اور غلط فہمیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔ اتحاد و یکجہتی کی کوششوں کی طرف موجودہ جھکاؤ اس بات سے مانع رہا ہے کہ ان فرقوں کو صحیح طور سے سمجھا اور جائزہ لیا جائے اور یہ ایک بڑی مشکل ہے جو صرف اسی صورت میں حل ہوسکتی ہے کہ جب پوری غیرجانبداری اور جرأت و دلیری کے ساتھ اس سے روبرو ہوا جائے۔
یہ فرق ایک طرف تو شیعہ نشین اور سنی نشین ممالک کے سیاسی، تاریخی، معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے مختلف حالات اور امتیازات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری طرف اس نے ان دونوں مکاتب فکر کے اعتقادی خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات نے معاشرتی مذہبی اور اعتقادی عمارت بنانے میں اپنے معتقدین کے درمیان جو کردار ادا کیا ہے ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان دونوں فرقوں کا اسلام اور دینی عقائد کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کا انداز دوطرح کا ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی دین فہمی اور عقائد کی روشنی میں پوری تاریخ کے دوران میں دو طرح کی مختلف خصوصیات سے متاثر ہوکر پروان چڑھے ہیں۔ دو الگ الگ ثقافتی، سیاسی اور معاشرتی ماحول میں زندگی بسر کی ہے ہیں لہٰذا ان کی نفسیات اور مذہبی شخصیت، افکار و نظریات اور مذہبی جذبات اور احساسات بھی دو طرح کے ہیں۔(۵)
اب چونکہ ان کے نظری عقائد کی خصوصیات کا تحقیقی جائزہ اسلامی تحریک کی موجودہ صورت حال کو ذرا گہرائی سے بہتر طورپر سمجھنے میں مدد کرسکتا ہے، ان دونوں (شیعہ اور اہل سنت) کے سیاسی افکار کی تحقیق بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے لہٰذا تمہید کے طور پر ہم اس کو بیان کررہے ہیں۔(۶)
شیعہ اور سنی حضرات کے سیاسی افکار کے سرچشمے
پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اصو ل و اسباب، چاہے تاریخی ہوں، یا فقہی اور کلامی (شیعوں اور سنیوں کی اور مذہبی سیاسی سوجھ بوجھ کی تشکیل میں کس طرح موثر ہوئے ہیں اور کیوں اس طرح وجود میں آئے ہیں؟ اور اس طرز تفکر نے ان کی گذشتہ اور موجودہ دینی سیاسی تغیرات کی تاریخ پر کیا اثر ڈالے ہیں اور ڈال رہے ہیں؟ آیا ان دونوں کی سیاسی اور معاشرتی حتیٰ ثقافتی تبدیلیوں کا سفر جہاں دین و مذہب کے ساتھ آمیزش اور ٹکراؤ ہوا ہے، یکساں رہا ہے یا دونوں میں فرق پایا جاتا ہے اور اگر فرق رہا ہے تو یہ فرق کس حد تک سیاست اور دین کے دائرے میں دونوں کے نظریاتی بنیادوں اور دونوں کے باہمی رابطہ کی کیفیتوں سے متائثر رہا ہے؟ نیز یہ کہ اس فہم نے دونوں مذہب کے ماننے والوں کے معاشرتی اور معنوی ڈھانچہ پر کیا اثر ڈالا ہے؟
اس موضوع کی گہرائی کے ساتھ تحقیق صرف اس لئے اہم نہیں ہے کہ اس کی روشنی میں اہل تشیع اور اہل سنت کے ماضی کو بہتر طورپر سمجھا جاسکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس پر توجہ دیئے بغیر اسلامی تحریک کی موجودہ حالت کو صحیح طورپر سمجھا نہیں جاسکتا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ موجودہ اسلامی تحریک، شیعہ اور سنی علاقوں میں یا کم سے کم بعض علاقوں میں یکساں طور پر احاطہ کئے ہوئے ہو ،لیکن اس سے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ تحریک ایک ہی جیسے مقدمات اور بنیادی نظریات سے وجود میں آئی، پھولی پھلی اور آگے بڑھی ہے تو یہ غلط ہے۔ سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی حالات کی تاثیر نیز ان دونوں مذاہب کے پیرووں کے کم و بیش مشترکہ سامراجی تجربات اور تاریخی ماحول موجودہ حالات وجود میں لانے میں اس قدر قوی اور فیصلہ کن رہے ہیں کہ کسی متشکلہ امر کے آغاز میں ہی ان دونوں مکاتب کی اعتقادی خصوصیات اور سیاسی، مذہبی عمارت کی اہمیت کو دو طرح سے اسلامی تحریک کے عملی تعیین میں صاف طورپر پرکھا جاسکتا ہے۔
البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مختلف میدانوں منجملہ سیاسی افکار کے دائرے میں ان دونوں کے بہت سے مشترکات کو نظر اندار کردیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں باہمی شباہتوں بلکہ بہت سارے مشترکات کے باوجود باریک قسم کے اہم فرق پائے جاتے ہیں۔ ایسے فرق اور امتیازات جن کو آج کے پیچیدہ حالات نے اور زیادہ بہتر طورپر نمایاں کردیا ہے۔ ان باریک اور ذہن سے پھسل جانے والے فرقوں سے غیر جانبدارانہ صحیح واقفیت جس قدر گہری ہوگی اتنا ہی ایک دوسرے کی شناخت میں مددگار ہوگی اور باہمی مشکلات و بدگمانیوں کو زائل کردے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان کو پیش کرکے ان کے بارے میں بحث کی جائے نہ یہ کہ ان کو پوشیدہ رکھا جائے۔
حقیقت یہ ہے کہ شیعہ اور سنی، خصوصاً سیاسی نظریات میں بالکل دو طرح کے مختلف مکاتب ہیں اور سیاسی و مذہبی تحریک، ان دونوں معاشروں میں دو طرح سے وجود میں آئی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک معاشرتی اور سیاسی تحریک خود اپنے حلقے میں موجود سماجی اور نفسیاتی حقیقتوں، تاریخی تجربوں اور اعتقادوں سے متاثر ہوتی ہے اب جبکہ یہ ثابت ہے کہ حقیقتیں مختلف ہیں تو فطری طورپر تحریک کو بھی متاثر کردیں گی۔ ایک شیعہ اور ایک سنی کے مذہبی نفسیات بھی مختلف ہیں اور ان دونوں کے دینی و معاشرتی ڈھانچہ میں بھی فرق پایا جاتا ہے اور جب ایسا ہے تو نتیجہ بھی خواہ مخواہ اس فرق سے ضرور متاثر ہوگا۔(۷)
بطور نمونہ ایران میں عام طورپر اہل سنت کے یہاں دینی اور سیاسی رہبری کا نہ ہونا عصر حاضر کی اسلامی تحریک میں ایک بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ جبکہ یہ تنقیدی پہلو شیعوں اور سنیوں کے درمیان ایک بے جا موازنہ کی دین ہے اور ناقدین نے اس نکتہ کو نظر انداز کردیا ہے کہ یہ خصوصیات دونوں کی فقہی، کلامی عمارت، روایتی تاریخ نیز نفسیاتی اور معاشرتی ڈھانچہ سے متاثر ہے۔ ایسی بنیادیں اور ضرورتیں اصولی طورپر ًاہل سنت کے یہاں نہیں پائی جاتیں جبکہ شیعہ، شیعہ ہونے کی حیثیت سے، نہ یہ کہ وہ ایرانی ہے یا موجودہ زمانہ میں زندگی بسر کررہا ہے، اپنے دینی لزوم کے تحت، نہ صرف رہبری کو قبول کرتا ہے بلکہ خود رہبر تربیت کرتا رہا ہے اور یہ ضرورت اور لزوم اہل سنت کے یہاں نہیں ہے۔ نہ تو ان کے یہاں اس طرح کا کوئی نظریاتی سرچشمہ پایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے یہاں کوئی تاریخی تجربہ رہا ہے؛ نہ تو ان کی معنوی اور مذہبی عمارت اس طرح کے ستون پر کھڑی اور بلند ہوئی ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں اپنے مرجع دینی کی طرف رجوع کریں اور نہ ہی ان کے مذہبی معاشرہ کا ڈھانچہ اس طرح کا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنے فیصلوں میں آخری نقطۂ اقتدار قرار دیں۔
مختلف نظریات
اس بحث کی اہمیت کے پیش نظر کہ جس کی یہ حامل ہے بہتر ہے ہم پہلے کتاب ''الفکر السیاسی الشیعی'' کے مؤلف علامہ محمد جواد مغنیہ کی بصیرت افروز تنقید کا ایک حصہ یہاں پرنقل کردیں۔ علامہ موصوف اپنی کتاب ''الشیعہ و الحاکمون'' میں تحریر فرماتے ہیں: ''جمہور اہل سنت حاکم جائر کی اطاعت اور اس کے ظلم و جور پر صبر کرنے کو واجب جانتے ہیںاور اس کے خلاف خروج کی اجازت نہیں دیتے، لیکن شیعہ ظلم اور برائی کے خلاف انقلاب اور مقابلے کو واجب جانتے ہیں۔ شیعیت اس مسئلہ میں سنیت کی مخالف ہے اور اس نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اکثر اہل سنت کی نظر میں کسی ظالم و جابر حاکم کے خلاف خروج دین اور اسلام سے خروج ہے اور شیعوں کی نظر میں اس طرح کا خروج عین دین ہے اس کے برخلاف ظلم پر صبر کرنا دین سے خروج شمار ہوگا۔ اور اسی مقام پر احمد امین اور ان کی مانند دوسروں کے اس قول کی سچی اور صحیح علت سمجھ میں آتی ہے جو کہتے ہیں: ''شیعیت ہر اس فرد کے لئے جو اسلام کی نابودی کا درپے ہو ایک سائباں ہے'' کیونکہ احمد امین اور ان کے بزرگوں کی نظر میں، اسلام ایک حاکم کے وجود میں، چاہے ظالم ہو یا عادل، مجسم ہوتا ہے لہٰذا ہر وہ شخص جو اس کے مقابلہ میں قیام کرے اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ لیکن شیعوں کی نظر میں خود حاکم ظالم ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے... اسی بناپر یہ بات تعجب آور نہیں ہونی چاہئے کہ وہ (احمد امین) ایک شیعہ کو اگر ''نابود کرنے والے'' سے تعبیر کریں۔ ''جی ہاں! یقینا شیعہ گمراہی اور برائی کو نابود کرنے والے ہیں۔''
''یہ حسن بصری تھے جو کہا کرتے تھے: ''بنی امیہ کی اطاعت واجب ہے اگرچہ وہ ظلم و ستم ہی کیوں نہ کریں... خدا کی قسم ان کے ذریعہ جو بھلائی سامنے آئی ہے وہ ان کی برائی سے کہیں زیادہ ہے۔'' اس کے بعد وہ اپنے بیان میں مزید اضافہ کرتے ہیں: ''شیعوں کے ائمہ، فقہا اور ادبا نے ہمیشہ حکام جور کے خلاف قیام کیا ہے اور ان کی مدد اور تعاون کو گناہ اور معصیت میں قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ تشیع اپنی حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے باطل کے خلاف قیام اور استقامت کا حامی ہے اور وہ حق کی برقراری کے لئے ایثار کا حکم دیتا ہے اور یہ معقول نہیں ہے کہ صاحبان قوت و اقتدار اس بات سے غافل رہے ہوں، یہی سبب ہے کہ وہ حکام جور شیعوں کو آزار و اذیت میں مبتلا رکھتے تھے اور ہر جگہ ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے علمائے سوء کو خرید لیا اور دونوں (حکام جور اور علمائے سوئ) نے مل کر طئے کرلیا کہ خدا و رسول کے مخلص مومنین اور ان کو قتل کردیں۔ یہ لوگ ان کے قتل کو مبارک سمجھتے اور ان کے خروج کے خلاف، اس دین سے کہ جس کی وہ تفسیر کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔''(۸)
جواد مغنیہ کی یہ بات خود اپنے مذہب کے سلسلے میں شیعوں کے عمومی تصویر کو بیان کرتی ہے اور اسی طرح اہل سنت اور ان کے علمائے سوء کے بارے میں ان کے خیال کی ترجمان اور یہ بیان اگرچہ اپنی حدتک صحیح ہے لیکن یہ کامل اور مکمل نہیں ہے؛ حقیقت کا ایک حصہ ہے نہ کہ پوری حقیقت؛ دیکھنا ہوگا کہ کیوں یہ ایسے اور وہ ویسے ہیں؟ آیا یہ صورت صرف شخصی اور اخلاقی دلائل کا نتیجہ ہے یا مسئلہ اس سے زیادہ گہرا اور باریک ہے۔ ان دونوں مکاتب فکر کے مواقف کا جائزہ لینے کے لئے پہلے مرحلہ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ انھوں نے اپنے اعتقادی، فکری، معاشرتی اور تاریخی فیصلوں میں کن بنیادوں پر عمل کیا ہے اور ان کے لزومات اور پابندیاں کیا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ بہرحال اپنے اعتقادی، فقہی اور کلامی حدود سے باہر قدم نہیں نکال سکتے تھے۔ جو شخص اپنے اصول و ضوابط اور اعتقادی ذمہ داریوں کے تحت اپنے قدم اٹھاتاہے نہ فقط یہ کہ وہ شخص سرزنش کے قابل نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اس کام کو اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ انجام دے تو وہ قابل ستائش اور تعریف بھی ہے۔
اگر کوئی اعتراض اور تنقید بھی ہو تو اسے بھی آزادی کے ساتھ ہونا چاہئے نہ یہ کہ خاص اصول (قواعد) اور معیار کو قبول کرکے اس کی پابندی کی جائے اور اسی طرح اصول اور فرائض سے دست بردار ہوکر توقع رکھنا ایک بے محل اور بے جا توقع کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔
مغنیہ کے بیانات نقل کرنے کے بعد (نقاد) تنقید کرنے والا اس طرح تنقید کرتا ہے: ''بغیر اس کے ہم اس بارے میں تعصب سے کام لیں اور تعصب کی آگ بھڑکائیں استاد مغنیہ کی قدر دانی اورشکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ ہم ان کے اس تجزیہ کی موافقت نہیں کرسکتے۔ ان کی احساساتی اور خاص روش پر توجہ کئے بغیر ایک عام انسان یہ احساس کرتا ہے کہ شیعہ اور اہل سنت کا حکام کے ساتھ سلوک اور برتاؤ بنیادی طورپر دو طرح کا رہا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد یہ دونوں حکام کی حاکمیت کے تحت دو مختلف حالات میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔''
اس کے بعد وہ اس طرح اضافہ کرتا ہے'': وہ نظریات جو فقہائے عظام سے صادر ہوتے تھے وہ کوئی شخصی اور ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ عا م مسائل سے متعلق تھا کسی فقیہ سے صادر ہونے والا فتویٰ اس کی شخصیت اور ذات سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ان کے ماننے والے اور پیروی کرنے والوں، مریدوں اور مقلدوں کو بھی شامل ہوتا تھا۔ لہٰذا کسی بھی مسئلہ کی اس طرح تحقیق و تجزیہ نہیں کرنا چاہئے۔ ان کے بیان میں ایک بہت بڑا اشتباہ اور غلط فہمی ہوگئی ہے جس پر کوئی ایک بھی محقق ان کی موافقت نہیں کرسکتا، اگرچہ یہ نظریہ کچھ ایسے حقائق اور مطالب پر بھی مشتمل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمیں اپنے موقف اور نظر یہ کے بیان میں شجاع اور صاف گو ہونا چاہئے، لیکن اس کے حدود اربعہ کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ بیان میں صراحت صرف ایک وسیلہ کی حیثیت رکھتی ہے نہ یہ کہ یہی ہمارا اصلی مقصد ہے لہٰذا اس صورت میں ہم نے اپنے مقصد کو وسیلہ پر قربان کردیا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف موقف یہ ہے کہ ظالم حاکم سے متعلق شیعوں کا موقف یہ ہے جس کی بازگشت ایک عمیق اور گہرے معیار کی طرف ہوتی ہے اس کی بنیاد ائمہ معصومین(ع) کا حکام کے ساتھ سلوک اور رویہ ہے اور شیعہ ان (ائمہ معصومین(ع)) کے تابع ہیں۔''(۹)
پھر بھی یہ مسئلہ کا ایک رخ ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ خود عوام ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اہل سنت کی فقہی و کلامی عمار ت نیز اہل سنت کا اجماع اور تاریخی تجربہ ان کے علما کے متعلق ان کے سیاسی اور معاشرتی میدانوں میں ہمیشہ ان کے علما کی کارکردگی اور فعالیت میں رکاوٹ پیدا کی ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ اہل سنت کے علما کی ایسی محدودیت نے اس پوری تاریخ میں عوام کی سطح امید کو بھی محدود بنادیا ہے۔ ایک مذہبی عالم کے بارے میں ان کی فکر او رسوچ بھی شیعوں سے بہت زیادہ مختلف ہے اور شیعوں کا اپنے علما کے بارے میں سوچنے میں فرق کے ساتھ ساتھ ان (شیعہ و اہل سنت) کی (اپنے علما کے ساتھ) توقع بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔
اہل سنت کے درمیان ان کا مذہبی عالم وہ شخص ہے جو باتقویٰ انسان ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی علوم میں خاص مہارت کا بھی حامل ہے اور اسی لئے وہ اپنے دینی مسائل میں اس (عالم دین) کی طرف رجوع کرتے ہیں۔(۱۰)
لیکن شیعہ نقطہ نظر سے ان کا عالم ان معیاروں سے کہیں اونچا ہے وہ لوگوں کے امن و امان کا مرکز اور ان کی پناہ گاہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ دینی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں بلکہ اپنے ذاتی امور میں بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے سیاسی ، سماجی اور معاشر ہ کے مختلف مسائل میں بھی اس سے کسب تکلیف کرتے ہیں اور یہ ایسا کیوں ہے؟ اس فرق اور اختلاف کو فقط معاشرتی دائرہ میں تلاش نہیں کرنا چاہئے ۔ ایک طرح سے اس اختلاف کا اہم جز سماج اور معاشرہ ہے اور وہ اس کے اعتقادی اور نظری ( Ideologic ) اسباب کے تحت ہے ۔ شیعوں کے نزدیک اجتہاد کے دروازہ کا کھلا ہونا اور زندہ مجتہد کی تقلید کا واجب ہونا، بالکل درست اہل سنت کے برخلاف ہے، یہ اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اس کے لازم اور ضروری ہونے کا فطری اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ لوگ ''اپنے جدید مسائل میں''(حوادث واقعہ) چاہے جس قسم کا نیا مسئلہ ہو اور وہ جس موضوع سے بھی متعلق ہو، دینی ضرورت کے تحت زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں اور اپنے جواب کو اس سے حاصل کریں اور اس کے ذاتی نظریہ کومعلوم کریں اس لئے کہ یہی (یعنی اس سے سوال کرنا) اور اس کی اطاعت کے واجب ہونے کے لئے معتبر اور قابل قبول ہے۔ اور ایک سنی عالم کی حیثیت ،فتویٰ نقل کرنے والے سے زیادہ نہیں ہے، (اس عالم سے چار مجتہدوں میں سے کسی ایک مجتہد کا نظریہ معلوم کرنا) اور وہ فتویٰ بھی ایسا فتویٰ جو ایک ہزار سال سے بھی زیادہ سابقہ رکھتا ہے۔ (اسی کے مقابلہ میں) ایک شیعہ عالم اپنی نظر بیان کرتا ہے یا کم از کم کسی زندہ مجتہد کے نظریہ کو بیان کرتا ہے۔ نفسیاتی اور ذاتی اعتبار سے بھی وہ شخص جو اجتہاد اور مقام فتویٰ تک پہونچ گیا ہو اور جس کی روحی اور ذاتی حیثیت جو زیادہ سے زیادہ نقل فتویٰ کے آخری مرحلہ تک پہنچ پائی ہو ان کا باہم مقایسہ نہیں کیا جاسکتا اور ان میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی ذہنی اور ذاتی سطح جو اپنا جواب پانے کے لئے دو مختلف عالموں سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر یہ فرق ماضی میں اسلامی مراکز خصوصاً اسلامی ممالک کے مذہبی معاشرہ کے بند ہونے کے سبب اور معاشرتی ثقافتی اور اقتصادی حالات کے بدلاؤ میں سستی کی بناپر کھل کر سامنے آنے کا موقع نہیں تھا، آج اس فرق کے ظاہر کرنے کا موقع فراہم ہوگیا ہے۔
اس مقام پر نکتہ یہ ہے کہ یہ تفاوت اور فرق کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایسا فرق ہے کہ کم و بیش یہ دونوں مذہبوں کی ابتدا سے چلا آرہا ہے البتہ موجودہ دور میں پردۂ خفاء سے نکل کر سیاسی عرصہ میں معاشرتی تجلی حاصل کرلی ہے۔
اس سے قطع نظر کہ اہل سنت کے اپنے بہت سے ایسے امور ہیں جن میںوہ لوگ حاکم کو یہ حق دیتے ہیں اور تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن شیعہ فقہ میں ان تمام امور میں فقیہ کی طرف رجوع کیا جاتاہے۔ یہ موضوع صرف سیاسی حیثیت کا حامل نہیں ہے۔ اس کی معاشرتی حیثیت بہ در جہ ہا بہت ہی قوی اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور ایسی صورت میں شیعہ عالم بھی اپنے کو ضروری اختیارات کا حامل سمجھتا ہے اور لوگ بھی اپنے تمام امور میں اس (مجتہد جامع الشرائط) کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہٰذا شیعہ عالم بھی اپنے آپ کو واجب الاتباع سمجھتا ہے اور لوگ بھی اس کی اطاعت کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ ایسے مسائل اہل سنت کا معاشرہ اور ان کی تاریخ نے کبھی بھی ایسا تجربہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ ایسے تجربہ حاصل کرنے پر قادر ہیں اور بہت بعید ہے کہ وہ (اہل سنت) آئندہ بھی اس بات کا تجربہ کرپائیں۔(۱۱)
دینی قیادت
دینی مرجعیت کا مفہوم اور مجتہد جامع الشرائط کی اطاعت کا واجب ہونا دقیق طورپر شیعہ فقہ اور علم کلام کے معیار سے وجود میں آیا ہے۔ یہ موازین اورمعیار جس طرح سے کہ مجتہدین کرام کو ان کے بلند و بالا مقام پر پہنچاتا ہے، لوگوں کو بھی ان (مجتہدین کرام) کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ شیعہ حضرات اپنے روز مرہ پیش آنے والے مسائل میں مجتہدین کرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مذہب تشیع کی (شیعہ) بنا وٹ کچھ اس طرح ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ ایسے مجتہدین کی تربیت کرکے ان کو سماج کے واسطے پیش کریں۔ پھر بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ علما اپنے ہم پلہ سنی علما کے مقابلہ میں جنگ طلب اور شجاع ترین رہے ہیں، بلکہ مسئلہ اس بات میں ہے کہ انھوں نے شیعوں کے نظری معیار کو مضبوط کر نے والی حتی ایسی خصوصیات کے موجد اور بانی ہیں۔(۱۲)
ایک شیعہ عالم اپنے عقاید پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر کسی شک و شبہہ اور کسی خوف و ہراس ایک حکومت کے مقابلہ میں ایسے مقامات پر جہاں وہ ضروری سمجھے قیام کرے ہے اور لوگوں کو اس قیام کی طرف دعوت دے ۔ لیکن اس کے مقابلہ میں ایک سنی عالم اپنے عقاید کے کون سے حصوں پر تکیہ کرکے ایسا اقدام کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سنی فقہ اور کلام میں بھی ظالم حاکم اور باد شاہ کے مقابلہ استقامت جس کو وہ جائز یا پھر لزوم کا قائل ہو ایسے مقابلہ کے کچھ نمونے ملتے ہیں لیکن اولاً یہ نمونے معارضہ اور ٹکراؤ (یعنی اس کے مقابلہ میں مخالف قول) سے دوچار ہیں۔ یعنی بہت سے مقامات پر اہل سنت کے درمیان بہت زیادہ مثالیں اوربہت ہی معتبرا قوال اس فکر کے مد مقابل موجود ہیں (اہل سنت کے نزدیک)۔(۱۳) دوسرے یہ کہ کم از کم ہم یہ صراحت اور قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو قطعی نصوص (یعنی قرآنی دلیلیں اور روایات ائمہ) شیعہ فقہ اور کلام میں موجود ہیں وہ سنی فقہ اور کلام میں ہرگز اس صراحت و قاطعیت کے ساتھ نہیں پائی جاتی ہیں اور اصل نکتہ یہی ہے۔ ایسے حالات میں کس طرح ایسے علما کے میدان میں آنے کی توقع کرسکتے ہیںجو اپنے اعتقادی و کلامی ا ور فقہی مسائل میں ذمہ داری کو قبول کرکے پابندی بھی کر یں اور عین اسی عالم میں وہ ایسی جنگ طلب خصوصیات کے بھی مالک ہوں۔
اس نقطۂ نظر سے یہ مسئلہ شخصی اور ذاتی مسئلہ نہیں ہوگا اور صرف شیعہ اور سنی علما کی ذاتی خصلتوں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ان دو نوں کے فقہی اور کلامی ڈھانچہ کا لب لباب ہے جس کے سب ان کے عالموں اور ماننے والوں کو اہم سیاسی مسائل میں اور اس کے مقابلہ میں اپنا اپنا مسلک اختیار کرنے میں ان لوگوںکی دو طرح سے پرورش اور تربیت کی ہے۔ فطری طورپر اس فکری اور نظری معیار کو اس پوری طولانی مدت میں معاشرتی اور سیاسی بنیادوں اور ان کے مذہبی رجحان کی عمارت کو اپنی خصوصیات کے مطابق مستحکم اور استوار کرکے عملی طورپر شیعہ حضرات اہل سنت و الجماعت اور ان دو مذہبوں کے علما کو دو مختلف تاریخی، معاشرتی، فکری اور اعتقادی میدان میں لاکر کھڑا کردیا ہے۔(۱۴) اگر ہم یہ چاہیںکہ ان دونوں (شیعہ اور سنی) کے فرق کی طرف توجہ دیئے بغیر ان کے بارے میں ملاحظہ کرسکتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی البتہ یہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے فعال جوانوں کا ایک مذہبی اور دیندار گروہ احزاب اسلامی کے ایسے مجموعہ میں (اسلامی گروہ) جمع ہوکر کسی ایک شخص کو سیاسی اور مذہبی ریاست کی کرسی پر بٹھادیں لیکن یہ بہت سخت ہے کہ ایسا قدم اس لحاظ سے کہ دینی بنیاد اور اس کے لزوم سے عاری رہے اور اور ایسی توفیق حاصل کر کے اس کی بقاء کے ضامن ہو جائے اور ایسے سخت حقائق سے مقابلہ کرنے میں خود درہم برہم نہ ہو۔ اس سے قطع نظر ایسے محدود اقدام کو تمام معاشرہ اور سماج میں نفاذ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ہر معاشرہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ترقی کے راستہ پر گامزن ہوجاتا ہے نہ کہ کسی خاص گروہ کے منشا اور چاہت کی بنیاد پر کہ جس طرح وہ چاہیں معاشرہ کو اس ڈگر پر لگادیں۔(۱۵)
بہرحال یہاں پر ان اختلاف اور فرق کی کامل توضیح دینا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بلکہ اس مقام پر اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ دونوں مذہبوں کے حامل لوگ موجود ہیں اور ان دونوں مذہبوں کی جڑیں تاریخ کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ (ان کے بارے میں قضاوت کرنے سے پہلے) یہ لازم ہے کہ علمی اور بغیر کسی پیش داوری اور پہلے سے فیصلہ کئے ہوئے ان کو پہچانا جائے تاکہ ہم نتیجہ کے طورپر ایک دوسرے کی بہتر پہچان کرسکیں اور اپنے اپنے اعتقادی خصوصیات سے زیادہ ایک دوسرے سے توقع نہ رکھیںاور ہر ایک کی وسعت کا لحاظ رکھیں۔ اس لئے کہ ایسی مشکلیں خصوصاً ان آخری سالوں میں موجود رہی ہیں۔
یہ معلوم کرنے کے لئے کہ شیعہ حضرات اور اہل سنت کی سیاسی افکار کی موجودہ اسلامی تحریک پر کیا اثر پڑا ہے، اس تحریک کی خصوصیات کو واضح و آشکار ہو نی چاہئیں۔ البتہ اس بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا جاچکا ہے۔ بلا شک و شبہہ ان آخری دس سالوں کے دوران ۱ بین الاقوامی سطح پر اس تحریک کے برابر ۱ لوگوں کے افکار اور نظریات کی توجہ کا مرکز نہیں بن پایا اور اپنی طرف جذب نہیں کرپایا ہے۔ البتہ اس مقام پر تحلیل و تجزیہ یا تکرار مقصود نہیں ہے بلکہ موجودہ زمانہ میں تاریخی اور معاشرتی پس منظر میں پوری تیسری دنیا جس کا ایک حصہ اسلامی دنیا ہے اس کے بارے میں چھان بین مقصود ہے۔
اپنے موقف سے اوپر اُٹھ کر سوچنا اور جامع رویۂ نگاہ سے، موجودہ اسلامی تحریک دورجدید کی تاریخ کا پیش خیمہ (طلیعہ) ہے جو تقریباً تمام تیسری دنیا پر چھاگیا ہے۔ اگرچہ اس تاریخی دورہ ظہور کے نمونے تیسری دنیا میں یکساں طور پر نہیں ہیں، لیکن جزوی طورپر ساری دنیا میں یہ پایا جاتا ہے؛ اور اسلامی دنیا میں کچھ خاص اسباب کی بناپر زیادہ قدرت کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ اگرچہ اسلامی دنیا میں بھی تاریخی حالات کے اعتبار سے اور دینی نفوذ کی گہرائی اور گیرائی کے تحت نیز اقتصادی تکنیکی و معاشرتی اور خلاقیت کے معیار کے اعتبار سے نیز سیاسی حجم کے بدلاؤ کے اعتبار سے، اس موج کی قدرت اور قوت مختلف ہے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اس کی وسعت ہر جگہ موجود ہے اور یہ تمام اشیا پر اثرانداز ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
جس وقت سے تیسری دنیا کے ممالک عصر جدید میں وارد ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے ورود کی کیفیت علاقوں کے اختلاف کے اعتبار سے بہت زیادہ مختلف تھی، ایک جدید تاریخی دور کا آغاز ہوگیا جو کم و بیش ۶۰ئ کی دہائی کے آخر میں اور ۷۰ئ کی دہائی کے شروع تک یہ (دور) باقی رہا۔ اس زمانہ کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا، جو از کم تہذیب و ثقافت، یاسی اور معاشرتی لحاظ سے ان کی طرف جھکاؤ کا آغاز ہو جاتا ہے ۔ جو اپنے پہلے والے دور سے بہت زیادہ اہم فرق کا حامل ہے۔ البتہ یہ فطری بات ہے کہ اس آخری دور میں تمام ممالک میں شروعات اور ابتدا کی تاریخ ایک نہیں ہے۔ تاریخی، اقتصادی اور سیاسی خصوصیات کے اعتبار سے ان تمام ممالک میں جلدی اور دیر سے بلکہ آخری دورہ میں شدت اور ضعف کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ۶۰ئ کی دہائی کے آغاز سے لے کر ۷۰ئکی دہائی کے آخر اور ۸۰ئ کی دہائی کے شروع تک عموماً تیسری دنیا کی حکومتوں میں موجودہ اضطراب اور بے چینیاں بالخصوص اسلامی دنیا میں اس دور جدید کی سیاسی علامتوں کے عنوان سے رونما ہوئی ہیں۔(۱۶) جو یا تو یکسر اور کاملاً اس تاریخی دورہ کی تخلیق ہیں یا ان خصوصیات کی زیر اثر قرار پائی ہیں۔
جس وقت سے تیسری دنیا والوں نے اس جدید تاریخ اور تمدن کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، اب چاہے استعمار کے راستہ کو اختیار کیا ہو اور چاہے زمانہ کے عمومی حالات اور فطری طور بغیر کسی سامراجی سیاست کو بروئے کار لائے ہوئے اس کام کو انجام دیا ہو، وہاں پر تاریخ کے نئے دور کا آغاز ہو جا تا ہے ۔وہ لوگ اس سے پہلے وہ اپنے گذشتہ طریقہ پر زندگی بسر کرتے تھے۔ اس طرح ان کی چین، جاپان سے لے کر ہندوستان، ایران، مصر اور تمام افریقی ممالک اس دور جدید کی لپیٹ میں آگئے اورجنوبی امریکہ کے ممالک کچھ تاریخی اسباب و عوامل اور ملکی آبادی کی بناپر ہماری اس بحث میں داخل نہیں ہیں۔ یعنی ہماری اس بحث سے خود بخود خارج ہوگئے ہیں۔ گفتگو ان ممالک کے اس گروہ کے بارے میں ہے جو خود اپنی ایک تاریخ اور مستقل تہذیب و تمدن کے حامل تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور اچانک اس نئی دنیا کے روبرو ہوئے تو ان میں تغیر اورتبدیلی پیدا ہوگئی اور اس طرح سے ان لوگوں نے ایک نئے دور میں قدم رکھ دیا۔بغیر اس کے کہ یہ تاریخی صانحہ جنوبی امریکہ کے مانند لوگوں کا جوق در جوق ہجرت کرنا، جو ثقافت اور تمدن کے لحاظ سے وہاں کے مقامی لوگوں سے بہت زیادہ فرق رکھتے تھے، اس کو قطع کردیا جائے اور طرح طرح کی تبدیلیاں ان پر تحمیل ہو جائیں۔( یعنی ان کے چاہت کے خلاف ان پر لاد دی جائیں)۔(۱۷)
ان سرزمینوں پر اس موجود تغیر و تبدل اور تبدیلی سے پہلے ان کی اپنی ذاتی تاریخی وثقافتی خصوصیات ایک حدود اربعہ میں تھیں لیکن جس وقت سے اس (نئی تہذیب) سے روبرو ہوئے اور آہستہ آہستہ اپنے اندر گیرائی اور وسعت پیدا کرلی تو ایک نئے دور کا آغاز ہونا شروع ہوگیا۔ یہ دور کچھ خصوصیات کا مالک تھا جو ہماری بحث سے متعلق ہیں ان میں سے چند اہم خصوصیتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔
شخصیات اور دانشوروں کی حکومت
اس دور کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ دانشور اور پڑھا لکھا طبقہ جن کے ہاتھوں میں زمام ِحکومت اور اقتدار تھا،وہ طبقہ جدید تہذیب و ثقافت سے اچھا خاصا متاثر تھا۔ باوجود اس کے کہ کبھی اس طبقہ (دانشور اور شخصیات) کی تاثیر بہت ہی عمیق اور گہری اور کبھی تاثیر قبول کرنے میں والہانہ انداز اختیار کرلیتی اور اپنے آپ کو بھول جانے اور سرمست ہونے کی حد تک پہنچ دیتی تھی، اس کے بر خلاف عوام کی اکثریت نے ۶۰ ئ و ۷۰ئکی دہائی کی ابتدا میں، مختلف معاشرتی واقتصادی حالات کے تیزیا سست اور مدھم بدلاؤ کے اعتبار سے سماج کے بسیط اور محدود ہونے اور حسب منشا براہ راست پورے طور پر اس نئی تہذیب کے اثر کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ اپنے روایتی اور قدیمی ماحول پر خاص طرز پر اپنی قدیمی روایت جو ان کے پہلے والوں سے ان کو میراث کے طور پر ملی تھی اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کررہے تھے۔ ان کے مقدسات وہی قدیم مقدسات اور ان کے زندگی گذارنے کا طریقہ، ان کی چاہتیں اور ان کا مثالیہ کردار اور نمونہء عمل( Idial ) سب کچھ قدیمی طور طریقہ پر تھیں۔ اگرچہ تہذیبِ نو کے بعض عناصر، چاہے ان دانشوروں، روشن فکر اور پڑھے لکھے طبقہ کے ذریعہ یاوہ لوگ اپنی زندگی میں روز مرہ کی ضروریات کو پورا کرنے اور تکنیکی چیزوں ( Technologic )کے روز افزوں دبائو کے تحت ان کی زندگی کا جز بن گئے تھے، لیکن وہ مجموعی حیثیت سے اتنی مقدار میں اثر انداز ہو کر حالات میں تبدیلی لانے پر قادر نہیں تھے۔ معاشرتی،مذہبی، ثقافتی اور اقتصادی بنیادیں یا تو بالکل ویسے ہی اپنی ہی قدیمی شکل میںباقی تھیںاوریا ان میں جدید انقلاب کی روشنی میںاس حد تک تبدیلی نہیں آئی تھی کہ ان کی قدیمی روایات،رسم و رواج اوران کی بنیادیںبالکل نابود ہوجائیں۔(۱۸)
یہ تاریخ کا تیسرا موڑ یا دور تیسری دنیا اور اسی طرح اسلامی ممالک میں بھی دو اہم خصوصیات کاحامل ہے۔ایک تو وہی خصوصیت ہے جسے سابقاً بیان کیا گیا ہے۔ یعنی دانشور، روشن فکر اور پڑھے لکھے طبقہ میں گہری تاثیر اور جن کے ہاتھوں میں ان کے معاشرہ کی زمام حکومت تھی ان لوگوں کا جدید تہذیب سے بے حد متاثر ہونا اور کم و بیش اپنی قدیمی تہذیب اور روایات سے دور ہوجانا (البتہ افراد، حالات اور ان کے علاقوں کے اعتبار سے اس تاثیر میں فرق پایا جاتا تھا) مذہب و ثقافت اور قدیمی وراثتوں اور رسومات عوام الناس کے ذریعہ ہمیشہ باقی اور زندہ رہیں۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ تمام معاشرہ پر جو نظام حاکم تھا اس پر بغیر کسی اختلاف اور نزاع کے قہر برساتے ہوئے اپنے مقدس نظام کو مصمم ارادہ والے نظام اور سماج کے کلی نظام پر تہذیب نو کو مسلط کردیا تھا، البتہ یہ تسلط اور قبضہ بھی ان دانشوروں کے ذریعہ وجود میں آیا۔ جو لوگ نئی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر تھے یہ غلبہ اور اقتدار ایک طرف سے ان دانشوروں اور شخصیات کے پختہ اعتقاد راسخ سے متعلق تھا جو نئی تہذیب کی مطلق برتری کے معتقد اور قائل تھے۔(۱۹) اور دوسری طرف سے ان عوام سے متعلق تھا جن کو ضمنی طور پر وہ عوام الناس اقرار کررہے تھے کہ اگر ایک خاص ماحول میں قدیمی روایات کے مطابق اپنے معاشرے میں زندگی بسر کررہے تھے، لیکن وہ ایک طرح سے اس نئی تہذیب کی بالادستی اور برتری کا یقین رکھ تے تھے۔ ایک ایسا اعتماد اور اطمینان کم سے کم واضح طور پر تہذیب کی بہ نسبت مخالفت کا اعلان نہ کرنے کے ذریعہ حاصل ہوا۔ اگر چہ بعض لوگوں نے خود جوش ، وقتی اور ناپائیدار مخالفت بھی کی جواس نئی تہذیب کے خلاف دیکھنے میں آئی ہیں، لیکن یہ مخالفتیں منظم نظام کے تحت، دائمی، پائیدار سوچے سمجھے نظام کے تحت نہیں تھیں۔بے شک اس دوران تہذیبِ نو کو تسلط بخشنے میں استعماری طاقتوں اور سامراج نے بھی بنیاد ی کر دار ادا کیا ہے۔(۲۰)
اجمالی طور پر اس تاریخی دور کی یہ فطرت عموماً تمام تیسری دنیا کے ممالک اور اسلامی دنیا کے ملکوں کی دور حاضر کی تاریخ بھی یہی رہی ہے۔ عوام الناس کی اکثریت اور ان سے متعلق تہذیب و ثقافت موجودہ پُرکار، فعّال، سیاسی، معاشرتی اورتہذیب تمدن کے ساتھ موجود رہی ہے۔ اس جدید تر طرز کے مالک دانشور اور نخبگان ہی حاکم مطلق تھے۔ ایک ایسی حاکمیت جو تاریخ جدید میں وارد ہونے سے پہلے جو کہ ظالمانہ حاکمیت کی اساس پر قائم تھی۔ صرف فرق یہ تھا کی یہ لوگ اپنی حکومت کو ظاہری طور پر نئی ) ( Modern اور سنوارے ہوئے تھے اور اتفاقاً یہی ظاہری خوبصورتی، ان کی حکومت کی پائیداری میں زیادہ مددکررہی تھی۔ ان کا واحد ہدف اور مقصد یہ تھا کہ معاشرہ کواس سمت لے جائیں جو ان کے لئے اہمیت اور ان کی خصوصیات کی طرف رہنمائی کرتا تھا اور یہ تمام چیزیں ظاہری طور پر تمام لوگوں کی رضا مندی کے سبب انجام پاتا تھا کم از کم قدیم وراثتوں کے ورثہ داروں اور اس کی حفاظت کرنے والے محافظین کے سکوت اور خاموشی کی بنا پر انجام تک پہنچتا تھا۔(۲۱) البتہ یہ ہرگز اس معنی میں نہیں تھا کہ تہذیب و ثقافت اور گزشتہ میراث یکسر فراموش کردی گئی تھیں اور نئی تہذیب کے دلدادہ اور جدت پسند دانشور حکام اس کی طرف توجہ نہیں کررہے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا بلکہ کبھی کبھی قدیم وراثتوں کی حفاظت کی تاکید بھی کی جاتی تھی۔ بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ نئے اور ان کے اہمیت کے حامل نظام اور تہذیب نو کی کیفیت پر غور و فکر کے بعد اس کے بارے میں خوب چھان بین اور قضاوت کی جاتی تھی۔ لہذا اس کی حقیقت سے بہت کم اور جو عام لوگوں کے درمیان موجود تھی، شباہت اور یکسانیت پائی جاتی تھی۔ گذشتہ زمانے کی ایسی تصویر اس کی ہویت و حقیقت، ضرورتوں، ان کے قلبی لگاؤ، مقاصد اور ثقافت، وہی معاشرہ پر حاکم ثقافت اور (نئی تہذیب کے علمبردار) حکام وقت یعنی دانشوروں کے ساتھ سازگار اورہم آہنگ تھیں۔(۲۲)
دقیق طور پر اسی کے تحت سبب عوام اپنی فعالیت کے اعتبار سے سیاسی اور معاشرتی زندگی میں فعال تھے۔ وہ لوگ ایسا وسیلہ تھے جو صاحبان قدرت اور معاشرہ کے جاہ طلب لوگوں کی خدمت میں آجاتے تھے، البتہ ہر دو فکریں جدیدیت کی علمبردار اور جدت پسندی کے عنوان سے سماج میں جانے جاتے تھے۔ اور عوام الناس اپنی کو ئی خاص نظر نہیں رکھتے تھے اورکبھی کبھی بے توجہی اور خوف و حراس کے ساتھ حوادث پر نظر رکھتے تھے نہ تو وہ لوگ عقلی اور فکری اعتبار سے اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ وہ لوگ جدید اور نئے نظریات کو حاصل کرلیں اور نہ ہی اس بات کی قدرت رکھتے تھے کہ تہذیب نو سے مقابلہ کر یں اور ان کی بلا منازعہ نئی تہذیب تمدن اور اس کی دعوت دینے والوں اور ان کے حامیوں جو کہ اس کے معاشرہ پر حاکم تھے اس کے مقابلہ میں آواز اُٹھا سکیں۔ تمدن نو، اس کی دعوت دینے والوں اور ان کے حامیوں کے زرق برق نے لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کردیا تھا۔یہ بھی اسی کے سبب ہے اس تاریخی دورہ کے سیاسی، معاشرتی بدلاؤ، تغیرات اکثر ان حکام (داشمندوں اور مفکروں) کے ذریعہ جوکہ موجودہ حاکم نظام کے خلاف سوچتے ہیں اکثر حکام یاجدا گانہ سونچ رکھنے والے شخصیت حاکم نظام کے ذریعہ اپنی موجودگی کو ثابت کردیتے تھے، البتہ اس کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ اس میں جوہری اور حقیقی فرق نہیں پایا جاتا تھا(یعنی بنیادی و اساسی مخالفت نہیں تھی) کیونکہ ہر دو طبقے صاحبان اقتدار (حاکم) اور چاہے ان کے سیاسی مخالف کہ ان میں کے اکثر سب کے سب طرز نو کی حامل شخصیات تھیں وہ لوگ Modernity ) جدت پسندی اور جدید تمدن کو مثالیہ کردار بنانے میں باہم مشترک تھے۔ اختلاف یا تو قدرت کے حصول کے بارے میں یا انداز اور سلیقہ کے بارے میں تھا۔ بعد والے دورہ کے بالکل برخلاف جو تغیر اور تبدیلی کو نہ تو یہ گروہ ایسا تھا جو عملی طور پر جو وہ لوگ ہیں جو اس کو وجود بخشتے ہیں۔(۲۳) جیساکہ ہم بیان کرچکے ہیں کہ اس دورہ کے سیاسی اور معاشرتی یہاں تک کہ فکری اور ثقافتی انقلاب مغرب پرست جدت پسند دانشوروں کے ذریعہ وجود میں آتا ہے۔ عام لوگ انقلابوں اور اپنی معاشرتی زندگی میں ایک کنارہ ہوجاتے ہیں اور لوگ یا لاپرواہی کے ساتھ دنیا کے حوادث کا نظارہ کرنے پر چُپّی سادھ لیتے ہیں یا ان کے ذریعہ اس نئی تہذیب کو مستحکم کیا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہرحال اس سے متاثر اور اس کے تابع ہیں نہ یہ کہ وہ خود فعال، سر نوشت ساز اور صاحب ارادہ بھی نہیں ہیں۔ اس مدت میں بھی قدرت دانشوروں اور شخصیات کے ہاتھ میں ہی تھی اور ان کے سیاسی قائدین، جو حکام وقت کے مخالف تھے وہ بھی انہیں دانشوروں میں سے تھے۔ گویا سیاسی اور معاشرتی فعالیت اور اثر کو قبول نہ کرنے کی صلاحیت عوام الناس کی عملی زندگی کے حالات سے زیادہ وسیع پیمانہ پر وجود میں آتی تھی۔
جو ا نوں کا میدان میں وا رد ہو نا
اقتصادی اور معاشرتی حالات کا تیزی سے بدلنا اور سیاسی ثقافتی دباؤکا بڑھ جانا ۵۰ ئ کی دہائی کی ابتدا اور اس کے بعد، ایک دوسرے تاریخی دور کے وجود میں آنے کے حالات ہموار ہوئے، جو زیر بحث ہیں۔ ایک ایسا دور جو فکری اور ثقافتی رجحان اور اسی طرح معاشرتی ضروریات ، سیاسی اقتضا اور اس کے نظام رہبری کے لحاظ سے پہلے والے دور سے مختلف اور جدا ہے۔تیزی کے ساتھ اقتصادی ، صنعتی اور تکنیکی تبدیلی کا آنا ( Technologic ) قدیم معاشروں کا منحصر اور محدود ہوجانا بلکہ تقریباً ان تجاری مراکز کا بند ہو جانا یہ چیزیں عام لوگوں کی اندرونی خواہشات کو چکنا چور کردیتی ہیں۔ ان کے معاشرہ کو بند اور انحصار سے بچنے کے جدید علم وفکر اور فلسفہ سے روبرو کردیتی ہے۔ جیسا کہ ان (عام لوگوں) کو اپنی قدیم تہذیب کی باواسطہ یا بلا واسطہ توہین وتحقیر اور ذلت ان کی قدیمی وراثتوں، رسم رواج اوردین و مذہب کے مقابلہ میں حساس اور ناراض کردیتا اور تیوریوں پر بل آنے لگتے ہیں۔ عام لوگوں کا بڑے شہروں میں آباد ہونا، وہاں کی آبادی کا بڑھنا، گروہی مواصلاتی نظام میں وسعت، تعلیم و تربیت کا عام ہوجانا، طبقاتی تضاد اور مخالفت کی زیادتی، ایسے اداروں میں سستی اور کندی کا آجانا بلکہ ان کا درہم برہم ہوجانا (ایسے ادارے) جو معاشر میں کسی شخص یا فرد کی مقام و منزلت اور اس کی شخصیت بنانے میں اساسی کردار ادا کرتے ہیں، (یہ تمام چیزیں) ایک نئی صورت حال کو جنم دیتی ہیں اور آخر کارظاہری اعتبار سے روشن فکروں کی تجدد پسندانہ حکومت جس کے پائے ثبات میں تزلزل ممکن نہیں ہے اورحاکم کی فکر اورآرزو نیز اسکی جدت پسندی کا لباس پہنتی ہیں۔(۲۴)
اب یہ کہ لوگوں کی قلبی خواہش کس طرح منتقل ہوکر ختم ہوئی اور دوسرے دورکا کس طرح آغاز ہوا اور معاشرتی اور ثقافتی حالات اور اس کا مطلق العنان تصرف کس طرح نابود ہو گی اور ایسا رجحان اور یہ قلبی میلان قاعدةً کیوں کر وجود میں آیا اور یہ قلبی میلان علاقوں اور معاشرہ کے کس حصہ میں زیادہ قوی اور مستحکم تھا؟ یہ ایسے مسائل ہیں جن کی الگ سے مفصل بحث کی ضرورت ہے۔اس مقام پر جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دورہ (اس صدی کے) دو تین گذشتہ دہائیوں سے شروع ہوا، البتہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شدت و ضعف(کمی وزیادتی)تقدم وتاخر تمام علاقوں میں اس کی علامتیں اور نشانیاں گذشتہ دہائی کے درمیان ظاہر ہو گئیں اور اس دور کی اہم خصوصیت'' حقیقت کی تلاش'' اور صرف اپنے آپ کو اہمیت دینا'' ہے۔ دوسری عبارت میں یہ کہا جائے کہ اس (دور) کا اصلی مقصد قومی، ملی، دینی، نسلی، لسانی اصالت اور حقائق کی طرف پلٹنا ہے، یہ چیزیں تاریخی اور ثقافتی امتیازات ہیں یہاں تک کہ اگر تجزیہ طلبی اور تو ڑ پھوڑ کا سبب بنے۔(۲۵)
ایسے دورہ کی پیدایش کے مظاہر کو تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں تلاش کہ کیاجاسکتاہے۔ تیسری دنیاکے بہت سے ممالک کے معاشرتی اور سیاسی اضطراب اور ناامنی، یہ اس مقام پر ان کے معاشرتی،سیاسی اورثقافتی حالات کی طرف پلٹتا ہے اور اکثر اسی دور جدید کی پیدائش کا سبب ہے،اس صدی کی آخری دہائی کی اسلامی تحریک کو بھی ان طبقہ بندیوں کے اندر جگہ دے سکتے ہیں۔(۲۶)
دورہ ٔجدید پہلے والے دورہ کے مقابلہ میں اہم تفاوت (فرق) کا حامل ہے۔ اس کی فطرت اور حقیقت کے اعتبار سے ہو یا اس کے معاشرتی اور ثقافتی حالات کے اعتبار سے اور یا اس کے مقاصد اور اس کی طرف جھکاؤ اور رجحانات (قلبی لگاؤ)کے اعتبار سے ہو۔ پہلے دورہ کی پیدائش نئی ثقافت اور تمدن کے ملاپ کا نتیجہ ہے اور گذشتہ تاریخی رہ گذر سے اُلٹے پاؤں واپس پلٹ آنے اور معاشرہ کو نئی تہذیب سے ہم آہنگ کرنے کی پوری کوشش، اس مقام پر صاحبان قدرت اور حکام نے کم سے کم منتظمین (حکومت کے منتظمین) سے متعلق ہوتا، اس طرح کا تھا۔ یہاں اس کے مقابل ایک عکس العمل سامنے آیا ہے ایسے آنکھ بند کر کے اثر قبول کرنے والے ملاپ کے مقابلہ میں بغیر کسی قید و شرط تابع ہونے اور اپنے آپ کو ان کی فکر کے مطابق ڈھال لینے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیںکہ (معاشرہ) اپنی اصالت اور قدیمی حقائق کی طرف لوٹ جائیں۔ اگرچہ اس ہدف تک پہنچنے کے لئے انہیں بھاری قیمت ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ وہاں پر قدرت اور حکومت کی باگ ڈور مغرب پرست دانشوروں کے ہاتھوں میں تھی اور وہاں کے لوگ عملی طور پر میدان سے دورتھے، وہ دور سے ان کی سیاست بازیوں کا نظارہ کررہے تھے اور یہاں پر حکومت اور اقتدار ان جوانوں کے ہاتھ میں ہے جو دور جدید کے معیار سے اپنا منھ موڑے ہوئے ہیں ۔اور لوگوں کی اکثریت (عوام الناس) بطور فعال سیاسی اور معاشرتی زندگی میں وارد ہوگئی ہے۔
ان دو تاریخی مرحلوں کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات کے باوجود، دوسرے مرحلے کی پیدائش پہلے مرحلے کی حاکمیت کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ جدید تمدن نے تیسری دنیا میں داخل ہوتے ہی، اس طرح آنکھوں کو خیرہ کردیا تھا کہ کسی شخص میں بھی اس سے مقابلہ اور ٹکر لینے کی ہمت تک باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ایک مختصر ساگروہ اسی( جدید تمدن)میں ضم ہوگیا اور لوگوں کی اکثریت کسی شدید عکس العمل کے بغیر تماشائی بنی رہی اور اس کے مقابلہ میں سکوت اختیار کر لیا۔ لیکن یہ ان کی آخری تسلیم اورخود سپردگی کے معنی میں نہیں تھی کہ انہوںنے اپنے آپ کو ان کے حوالہ کردیا ہو (خصوصاً ان علاقوں میں جہاں کے رہنے والے روشن اور درخشاں تہذیب و ثقافت کے وارث اور مالک تھے۔) گویا ان پر ایک قسم کا سکتہ (بے ہوشی) طاری ہوگیا تھا اور یہ حالت(اس صدی کے) آخری دو تین دہائیوں تک اسی بے ہوشی میں باقی ر ہی اور ان لوگوں کا اس حالت سے خارج نہ ہونا دوسرے نورانی مرحلہ کا پیش خیمہ تھی۔
بہر حال یہ بھی لازم تھا کہ ایک مدت گذر جاتی اور حالات میں بدلاؤ اور انقلابات رونما ہوتے اور تجربے حاصل ہوجاتے اور اس کے ساتھ جس میں واقعیت کے خلاف نامطلوب حالات سے ٹکر لینا پڑتا اور موجودہ حاکم کے مقابلہ میں قیام کی جرأت و جسارت پیدا ہوجاتی، تاکہ اتنا بڑا تغیر و تحول پیدا ہوجائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیسری دنیا کے بہت سے ممالک کے بڑے بڑے اقتصادی اور معاشرتی انقلاب، اقتصادی اور معاشرتی تبدیلیاں دوسرے تاریخی مرحلہ کو وجود بخشنے اور ظہور میں لانے کے لئے بہترین حالات فراہم کرنے والی رہی ہیں۔ قدیمی معاشرہ کا تربیت یافتہ جوان بہت ہی کم اور ضروری خصوصیات سے محروم تھا جو قدرت، ثقافت و تمدن اور موجودہ نظامِ حاکم کے مقابلہ کے لئے قیام کرسکے۔ اس کا امکان پایا جاتا ہے کہ ایمان میں استحکام اورپختگی اور دینی مسائل میں تعصب اس کو اس اقدام پر ابھارے اور یہ کوئی اقدام کر بیٹھے، لیکن یہ اقدام ایک بڑے حادثہ اور تحریک کو وجود میں نہیں لاسکتا ہے اور ایک جدید تاریخی دورہ کو اپنے ساتھ نہیں لاسکتا ۔ بعنوان مثال سکھوں کی تحریک جو ۸۰ ء کی دہائی کے اوائل سے اب تک اپنی مرکزی حکومت کے مقابلہ میں سخت استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی ہے، سکھون کی تحریک سب سے زیادہ ان آخری دہائیوںمیں ہندوستانی معاشرہ کے بہت بڑے تغیرات کی مرہون منت رہی ہے، نیز ہندوستانی قدرت مند لوگوں کے دستورالعمل بنانے کی کیفیت کی بھی مرہون منت ہے۔ بے شک اگر بجز اس آخری سبب کے علاوہ تمام اسباب موجود ہوتے تو بنیادی طور پر ایسی تحریک وجود ہی میں نہیں آتی یا کم از کم ایسے حدود اربعہ اور اس میں اتنی استقامت اور شدت پیدا نہ ہوتی(۲۷)
موجودہ اسلامی تحریک بھی مندرجہ بالا نکات کی طرف توجہ دیتے ہوئے جائزہ لینے کے قابل ہے اور دینی اور سیاسی علامت کے عنوا ن سے اسلامی دنیا کا یہ دوسرا تاریخی مرحلہ ہے۔ اگرچہ یہ تحریک، تیسری دنیا کی غیر اسلامی حکومتوں میں اس کے مشابہ دوسری سیاسی تحریکوں سے مقایسہ اور موازنہ میں یہ تحریک وسیع اور کافی عمیق( و گہری) ہے، البتہ یہ خصوصیات اسلام اور اسلامی تمدن کی طرف پلٹتی ہیں۔
دین اسلام مورد اعتقاد دین ہونے اور اسلامی تمدن اور ثقافت کے عنوان سے قابل فخر شان و شوکت والی میراث ہے ،جو اور عین اسی عالم میں مسلمانوں کی موجودہ تاریخی حقیقت بنانے کے اعتبار سے طرح موجودہ مسلمانوں کو سنوارنے والی ہے، اسلامی معاشروں کا جدید تمد ن سے روبرو ہوتے ہی، اسلامی تمدن لگا تار کسی نہ کسی طرح سے نکتہ چینی کا مرکز تنقید اور حملہ کی آماج گاہ حتیٰ مورد تجاوز قرار پایا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے بھی موجودہ تقاضوں کے تحت ان کے حملوں کا مقابلہ کر کے عکس العمل ظاہر کیا ہے، لیکن یہ عکس العمل کبھی بھی اس حد تک نہیں پہنچا کہ مغرب پرست حکام جو اسلامی مراکز پر قابض تھے ان کے افکار اور ان کی حکومت اور اقتدار کو ختم کرپائیں۔ اور اگر کبھی ایسے مواقع پیش بھی آئے ہیں تو وہ بہت ہی محدود اور بے اہمیت اور سطحی تھے اور زیادہ تر یہ حالات دینی پختگی، استحکام اور اس میں بہت زیادہ پابندی سے وجود میں آتی تھی نہ کہ فکرمیں بلندی، مطلوبہ معاشرتی اور ثقافتی پختگی اور بالیدگی کے استعمال اور صحیح سوجھ بوجھ کے سبب وجود میں آئی ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مغرب (مغرب پرستی) اس مدت میںاسی طرح اپنا پورے اقتدار کے ساتھ ان کے اتہامات کے مقابلہ میںاپنا قبضہ اور تسلط جمائے ہوا تھا حتیٰ کہ اسلام کا دفاع بھی انھیں کی مدد کا محتاج اور نیازمند تھا۔ ان کی دلیلوں کا لب لباب اس طرح تھا کہ اسلام تبھی حق ہو سکتا ہے جب وہ اگر مغربی تمدن اور جدید تمدن کے معیار کے مطابق اور موافق ہو اس لئے کہ اسلام در اصل انہیں (مغربی تمدن) کی طرح ہے بلکہ وہ ہو بہ ہو وہی ہے۔ اس مدت میں ساری کوششیں صرف اس بات پرکی جارہی تھیں کہ اسلام کے ایسا کوئی نیا تمدن کھوج نکالیں اور اس طرح سے انہیں کی حقانیت ثابت ہوجائے۔(۲۸)
یہ حالات تقریباً ۶۰ ء کی دہائی تک جاری اور برقرار رہے۔ لیکن وہ تمام اسباب جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے، اس بات کا سبب بناکہ مسلمانوں اور خاص طور پر جو ان طبقہ اور طلبا ( Students ) تیسری دنیا کے اپنے ہم عمر ساتھیوں کی طرح، شدت و سرعت کے ساتھ، دوسرا راستہ اختیار کرلیں۔ اس طرح دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگیا۔ جن ممالک میں اقتصادی، معاشرتی نیز ثقافتی، فکری اور مذہبی اور ثقافتی تغیرات میں تیزی و گہرائی زیادہ پائی جاتی تھی ان ممالک میں ایمان اور اسلامی تہذیب و ثقافت پر زیادہ ہجوم اور حملہ تھا اور اس پر مستقل دبائو بنا ہوا تھا ان علاقوں میں اسلام بہت جلدی نمایاں ہوا اور طاقتور اور عمیق تر ہوگیا اور انھیں ممالک کے ذریعہ دوسرے علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آگئے البتہ معاشرتی، و فکری و دینی رجحان اور اس کے حالات کے اعتبار سے کس حد تک اس جدید مرحلہ سے سازگار ہو کر زیر اثر قرار پاگئے۔
مشر قی سیاسی محاذ (( Bloc میں تبدیلیاں
یہاں پر مناسب ہے کہ مشرقی سیاسی محاذ ( Bloc ) کی موجودہ تبدیلیوں کو جو وہاں کے ساکن لوگوں، خاندانوں اور ملتوں کی مذہبی، دینی، قومی اور ثقافتی حقائق اور اسباب کا اثر قبول کئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اشارہ کیا جائے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اس( Bloc )سیاسی محاذ نے بہت سی مختلف دلیلوں (دلائل) اور اسباب کے ذریعہ تیسری دنیا کو دینی و ملی اور ثقافتی اصالت کی طرف لگاکر،ان کی اصالت اور حقائق کی طرف کھینچ لے گئی ہے ،لیکن یہ بات بھی قابل انکار نہیں ہے کہ یہ دونوں موجودہ زمانہ میں اپنے مقاصد کو پانے کے لئے کم و بیش ایک ہی مقصد کے حصول میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اور ظن غالب کی بنا پر اپنے ہدف تک پہنچنے میں کامیابی کے لئے ایک دوسرے کی تحریک ہر ایک اپنے لئے راستہ کھوج نکالنے کاسبب بنی ہے۔ اس بلاک Bloc ) (میں رہنے والے بعض قومی و نسلی اور خاندانی گروہ کی خود مختاری اور انفرادیت کی خواہش کبھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بلا شک و شبہہ اصالت اور حقیقت پرستی اور انفرادیت کی لہرتیسری دنیا والوں میں تحریک کی آگضرور دوڑا دے گی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بات کیا ہے اور وہ کیسے وجود میں آئی ہے؟
جیسا کہ تیسری دنیا کے موجودہ انقلابات اور تبدیلیاں عموماًایک جدید تاریخی دورہ کے سبب ان ممالک کی تاریخ میں وجود میں آئی ہے، ان پیوستہ سالوں میں مشرقی سیاسی محاذ (بلاک) کے بہت عظیم اور بہت سریع اور تیز تغیرات کے بھی جدید تاریخی مظاہر میں سے ایک مظہرجس کا آغاز ایک مدت سے ہو چکا ہے اور وہ اسی طرح باقی ہے اور باقی رہے گا۔ ان دونوں دوروں میں جو بنیادی اور اساسی فرق پایا جاتا ہے وہ اسی میں ہے کہ پہلے تاریخی دورہ کا تعلق تیسری دنیا سے ہے اور اس کی تاریخ مختلف اسباب و عوامل کے زیر اثر ہے جن میں سے اکثر نظامی، سیاسی اورتکنیکی کمزوریوں کے زیر اثر ہیں، وہ کمزوری اسی علاقہ میں باقی رہے گی، لیکن تاریخ کا موجودہ اور آخری دور اگرچہ وہ موجودہ زمانہ میں مشرقی بلوک( bloc ) میں ہے، لیکن یہ کہ (اوّلاً) اس کی پیدائش کے کچھ اسباب و عوامل بین الاقومی دلائل اور وجوہات کے حامل ہیں اور صنعتی ا ور غیر صنعتی چیزوں میں تیز تبدیلیاں (چاہے وہ فوجی۔ ٹکنا لوجی ہو اور چاہے غیر فوجی ٹکنولوجی ہو) ستّر اور اسّی کی دہائیوں میں ترقی یافتہ ممالک سے متعلق ہے۔(۳۰) دوسرا اس لحاظ سے ہے کہ یہ خیمہ (مشرقی بلاک) بین الاقوامی سطح کے دو بڑے سیاسی حصہ داروں میں سے ایک رہا ہے، لہذا اس کے محصلہ نتائج اس کے ملکی حدود سے بہت زیادہ وسیع اور بہت گہری حدود تک پہونچ جا ئے گا اور موجودہ دور کی پوری تاریخ میں ایک بہت بڑی گہری اور عمیق تبدیلی پر ہی تمام ہوگی۔
بہر حال سب سے زیادہ اہم اس دور کی خصوصیات کا حاصل کرنا ہے اور یہ کہ کیوں اور کس طرح یہ دور رونما ہوا ہے،؟ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اس دورکی پیدائش میں مختلف اسباب اور عوامل دخیل اور شریک رہے ہیں۔ یہاں پر اس دوران جائزہ لینے کا مقصد وہاں پر اس حد تک ہے کہ ثقافتی حقائق، ثقافت کے اپنے عام مفہوم کی طرف پلٹتے ہیں
یہ کہ یہ خصوصیات کیا ہیں؟ اور اس کے پیدائش کے اسباب اور عوامل کون کون سے ہیں؟اس نکتہ کے واضح اور آشکار ہونے کا لازمہ ہے کہ تہذیب و تمدن اور اس کی نئی تاریخ کا آغاز کس طرح ہوا؟ اور ان ممالک میں (اس سے مراد وہ ممالک ہیں جنہوں نے بعد میںمشرقی خیمہ ( Bloc ) کو ڈھوندھ نکالا) اس کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا ہے (مشرقی بلوک ) ان ممالک میں کس طرح اپنے قدم جما کر وہاں پر ڈٹ گیا اور کس طرح ان ممالک میں جذب ہوکر اس نے اپنا کام شروع کیا؟ اور کیا کیا تغیرات اس نے پیدا کئے؟ اور قدیمی تہذیبوں، ثقافتوں ، تمدنوںا ور قومی و لسانی اور دینی و مذہبی وراثتوں اور مجموعی طورپر یہ کہا جائے کہ جو چیزیں اس سر زمین کے لوگوں کی تاریخی، ملی ،قومی ماہیت اور حقیقت کوتعمیر کرنے والی ہیں ان کے ساتھ اس (مشرقی بلاک)کاکیا رویہ رہا ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اس معاشرہ پر حاکم طاقت (حکومت) نے اس بارے میں کیا موقف اختیار کیا؟ اور کس طرح اس نے صنعتی، اقتصادی اور معاشرتی میدان میں ان کو وسعت دے کر ترقی کے راستہ پر گامزن کردیا؟آخرکار آیا قدیمی تہذیب و ثقافت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور نئی تہذیب ثقافت اور اس کی ضروریات اور چاہتوں کے علاوہ بالکل کچھ نہ سوچا اور یا مقامی تہذیب و ثقافت کے پھلنے پھولنے کے لئے کوئی موقع نہیں چھوڑا اور ا سے دشمنی کی نگاہ سے نہیںدیکھا۔(۳۱)
اس (نکتہ) بات کا جائزہ لینازمانۂ حال اور آئندہ کے بہت سے تغیرات کی بنیاد کو واضح اور آشکار کر تا ہے ۔ اگرچہ مشرقی سیاسی محاذ ( Bloc ) کے بہت زیادہ محسوس اسباب و عوامل جو اکثر سیاسی، اقتصادی ا ور صنعتی حیثیت کے حامل تھے وہ تبدیلیاں شروع ہوگئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحولات اور تبدیلیاںقاعدتاً بدلاؤ لا نے والی پوشیدہ صلاحیتیں ایک اعتبار سے ان تبدیلیوں کا سبب بنی ہیں، اس کو اپنے فطری راستوں پر قرار پا جانا چاہئے تھا۔ البتہ ان راستوں میں سے ایک بہترین راستہ اور طریقہ حقیقت طلبی اور قدیمی روایتی رسم و رواج پر لگا دینے کا راستہ تھا۔ اکثراً اسی سونچ کے زیر نظر اور اس کے ماتحت ہے کہ تغیرات اور تحولات، اس مقام پر لوگوں سے متعلق ہیںاور کھل کر سامنے آجاتے ہیں اور قوی احتمال کی بنا پر یہ ماتحتی بھی موجودہ سیاسی اور معاشرتی تغیرات و تحولات میں خود ہی مؤثر سہم (حصہ) کی حیثیت رکھتا ہے، مستقبل میں بھی یہ اپنی اہمیت کو اسی طرح محفوظ رکھے گا۔
اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جدید تمدن نے شروع میں جنوبی یورپ کے کچھ علاقوں اور اس کے بعد مغربی یورپ میں وجود میں آئے اور پھر اپنے پیر جمالئے وہاں پر یہ پھلا پھولا اور پروان چڑھا۔ یہ تمدن فطری طور پر طرح طرح کے تغیرات اور تحولات کا محصول اور ثمرہ تھا کہ عام طور پر مغربی یورپ کے ممالک کو رنسانس کے بعد میں آنے والی صدیوں پر محیط ہوگئے تھے۔( یعنی ان پر پوری طرح مسلط ہوگئے) لہذا اس کے علاوہ کہ ان علاقوںمیں انہوںنے اپنے مختلف تاریخی مراحل کو گذارا تھا، اپنے آپ کو ان سر زمینوں کے تاریخی ، سیاسی ا ور معاشرتی حالات کے مطابق ڈھال لیا تھا اور موجودہ حالات کو بھی اپنے لئے سازگار اور ہماہنگ بنالیا تھا۔ یہ تمدن (تمدن نو) اسی درخت کا ایک پھل ہے اور یہ دونوں باہم کامل سازگاری اور فعالیت میں دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور مد مقابل تھے۔
توسیع اور ترقی کا بر ابر اور خلّا ق نہ ہو نا
لیکن یہ تناسب اور باہم سازگاری و ہم آہنگی جو مغربی یورپ میں موجود تھی اوردوسرے علاقوں میں ہرگز ایسا نہیں تھا منجملہ مشرقی یورپ اور روس اگرچہ مشرقی یوروپ کے بعض ممالک مثل یوگوسلاوی (چک اسلواکی)، مشرقی جرمنی اور ایک حد تک مجارستان و لہستان گذشتہ اور موجودہ صدی میں کمیونسٹوںکے قبضہ سے پہلے یا تو وہ خود مغربی یورپ سے وابستہ تھے یا پھر کم سے کم اس کے ثقافتی مراکز سے وابستہ تھے یا بلا واسطہ اور تدریجی طور پر اس سے متاثر ہورہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرے مشرقی یورپی ممالک نہ ان (مغربی ممالک) کے جغرافیائی مراکز سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی ان کے ثقافتی مراکز سے ان کا کوئی رابطہ تھا۔
یہ بات متحدہ روس (اب روس تقسیم ہو کر بہت سے ملکوں میں تبدیل ہوگیا ہے۔(بقلم مصحح)کے بارے میں زیادہ صحیح ہے۔ یہ ملک خود ایک برّ اعظم کے مانند ہے کہ جس نے یورپ اور ایشیا کے ایک بڑے حصہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، مختلف قومیں، ملتیں اور مختلف ثقافتوں کواپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اس (روس) کے مغربی حصوں میں آباد غیر روسی لوگ جن کی تہذیب و ثقافت اور خصوصیات مغربی یورپ والوں سے مشا بہ ہے مثال کے طور پر بالکان کے ثقافتی مرکز سے وابستہ اور اس علاقے کے رہنے والوں کے مانند ہیں یعنی ان سے شباہت رکھتے ہیں اس کے ایشیاکے گرد و نواح کے علا قوں کے لوگ مرکزی ایشیا اور ایشیا ئے بعید کے لوگوں کی جیسی خصوصیات کے مالک ہیں یہاں تک کہ مغربی ایشیا کی قومیں اور اس میں زندگی بسر کرنے والی دوسری قومیں بھی اسی سے شباہت رکھتی ہیں۔(۳۲)
اگرچہ تمدن جدید کی ان سر زمینوں میں آمد اس حد تک کہ تیسری دنیا کے ممالک میں اس کا وارد ہونا خاص طور سے وہ ممالک جو قدیمی اور روایتی زندہ ثقافتوں والی مستحکم اور قدرت مند تھیں مشکل ساز نہیں تھیں، لیکن اس تہذیب و ثقافت کی آمد اوربالخصوص اس کے وارد ہونے کی کیفیت اتنی زیادہ آسان اور بے زحمت نہیں تھیں۔ یہ پریشانیاں اور تکلیفیں ان سر زمینوں پر حاکم ثقافت اور نئی تہذیب وتمدن کے ٹکرائو سے کہیں زیادہ پہلے تیسری دنیا کے بہت سے ممالک کے مانند، بنیادی جڑوں کی حامل رہے، مختلف شعبوں میں معاشرے کے لئے صنعتی، اقتصادی اوراجتماعی میدانوں میں معاشرہ کی تعمیر کے لئے اب بھی بہت سی مشکلات موجود تھیں۔
مارکس کے نظری عقیدہ ( Marxism )کی تابع حکومتیں خودان ممالک پر حاکم، نظام پیش قدم لوگوں کے عنوان سے جدید تمدن کی وسعت اور صنعتی نوسازی اور اپنے معاشروںکو جدید ( Modern ) بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ نئی ساخت و ساز سے ان کا مسلح ہونا جوان کی نظر میں بطور کامل اشتراکیت کے نظام میں نمایاں ہوکر چمک رہی تھیں اور متجلی تھیں، فوجی و سیاسی ا ور اقتصادی طاقت کو ان ممالک میں متمرکز بناکر مقامی، قومی اور دینی ثقافتوں کی حقیقت جیسے تھی ان کو ویسے ہی ظاہر ہونے سے مانع تھیں۔ یا ان لوگوں کو سانس لینے کے لئے کوئی موقع فراہم نہیں ہونے دیا آخرکار ان لوگوں کو صرف اتنی فرصت دی جاتی تھی کہ وہ اپنی تہذیب کو ''مارکس'' کے نظریہ سے مطابقت دے لیں اور اسے اپنے دین اور ثقافت کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریںاور اس تفسیر کو در حد امکان مناسب ترین تفسیر سمجھ کر قبول کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ''مارکس'' کے نظریہ کو مطلق العنان اور آزاد چھوڑ کر اس کو حقیقت کی شناخت کا معیار قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کو بہترین اور آخری راہ حل سمجھ لیا جائے اور اس فکر ونظر کی رعب ووحشت اور طاقت کے بل بوتے پر تبلیغ و ترویج کرکے اس کو منوا لیا ،یا موجودہ اور رائج تہذیبوں اور ثقافتوں کو زبردستی بے حس کرکے پردۂ خفا میں ڈال دیا، اس کے بغیر کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں یا اس کو ذراسا بھی کمزور کریں۔(۳۳)
مشرقی خیمہ( Block )کے بعض ممالک کا فعال، خلاق اور عمومی سہم نہ رکھنے کے سبب تمدن نو کے وجود میں لانے اور اس کے( پھلنے وپھولنے) ترقی دینے میںکسی سیاسی کردار کا حامل نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی ان ممالک کا اس ثقافت سے تضاد اور اختلاف اور ان کی بیگانگی اور اس کے بابت اس مقام پر مفید اورکار آمد تجربہ کا نہ رکھنا اور اشتراکیت اور مارکسیسم کے قالب میں ان حکومتوں پر قابض ہوجانا (خود تمدن جدید کی تجلیات میں سے ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ مغربی یورپ کے حالات و احوال انیسویں صدی کے وسط میں اس جدید تمدن کے حالات کے لئے مقتضی ہوئے بلکہ اس کی ضرورت محسوس کی۔)(۳۴)
فوجی اور سیاسی آمرانہ نظام اور اس چیز کا باعث ہوئی کہ مقامی و علاقائی تہذیب وتمدن اور ثقافتوںکواپنے اظہار وجود اور موجودہ صورت حال سے مطابقت دینے کی انہیں مہلت ہی نہ ملے، یا وہ خود اپنے آپ خاموشی اختیار کرلیں یا ان کو زبردستی سکوت کے لئے مجبور کردیا جائے۔
قدیمی وراثتوں کے بارے میں حساسیت
ایک طرف مرکزی حکومتوں کا دبائو ان تہذیبوں اور ثقافتوں سے وابستہ لوگوں کو اپنے قدیم ا ور وراثتی تہذیب کی نسبت حساس بنا رہا تھا اور دوسری طرف سے موجودہ صنعتی اور اقتصادی تغیرات کو اپنے اور اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنا جو ان حساسیتوں میںجلوہ گر تھا، اس چیز پر آمادگی کے تمام حالات فراہم کرکے ان کو مستحکم اور قوی بنا رہا تھا (جیسا کہ ہم پہلے بیان کرچکے ہیں) اقتصادی اور صنعتی تغیرات اس کے بالکل برخلاف لوگوں بالخصوص جوانوں کو قدیمی میراث اور تمدن کے بارے میں یہ تصور چاہے مذہبی ہو یا تاریخی اور یا ثقافتی وراثت کے بارے میں ہو، طولانی مدت میں آہستہ آہستہ اس سے تعلق بڑھارہا ہے۔
عموماً یہ ممالک اس سے پہلے کہ سالم اور کھلی فضا میں بغیر کسی آمر (حاکم) کے دبائو کے اس نظری اعتقاد سے مسلح ہو کر جو اس بات کے مدعی تھے کہ وہ بہشت جس کا آخرت میں وعدہ کیا گیا ہے اس کو روئے زمین پر لے آئیں گے، نئی تاریخ کو نئے تمدن کی روشنی میں آزما ئیںایک دوسرے کے ساتھ ساتھ زندگی گذارنے اور ملی ا ور قومی مصلحتوں کے بارے میں فکر کرنا سیکھیں، وہ اپنی ہی تعمیر پر مجبور ہوکر خود اپنے کو اشتراکیت کی خصوصیتوں اور اعتقاد کے مطابق سنوارنے میںمشغول ہو گئے۔ ان کی اقتصادی و صنعتی وسعت اور معاشرہ اور ثقافت کی ترقی کے ساتھ ساتھ قدم بہ قدم اپنی قدیمی اور قومی وراثتوں کی حفاظت کے شعور کو بھی بیدار کریں اور ملی یکجہتی اور اتحاد کو تقویت بخشیں وہ لوگ ایسی صلاحیت کے مالک نہیں تھے۔(۳۵) البتہ یہ مشکل اس وقت تک باقی رہی جب تک ان کے سر پر فولادی ہتھوڑا پڑتا رہا اور اظہار کرنے کی جرئت نہیں تھی لیکن جیسے ہی دباؤ کی شدت اور زور کم ہوا، حقیقت خود بخود کھل کر سامنے آگئی۔
یہ اہم ترین دلیلوںمیںسے ایک دلیل ہے جو مشرقی یورپ کے ترقی یافتہ اورصنعتی ممالک میں قومی بے چینی اور اضطراب کے نہ پائے جانے کو واضح اور آشکار کرتی ہے۔ان ممالک کا ترقی حاصل کر لینا اور صنعتی اعتبارسے ترقی یافتہ ہو جانا''مارکس'' کے نظری اعتقاد کی تابع حکو متوںسے پہلے والے نظام کامرہون منت ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ وہ لوگ تسلط سے پہلے کافی آزاد فضا میں، جدید تمدن کا تجربہ کر چکے ہیں اور اس تجربے کے درمیان ملی ا ور معاشرتی مطلوبہ اتحادپاچکے ہیں۔ البتہ اس کامقصدیہ نہیںہے کہ ہم دوسرے اسباب کی کار کردگی کو نظر انداز کردیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی صنعتی ا وراقتصادی ترقی اس لحاظ سے ہے کہ ان کی ترقی کی کافی آزاد ماحول اور کھلی فضامیں مضبوطی اور قاطعیت کے ساتھ بنیاد رکھی گئی ہے اور یہ بھی کوشش کی ہے کہ ملی و قومی اتحادا ور انسجام کو مقتدرانہ طور پرہدیہ کے عنوان سے پیش کرے۔
اگر ان حادثات کے برخلاف دیکھنا چاہیں تو روس کی آزادی طلب ریاستوں کے نظریہ میں روس کے مختلف صوبوں یوگو سلاوی، رومانی اور بلغارستان کی قومی کشیدگی میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ روس کی جنوبی جمہوری ریاستوں کے موجودہ رجحانات میں بھی یہی حکم نافذاور رائج ہے۔ اگرچہ عملی رجحانات کا عملی ڈھانچہ ان آزاد ریاستوں (حکومتوں) میں اس لحاظ سے ہے کہ اس کے رہنے والے (باشندے) عموماً مسلمان ہیں لہٰذا بالٹیک کے علاقہ کی مرکزی جمہوری ریاستوں میں اس کی عملی کیفیت میں فرق پایا جاتا ہے، یہ تفاوت ایک طرف سے دین اسلام کی وجہ سے ہے کیوں کہ اس کے مقدسات مختلف اوربلکہ جدید ثقافت کے مقدسات کے بالکل بر خلاف ہیںبلکہ ''مارکس'' کے نظام کے مطابق چلنے والی حکومتیں اور اس کے رسم و رواج اور نئی تہذیب و تمدن کے قضاد (خلاف) کی طرف پلٹتا ہے اوردوسری طرف سے ثقافت کی حقیقت جس کو یہ دین وجود میں لایا اور اس کو پالا پوسا اور پروان چڑھایا ہے۔(۳۶)
بالٹیک کے علاقہ کی موجودہ ثقافت عیسائیت سے متاثرہے اکثراً '' کیتھولک '' عیسائی اور بعض ارتھوڈکس عیسائی ہیں۔ اور پروٹسٹان سے پرورش پاکر وجود میں آئی ہے۔ لہذا روس کی جنوبی آزاد ریاستوں پر حاکم ثقافت سے زیادہ نئی ثقافت میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ خود مختار اور آزادی خواہ جنوبی آزاد ریاستوں کے تغیرات و تحولات کی ماہیت مذہبی حقیقت کی بہ نسبت قومی اور ثقافتی حقیقت سے زیادہ مشابہ ہیں لیکن چونکہ یہ ثقافت اسلامی ثقافت ہے نہ کہ عیسائی ثقافت لہذا چند جہات کی بنا پر مرکزی بالٹیک کے علاقہ حقیقت کے جو یا رجحانات سے متفاوت اور مختلف ہے۔
جو کچھ بھی اوپر کہا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سیاسی، بین الاقوامی اور اقتصادی یا دوسرے اسباب مثال کے طور پر آزادی خواہی اور مغربی سطح کے برابر سطح زندگی لانے کی چاہت اس درمیان ان باتوں کا کوئی دخل نہیں تھا اوراگر اس کا حصہ مان بھی لیا جائے تو بہت ہی کم تھا۔ بلکہ اس معنی میں ہے کہ سب سے زیادہ اہم اور حالات کو بدلنے والے مقامات میں سے ایک مقام کو تجلی بخشنے اور یہ کہ اس کی پیدائش کے اسباب اور کیفیتں کیا ہیں اور انقلاب برپا کرکے پورے دورہ کی اصلاح کرنے کے حالات کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے شبیہ رجحانات کی پیدائش کے اسباب اور کیفیتوں کا تیسری دینا سے کیا فرق پایا جاتا ہے؟ اب اپنی اصل بحث کی طرف پلٹتے ہیں۔
گذشتہ حقائق کی تلاش
اسی ترح سے اصالت اور حقایق کی طرف قلبی جھکاؤ، حتیٰ بہتر یہ ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ ان حقایق اور اصالت کی طرف ہجوم بڑی ہی تیزی سے شروع ہوگیا تاریخ کے اس مرحلے میں یہ فکر سب سے زیادہ ترقی طلب اور سب سے زیادہ اپنے حامی رکھنے والی موجودہ معاشرتی اور سیاسی فکر تھی، لہٰذا دوسرے بہت سے لوگوں کو جو موجودہ سیاسی حکومت سے ایک طرح سے ناراض اور ہم آہنگ نہیں تھے، ان لوگوں کو اس فکر نے اپنے زیر سایہ کھینچ لیا۔ یہ بالکل اسی سبب کے تحت ہے فکر کے زیر سایہ بہت سی طاقتیں جمع ہوگئی ہیں جو عناد، بغاوت اور سرکشی کی حالت سے دوچار ہیں اور کبھی کبھی ان کے خلاف ساز شیں رچنے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ وہ معاشرے جو بڑی تیزی کے ساتھ جدت پسندی کو رواج دینے کی ہوا میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ خاندانی، تربیتی اور اخلاقی حیثیت سے فاقد ہیں اورکثرت سے پائے جا تے ہیں۔ جس وقت اقتصادی، صنعتی اورمعاشرتی تغیرات کا حجم (کسی معاشرہ میں) اس کی ہضم کرنے کی صلاحیت سے وسیع ہو جس کو سماج اور معاشرہ برداشت نہ کرپائے تو ایسی مشکلات کے جھیلنے کے لئے اس کا انتظار کرتے رہنا چاہئے۔(۳۷)
مندرجہ بالا نکتہ کی طرف توجہ دینا تیسری دنیا کی موجودہ سیاسی تحریکوں کی موجودہ حالت کو بھی صحیح سمجھنے کے واسطے اسلامی تحریکیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام موجودہ طاقتیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان مقاصد کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہوں، بلکہ وہ ان تحریکوں سے اسی لئے وابستہ ہیں کہ وہ اپنی قلبی اور باطنی خواہشات کا مناسب جواب دینے کیلئے اس راہ سے بہتر کوئی اور راہ نہیں پاتے ہیں اسی لئے کہ موجودہ حالات سے ٹکر لیناان کی ا فکار کے نقطۂ مرکزی کو تشکیل دیتا ہے، اسے تلاش نہیں کرپائے ہیں۔
اس واقعہ کے مختلف اسباب ہیں۔ لیکن وہ تمام اسباب اسلام اور اس کی استثنائی خصوصیات کی طرف پلٹتے ہیں۔ اسلام پورے موجودہ دور میں، نہ صرف ایک دین کے عنوان سے، بلکہ تہذیب و تمدن اور ثقافت کے خالق اور اسلامی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے بھی اس پرحملہ اور تجاوزکیا گیا۔ لہذا نئی اسلا می تحریک، نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کی عظمت اور تقدس کے ساتھ دوبارہ واپسی کے خواہاں ہیں ایک عقیدتی اور با عظمت نظام ہے، بلکہ اسلامی وراثتوں اور ان پراعتماد اور بھروسہ کرنے کے بھی خواہاں ہیں۔جدید تاریخی دور میں تیسری دنیا والوں کی اپنی اصالت و حقیقت اور انحصار طلبی مسلمانوں کے درمیان وراثت اور اسلامی ماہیت اور حقیقت کی طرف بازگشت کی صورت میں نمایاں ہوئی ہے۔
اسلام اپنی پوری گذشتہ تاریخ میں کبھی بھی کسی کے تحت تسلط اور دباؤ میں نہیں تھا، تاکہ وہ اپنے پیروں کو پیچھے ہٹائے اور زندگی کے فعال معاشرتی، سیاسی ا ورثقافتی میدان کو چھوڑ کر ہٹ جائے، لیکن ایسادباؤ پورے دور جدید میں عملی طور پر موجودتھا۔ یہ دباؤ نہ یہ کہ صرف جدید نہیں تھا اور ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی بلکہ اس (اسلام) کے اندرونی اور ذاتی خصوصیات کے مخالف بھی تھا۔ جیسا کہ دوسرے ادیان سے شمولیت اور پھیلاؤ کے اعتبار سے اسلام کی طرح ان کے پاس اصالت پسندی نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ بہتر طریقہ سے عصر نو کے دباؤ میں آسکتے ہیں اور اس سے ہماہنگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن دین مقدس اسلام ایسا ہرگز نہیں کرسکتا اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کرسکتا ہے۔
مغرب پرست مسلمان تجزیہ نگاروں یا وہ اہل یورپ جن کی نظر جہاں اسلام کے حوادث اور واقعات پر رہتی ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھے، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی گذشتہ صدی میں مقابلہ اور استقامت صرف ان کا خالص تعصب اور دین میں اندھی تقلید کی بنا پر تھا جو آہستہ آہستہ زمانہ کے ساتھ ساتھ نابود ہوجائیگا، وہ لوگ اسی حساب سے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ اس دین اسلام کی ذات اور اس کے اندر پائے جانے والے جوہر سے بے خبر اور غافل تھے اور یہ بھول گئے تھے کہ وہ چیز جو نئے زمانہ کے دباؤ کے ساتھ سازگار اور ہم آہنگ نہیں ہے وہ خود اسلام کا ذاتی جوہر ہے نہ یہ کہ ان (انگریزوں) کے کہنے کے مطابق اس کے ماننے والوں کو متعصب بنیاد پرست اور رجعت پسند کہا جائے۔(۳۸)
جو کچھ یہ لوگ (انگریز) اورمغرب پرست مسلمانوں کو، اتنی بڑی غلطی کی طرف کھینچ لایا، یہ اصلاح طلبی کا راستہ تھا، جس کو عیسائیت نے طے کیا اور تقریباً دوسرے تمام ادیان نے بھی کم وبیش اسی راہ کو طے کیا۔ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اسلام بھی ایک دین کے عنوان سے اسی راستہ کا انتخاب کر کے اس پر گامزن ہوجائے گا۔ مگر ایسا نہ ہوا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اسلام کی حقیقت ، عیسائیت حقیقت سے مختلف ہے اور اپنے ماننے وا لے مسلمانوں سے اسی ماہیت اور حقیقت کے لحاظ سے توقع بھی رکھتا ہے۔ ایمان کی شرط، اس دین کی کلیت اور تمامیت میں ایمان شرط ہے (اسلام) اور اہمیت کا حامل یہ تھا کہ عیسائیت کی طرح اس کلیت کو بانٹا نہیں جاسکتا۔ (یعنی تقسیم کے قابل نہیں ہے) مومنین اور زمانہ کا ہر دور میں اجماع اصول اور اس کے حدود اربعہ کی تعریف( اور اس کی حد بندی) میں، عیسائیت کی طرح، کوئی مداخلت نہیں تھی۔ اس موضوع کی اہمیت کے لحاظ سے اس کا اجمالی جائزہ لیں گے۔
اسلام، عیسا ئیت اور تمدن جدید
دین اسلام اور عیسائیت جدید تمدن سے ملاپ کے بارے میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تمدن عیسائیت کے آئین میں، پلا بڑھا اور اسی کے زیر نظر پروان چڑھا اور موجود ہوگیا ہے لہذا اس (عیسائیت) کی اس (نئے تمدن) سے ہم آہنگی اور سازگاری اسلام کی بہ نسبت کہیں زیادہ تھی اور اب بھی ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ عیسائیت ایک دین کے عنوان سے اپنے کو ان تغیرات کے ساتھ جو اس تمدن کے ترقی کرنے سے پیدا ہوئے اور نئی نئی ضرورتیں علمی، سماجیاتی،سیاسی اور ثقافتی حتیٰ اخلاقی ا ور تربیتی مختلف میدان میں پیدا کردی تھیں وہ اپنے آپ ایک طرح سے تمدن نو سے مطابقت کرسکتی تھیں اور یہ مطابقت پہلے درجہ میں خود اس دین کی ذاتی خصوصیات کی مرہون منت تھی۔(۳۹) عیسائیت کو اس کے مرکزی نقطہ سے تعبیر کیا جاتا تھا یعنی حضرت عیسیٰ ـ اور کتاب انجیل کے پیغام اور دستورات اور عہد عتیق سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا، جو بعد میں عیسائیت کے ایک جز کے عنوان سے قانونی طور پر پہچانا جانے لگا،اور اس کے کچھ ضمنی حصے جو کلیسا کے پادری (روحانی) اور اہل کلیسا کے ذریعہ تدوین کئے گئے تھے، اس میں اضافہ کردیا گیا تھا تاکہ عیسائیت کو ایک ایسے جامع وکامل دین میں تبدیلی کر دے جو کہ قرون وسطیٰ میں مؤمنین، تمام مادی، معنوی و ذاتی اور معاشرتی امور پر مشتمل تھی۔
قرون وسطیٰ میں یورپ پر عیسائیت اسی طرح حاکم تھی جس طرح اسلام اس دور کے مسلمانوں پر حاکم تھا۔ یہ دونوں دین یکساں طور پر اپنے ماننے والوں کی تمام مختلف جہات سے فردی اور اجتماعی زندگی میں ضرورتیں پورا کرتے اورفعالانہ طور پر حاضر رہتے تھے، اس فرق (تفاوت) کے ساتھ کہ اسلام کی تمامیت ذات خود اسی سے وجود میں آئی تھی، یعنی قرآن و سنت سے پیدا ہوئی تھی اور صرف اس زمانہ کی عیسائیت کی حقیقت بعض ابتدائی کے ایک حصہ کی طرف پلٹتی تھی۔ حقیقت میں یہ کلیسا کے پادری ا ور معنوی روحانیوں (پادریوں) اور کلیسا والوں کا اجماع ہی تھا جو عیسائیت کے خلاء اور کم و کاست کی تلافی کیا کرتا تھا تاکہ ایک جامع اور کامل دین میں تبدیل ہوجائے۔
یہ فطری بات ہے کہ یہ دونوں دین اس دباؤ کے مقابلہ میں جو ان کے مقابلہ کے لئے اٹھتا تھا ان کے عقب نشینی اور اس کی واپسی کا خواستگار تھا، دو مختلف کیفیتوں کا عکس العمل ظاہر کریں، ایک جگہ پر خود یہی دین تھا جو اس کے اصول و قوانین اور بنیادوں اور اس کے حدود اربعہ کو بیان اور معین کرتا تھا اور دوسری جگہ پر اس (دینی) مجموعہ کے کچھ حصے شارع مقدس کے ذریعہ نہیں بلکہ بعض دوسروں کے ذریعہ اگرچہ وہ لوگ بھی مقدس اور معتبر تھے مگر وہ لوگ ہرگز شارع مقدس کے ہم پلہ اہمیت حاصل نہیں کرسکتے تھے، ان کے ذریعہ اس دینی مجموعہ کی توضیح اور تعیین کی جاتی تھی۔اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی رائے کا اعتبار اور ان کا حجت ہونا بھی جن کو خود دین سے حاصل کر نا چاہئیے نہ کہ مومنین کے اجماع اور اتفاق سے ۔ یہ اہل کلیسا کا اتفاق اور اجماع تھا جس نے قدیسین اور کلیسا کے روحانیوں اور پادریوں کو اس مقام و منزلت پر لاکر کھڑا کردیا تھا کہ ان کے نظریات اور آرا کو دین کے برا بر اور قانون کا درجہ دیکر اس کا ایک حصہ سمجھ لیا جا ئے ۔
عملی طور پر بھی یہ دونوں (دین) جدید تمدن کے مقابلہ میں حقیقی طور پر اس کے رقیب بلکہ اس کے مخالف محسوب ہوتے تھے، دو طرح سے رد عمل کا اظہار کیا۔ عیسائیت نے ایک طویل عرصہ تک اس کا مقابلہ کیا مگر یہ مقابلہ فطری طور پر تاریخی بہاؤ کے رخ کا مخالف تھا اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں تھا آخر کار یہ استقامت اور مقابلہ شکست کھا گیا۔اس مقابلہ کے دوام نہ پانے اور اس کے بکھرجانے کے بہت سے وجوہات ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبھہ نہیں کہ اس کی اہم ترین نقصان اور ضرر قبول کرنے والی خصوصیت خود اسی سے متعلق ہوتی تھی۔ اسی خصوصیت نے لوٹر اور کالون اور دوسرے تمام پروٹسٹا نیزم ( Protestant ) کے بانیوں کی پرورش کی اور ان کو میدان میں لے آئی۔ وہ لوگ جنھوں نے دوسری تعبیر کی وہ تمام سختیوں اور موانع کے باوجود نفوذ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔
کیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے کہ جو لوگ خالص اور حقیقی ابتدائی عیسائیت کی طرف رجوع کرنے کے مدعی تھے، وہ لوگ عیسائیت کو ہر اس چیز سے سنوارنے کی فکر میں لگ گئے جس کا آہستہ آہستہ کلیسااور اہل کلیسا کے ذریعہ بڑھاوا دیا گیاتھا۔ انہوں نے اس فکر و خیال کے ساتھ میدان میں قدم رکھا اور ایسی فکر کو آگے بڑھانے کے لئے حالات بھی مناسب اور سازگار تھے۔ لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ یہ نظریہ پھیلا اور تمام رکاوٹوں کو بالکل صفح ھستی سے ختم کر دیا۔ ایسا حادثہ کسی اسلامی مملکت میں وجود میں نہیں آسکتا تھا جو بعد میں اپنے آپ کو وسعت دے۔
اگرچہ اسلام میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس آخری صدی کے دوران عیسائی ( Protastant ) مذہب کی پروٹسٹان شاخ کی پیروی کرتے ہوئے اٹھے یا اس کی طرف توجہ دئیے بغیر،کم و بیش ایسے مقاصد کی پیروی کرتے تھے۔ لیکن یا یہ لوگ شروع ہی سے شکست کھا گئے اور یا یہ کہ نتیجةً اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔(۴۰) جیسا کہ ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ اس کا اصلی سبب یہ تھا کہ یہ دو دین دو مختلف ماہیت اور حقیقت کے حامل ہیں۔ مذہبی اصلاح کے معنی یہ ہیں کہ بعض مذہبی اعتقادات کو ترک کردیا جائے اور بلکہ عیسائیت کے معیار پر عیسائیت میںیہ اتفاق رونما ہو سکتا ہے اور اسلام میں اس اتفاق کے رونما ہونے کا امکان بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ ایک عیسائی ہو سکتا ہے کہ معتقد اور مومن بھی ہو وہ اور اضافات کو اس اعتبارسے کہ یہ اضافات شارع واقعی سے متعلق نہیں ہے لہٰذا اس کو ایک کونے میں ڈال دے (یہ اصل شریعت عیسیٰ میں نہیں ہے) یہ چیز اس کے ایمان و اخلاص کے مخالف اور منافی نہیں تھی لیکن ایک مومن اور معتقد مسلمان ایسا ہرگز نہیں کرسکتا۔ کیونکہ جس چیز پر وہ ایمان و عقیدہ رکھتا اور اس پر پابند تھا وہ تمام چیزیں اسلام کی طرف سے تھیں نہ یہ کہ وہ علمائے اسلام کی طرف سے آئیں کہ جن پر انہوںنے اتفاق کرلیا تھا۔
البتہ اسلام میں بھی دوسرے آئین مذاہب اور مکتب فکر کی طرح پوری تاریخ میں خود ساختہ بہت زیادہ اضافے پائے جاتے تھے اور اس کے بہت سے قواعد اور قوانین اور مفاہیم جس کو خود اسلام نے بیان کیا تھا، اس کے خلاف بہت سی رنگ برنگ تفسیریں دیکھنے کو ملتی اور رائج تھیں۔بہت سے لوگوں نے قیام کیا تاکہ ان اضافات کو آہستہ آہستہ ختم کردیں ان غیر صحیح تفسیروں کی اصلاح کریں اور اس کو حقیقت کے مطابق پہچنوائیں۔ لیکن یہ اصلاحات ان اصلاحات کے بر خلاف ہیں جو عیسائیت یا دوسرے ادیان میں پائی جاتی ہیں اور جدید تمدن اور تاریخ کی درخواست کے عین مطابق قرار پائی ہیں۔ یہ تمدن اس سے زیادہ کہ ان ادیان میں اصلاح اور اس کے بنانے اور سنوارنے کا ان کے آخری معنی میں طلبگار ہو، (ادیان) کی تقسیم اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے اور ان کی عقب نشینی اور ان کو پیچھے ڈال دینے کے خواہاں تھے۔ تمدن نو چاہتا تھا کہ دین اپنے تمام معاشرتی مسائل کو یکسر پس پشت ڈال دے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کردے۔ اس (تمدن جدید) کا مقصد یہ تھا عیسائیت اور دوسرے ادیان بھی ان کو تعمیری اور مثبت جواب دے سکتے تھے۔ لیکن اسلام سے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ اور اصلاح طلب مسلمان جو اپنے ایسے اہداف تک پہنچنے کے لئے وہ اپنے خیال خام میں اصلاح کے لئے سبقت کی یا اصلاح کے لئے اقدام کیا تھا ،جلدی یا کچھ دیر میں اسے شکست اٹھانی پڑی۔ اصالت پسندی کی موجودہ تحریک اصلاح طلبی کی تحریکوں اور ان کے افکار، خود یہ ان کی شکست پر بہترین دلیل ہیں اصلاح طلبی کی تحریکیں ہی ہیں جو ایسے افکار اور اہداف کی مالک ہیں،ان کی شکست سیاسی دلائل سے زیادہ اعتقادی دلیلوں کی حامل تھی یعنی ان کی شکست کا واحد سبب مذہبی اور اعتقادی معیار تھے۔(۴۱)
البتہ اسلام اور عیسائیت کا تفاوت اور ان دونوں کا جدید تمدن سے مقابلہ، صرف اسی نکتہ پر ختم نہیں ہوتا ہے عیسائیت ''لوٹر پذیر'' ہے اور اسلام ''لوٹر پذیر'' نہیں ہے یا عیسائیت کے پروٹسٹان کے ایسا گروہ عیسائیت میں تغیر اور انقلاب پیدا کرکے کامیاب ہوسکتا ہے لیکن اسلام میں ایسا بدلاؤ ہرگز پیدا نہیں ہوسکتا۔ عیسائیت کی اصلی شاخ اور حقیقت پسند جدید تمدن اسلام کے برتاؤ کے مقابلہ میں مخالف ٹکراؤ کا حامل ہے یہ بھی ان دونوں کی حقیقت اور اس کے اندرونی ڈھانچہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور یہ اسلام کا جامع اور کامل ہونا اور اس کے دستورات اور احکام کے کامل نفاذاور یہ کہ اخروی کامیابی حتی ہم مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ دنیاوی عزت بھی ایسے کامل دستاویز پر کی مرہون منت ہے، دوسرے ادیان کے بر خلاف یا کم از کم ان کی موجودہ تفسیر کے خلاف، یہ بات بڑھتے ہوئے او رنئی تاریخ کو ذلیل و خوار کردینے والے دباؤ کے مقابل اس دین کی اصالت کا محافظ ہے۔
جانسن) ( Johnston نے اس بات کی دوسر ے زاویہ نگاہ سے اس طرح توضیح دی ہے: ''آج اسلام اور مغربی دنیا باہم ایک دوسرے کے خلاف صف آرائی کئے ہوئے ہیں اس طرح کہ وہ لوگ مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے کہ کسی بھی بڑے دین میں ایسی صف آرائی نہیں ہوئی ہے نہ عیسائیت میںکہ وہ خود مغربی دنیا کا ایک حصہ ہے اور جدت پسندی کے ذریعہ وہ اسی میںضم ہو گیا ہے، ہندوایزم کو اور بودھ ایزم کے طریقہ پر تحلیل و تجزیہ نہیں کیا ہے کیوں کہ ان کی گہرائی میں صرف روحانیت پائی جاتی ہے اور روح کی نجات و فلاح کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے اور نہ ہی یہودیت کہ ایک بہت چھوٹا سا آئین و مذہب اور ایک قوم و ملت میں محدود ہے۔ اور ان ادیان کے مذہبی رہنماؤں میں سے کسی رہنما کا وہ اثر نہیں ہے جتنا کسی خلیفہ، مہدی اور آیت ا...کا اثر مغربی دنیا پر ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام نے ڈیڑھ ہزار سال کے عرصہ میں مغرب کے ساتھ نظامی (فوجی) مقابلہ بنائے رکھا اور دور حاضر حالت میں بھی وہی جنگی صورت حال اور ٹکراؤ کا سلسلہ باقی ہے۔''(۴۲)
اگرچہ اس کی تحقیق اور چھان بین اور اس کی تفسیر اسلام اور مغرب کے مسلحانہ اور سیاسی ٹکراؤ پر ناظر ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ ٹکراؤ اسلام کی دینی حیثیت سے ہے جو اپنے حقائق اور اصالت پر زوردیتا ہے اس جدید تمدن کے مقابلہ میں جو درمیانی رویہ اختیار کرنے کا خواہاں، بلکہ اس کے پیچھے ہٹنے کا خواہاں ہے۔
دو با رہ پلٹنا
لہٰذا اس دین کی ذاتی خصوصیات کی طرف توجہ کرتے ہوئے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس دین نے ایک مدت کے لئے اس جدید تاریخی میدان کو ترک کردیا، (اور گوشہ نشینی اختیار کرلی) مگر ایسا نہیں ہے کہ آج کل متحرک اور فعالانہ طور پر میدان میں قدم رکھ دیا ہے؟ جو کچھ آج ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کے اندرونی خصوصیات کے ساتھ با ہمی توافق اور آپسی سازگاری ہے اور اس سے پہلے جن چیزوں کو دیکھتے تھے، وہ ایک عارضی اور ناپائیدارحادثہ تھا۔خصوصاًیہ کہ کوئی بھی دین اس دین کے برابر اس طرح سے کہ ہر طرف سے معاشرہ اور تاریخ میں اس قدر عمیق رسائی نہیں رکھتا ہے اور اپنا اثر نہیں ڈالتا ہے اور اس حد تک کہ اپنے پیروؤں کو اپنے مقصد کے حصول کے لئے اکٹھا کرنے اور اپنے مقاصد کو وجود بخش نے پر قادر نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کا خاصہ مغرب سے پیکار اور بلکہ اپنے غیر سے آمادہ پیکار رہنا دین اسلام میں دوسرے ادیان سے زیادہ عمیق اور قاطع ہے۔(۴۳)
حقیقت میںموجودہ اسلامی تحریک جدید تمدن کے پوری دنیا پر چھاجانے کے مقابلہ میں اس دین کی استقامت کا ایک نمونہ ہے۔ اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ اس کو اسلامی دنیا میں چھاجانے سے روکنا ہے جو خود اس سے متعلق ہے اور یہ ایک فطری امر ہے۔ ایسے جریان کا فقدان غیر فطری امر اور سوال طلب ہے؟، نہ یہ کہ اس کا وجود سوال طلب ہو اگر دوسرے ادیان اور ثقافتیں ایسی تحریک کی حامل نہیں تھیں، یا کم از کم اگر ایسی ہوں بھی تو وہ اتنی گہرائی اور شدت کی حامل نہیں تھیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر جدید تمدن کے دنیا پر چھاجانے کے مخالف نہیں تھے۔ یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنی حکومت اورسرزمین کے واسطے ایسے مقدسات اور معیار جو اس کو واجب اور لازم جانیں ان کے پاس نہیں ہیں اور یا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اس بات پر قادر تھے کہ اپنے معیار کو ان کے معیاروں اور مقدسات کو تمدن جدید اور اہم موجودہ نظام کے ساتھ ہماہنگ اور موافق بناسکیں۔(۴۴)
البتہ، اس بات کا اضافہ کرناچاہیے کہ اسلامی معاشرہ میں اس آخری صدی میں رونما ہونے والے انقلابات اس طرح تھے کہ اس استقامت اور ٹکراؤ کے لئے ضروری مادی طاقت کو فراہم کرلیا ہے۔ اس زمانہ کے حوادث اور واقعات اور پے در پے مسلمانوں کو جدید تمدن کے ذریعہ دھچکے لگے ہیں،اس سے ان کے افکار، اعتقاد ات اور ان کی شخصیت کی کچھ اس طرح پرورش کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی اور عظیم تحریک کی خدمت کے لئے آمادہ کرلیں۔
اس بات کا پتہ لگانے کے لئے اس کا بہترین نمونہ اس آخری دوران میں اسلامی فکر کی تحقیق اور اس کی چھان بین ہے جس سے مسلمان ابتدائی دہائیوں میں اسلام اور جدید تمدن کے مقابلہ اس طرح مرعوب ہوگئے تھے کہ وہ اپنے دین کے دفاع کے سلسلہ میں اس کے سوا کہ اسلام کو تمدن نو کے برابر ثابت کریں کچھ اور سوچ ہی نہیں رہے تھے وہ لوگ معذرت خواہی کے جواب کے ذریعہ اپنے زعم ناقص میں اس شباہت اور برابری کو ثابت کر نا چاہتے تھے ۔ بعد میں آنے والی نسل خود اپنے او پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے اعتقادات کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے میں لگ گئی۔ اس نسل کا ہدف اپنے اسلاف کی طرح اسلام کو جدید تمدن کے معیار کے مطابق اس کے مانند اور برابر ثابت کرنا نہیں تھا۔ بلکہ نسل جدید کا مقصد (ہدف) یہ تھا کہ ان کو اس کی مستقل طور پر توضیح دیں۔ آج کل کی نسل کا علم وفہم اور بیان قاعدةً (اصولی طور پر) دوسری طرح اور جداگانہ ہے اور وہ اپنے دین کی پورے طور پر حاکمیت اورچاہتوں کی تکمیل کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے اور یہ نسل اس سے کم پر قانع اور مطمئن ہونے والی نہیں ہے، اس نسل کی نظر میں صرف اسلام ہی حق وباطل کا معیار ہے اور یہ دوسرے (تمدن) ہیں جن کا مقایسہ اسلامی معیار پر کیا جائے نہ یہ کہ اسلام کا قیاس دوسروں سے (یعنی اسلام کا قیاس دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں کے ساتھ نہ کیا جائے چونکہ اس سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔)(۴۵)
یہ تغیر اور تبدیلی خود اس بات کی حکایت کرتی ہے کہ مسلمانوں میں دینی رجحانات کی شناخت اور ذہنی تبدیلی پیدا ہوگئی ہے خصوصاً جوانوں اور مسلم طلبا( Muslim Students ) کی فکر میں انقلاب آیا ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام تغیرات اور تبدیلیاں ایک ساتھ تمام اسلامی ممالک میں فکری اور اعتقادی انقلاب کا آجانا بلکہ اسلامی ممالک میں معاشرتی، اقتصادی اور معیشتی ، معاشرتی اور سیاسی تغیرات کے ساتھ ساتھ یہ بدلاؤ پیدا ہوگئے ہیں۔ لہٰذا بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے کو قوی اور مضبوط بنانے میں حصہ لیا۔ یہاں تک کہ ۷۰ ء کی دہائی کے آخر میں اوج کی آخری منزل تک پہونچ گیا اور لوگوں میں نئے حالات ا ورحوادث کو وجود بخشا جس کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ تحریک (اس دور جدید کی) سیاسی،( دینی اورمعاشرتی) اور دور جدید کی ثقافتی نشانی اور علامت ہے کہ اس (تحریک) نے دنیا کے تمام غیر صنعتی ممالک بجز جنوبی امریکہ کے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ عموماً دور جدید اپنے پہلے والے دورہ کا نتیجہ ہے۔ یعنی ایک ایسا دور جو اپنے زرق وبرق و قدرت اور جدید تمدن کی تکنیک ( Technology ) نے یوروپ کے علاوہ دوسرے علاقوں کے تمدنوں کو اپنے رعب و داب اور دھمکی میںلیکر، وحشت پھیلائی اور دوسرے تمدنوں کو پردہ ٔ خفا میںڈال دیا ۔(یعنی دوسرے تمدن بے اہمیت ہوگئے تھے۔)
اور خود نے چومکھا غلبہ کرکے اس پر اپنا قبضہ جمالیا۔ نئی حالت جو نئے تمدن کے غلبہ کے ہمراہ تھا، یہ زیادہ تر عارضی اور ناپائدار تھا یہاں تک کہ فطری طور پر اس ناپائیداری میں استحکام بنا رہا اس طرح، لحاظ کیا جاتا تھا کہ بغیر کسی سبب اور علت کے قدیمی میراث کو فراموشی کے سپرد کردیا تھا اور اس قدیم تہذیب و تمدن کی اولاد اور اس کے وارثوں کو بھی سکوت وخاموشی پر مجبور کردیا تھا۔
یہ فراموشی جو اکثر ذلت و رسوائی کے ہمراہ تھی، ایک طولانی مدت تک باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن اس زمانہ کو ختم ہونے کے لئے بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ مقدمات کو فراہم کیا جائے۔ کچھ مقدمات اور حالات آخری صدی میں پیدا ہو گئے، آخری دو تین دہائیوں میں اپنے مقام و منزلت اور بلندی کو پالیا اور تیسری دنیا کو تاریخ کے ایک نئے دور میں لاکر کھڑا کردیا۔ اس نئے تاریخی دور نے دنیائے اسلام کو بھی شد ت اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ نیا دور کن اسباب و عوامل اور طاقتوں کے زیر اثر ہے اور اس کے اچھے اور برے پہلو کیا ہیں؟ اور وہ اپنی پائیداری اور خلاقیت اور سربلندی کی کس حد تک حفاظت کرسکتا ہے ؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر جدید دور کی حقیقت طلبی کا عقیدہ اور نظریہ کہ یہ دور خود کسی نہ کسی طریقہ سے اس دور کی مخلوق ہے، تیسری دنیا خصوصاً اسلامی دنیا کی مختلف ضرورتوں کا جواب دہ ہو، ایک طرح سے اصالت اور تجدد پسندی اور اس کی طرف میلان اور تبدیلی کی خواہش، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر فدا نہ ہوں تو ایسی صورت میں اطمینان کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نظری اعتقاد ( Idiology ) میدا ن کارزار میں کامیاب ہوجائے گا۔ اصالت سے وابستگی آج کی بہت زیادہ اور مختلف ضرورتوں کو نظر انداز کرکے اس پرشتاب اور آئے دن تبدیلی کی شاہد دنیا، تنہا اس کامیابی کی ضامن نہیں ہوسکتی (یعنی کامیابی نصیب نہ ہوسکے گی) اور یہ بات ہمارے زمانے میں یعنی ۸۰ء کی دہائی اور اس کے بعد آنے والی دہائی میں گذشتہ تاریخ کے تمام زمانوں سے زیادہ صحیح ہے۔ اس کی طرف توجہ دینا نہ صرف یہ کہ اس معرکہ میں حقیقت طلبی جس کی بنیاد ڈالی جاچکی ہے نظری اعتقاد کی کامیابی کی ضامن ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور کی پائیداری اور اس کا ہمیشہ باقی رہنا کامیابی اور کامرانی بھی اسی کی مرہون منت ہے۔ اس نظری عقائد ( Idiology ) کی شکست اور اس دور جدید کی ضروریات واحتیاجات کے پورا کرنے کی توانائی نہ رکھنا، تقریباً اس دور کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ ختم ہوجائے گی۔(۴۶)
اس مقام پر بہتر یہ ہے کہ کتاب کے آئندہ حصہ میں جس حصہ کے بارے میں بحث کی جائے گی اس کی طرف اشارہ کریں۔ شیعہ حضرات اور اہل سنت کی سیاسی فکر کی تحقیق اور اس کی چھان بین کے لئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصولاً( قاعدتاً)ان دو مذہبوں کی حقیقت کیا ہے اور ان دونوں کے خصوصیات اور اختلافات کیا ہیں؟
عقید تی اختلا فات کی جڑیں (بنیادیں)
اس موقع پر بنیادی مشکل یہ ہے کہ ان دو مذہبوں کے تفاوت اور اختلاف کا مرکز صرف حضرت علیـ کی خلافت کو بنایا جاتا ہے۔ مسئلہ اور مشکل یہ نہیں ہے کہ حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بلا فصل وصی ہیں یا کہ چوتھے خلیفہ۔ ان دونوں کے اختلاف کا خلاصہ اسی مقام پر نہیں ہوتا ہے۔
بنیادی طور پر بحث کا مرکز ذات اورشخصیت نہیں ہے اور یہ کہ وہ کون ہے۔ بحث کا مرکز شان اور اس کا مقام و منزلت ہے۔ اور وہ یہ کہ وہ (شان) مقام و منزلت کیا ہیں؟ اور کون شخص اور کون کون اشخاص اس شان و شوکت اور مقام کے حامل ہیں؟دوسرے لفظوں میں یہ کہ بحث مصادیق سے زیادہ مفاہیم پر مبنی ہے۔ شروع میں بحث اس بارے میں ہے کہ امامت کا مفہوم کیا ہے؟نہ یہ کہ امام کون ہے؟ اگر اس مسئلہ پر ایک تاریخی مسئلہ کی حیثیت سے نظر کریں تو یہ ایک (بہت بڑی) غلطی محسوب ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مفہوم(امامت) اہل سنت وتشیع کے تمام مختلف زاویہ نگاہ اور دینی افکار کے حدود اربعہ کو متاثر کرتا ہے۔
اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ کہا جائے۔ شیعوں کا اعتقادی، فقہی اورکلامی ڈھانچہ اور اس کے بعد، تاریخی تجربہ، اہل سنت وتشیع کا نفسیاتی اور معاشرتی ڈھانچہ اور اہل سنت دو طرح کے مختلف اسباب سے متاثر ہوکر وجود میں آئے اور پروان چڑھے۔ اس اختلاف (تفاوت) کا اصلی سبب یہ ہے کہ اہل سنت اسلام کو (ماورائے اسلام) خلفائے راشدین وصحابہ اورتابعین کے زمانے میں اسلام کے وجود کے بارے میں صوری خیال کرتے ہیں اور پھر اسلام کو اسی زاویۂ نظر سے دیکھ کر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ لیکن شیعہ حضرات اس کو جانشینی کے سلسلہ میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی تاکیداور سفارش اور فرمان کے مطابق اسلام کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ ایک (فرقہ) اسلام کو صدر اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھتا ہے اور دوسرا (فرقہ) صدر اول کی تاریخ کو اسلامی معیاروں اور قواعد و ضوابط کے اعتبار سے جائزہ لیتاہے۔ ایک جگہ دین کو صدر اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے اور دوسری جگہ تاریخ کو دین سے ہٹ کر پرکھا جاتا ہے۔یہ دو نوں کاملاً، مختلف زاویہ نگاہ کے حامل ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شیعہ وسنی کے اصلی اختلافات اور ان دونوں کے اہم امتیازات اور شناخت دو کلامی اورفقہی مکتب کے اعتبار سے یہ اختلافات وجود میں آئے ہیں۔(۴۷)
جس وقت صدر اسلام کی تاریخ، خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے زمانہ کی اہمیت و عظمت و منزلت خود اسلام کے ہم پلہ ہوجائے، تو یقینا یہ اسلام دوسرے گروہ کے اسلام سے مختلف ہوگا جو گروہ نہ فقط اس تاریخ کی اہمیت ومنزلت کامعتقد نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت کا قائل ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنجیدگی کا حامل ہے کہ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کا اختلاف، اسلام کو سمجھنے میں دو مختلف معیار کی بنا پر ہے ۔
ایک جگہ امامت و خلافت وامام وخلیفہ کو ایک زاویہ سے سمجھا جاتا ہیاور دوسرے مقام پر (گروہ میں) دوسری طرح سے درک کیا جاتاہے۔ دوسری طرف شان وخصوصیات پیغمبر کی قدر و منزلت اور بعد میں آنے والے خلیفہ (امام) کی خصوصیات کو گھٹاکر برابر کردیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پر امام کی خصوصیات اور اس کے مقام و منزلت کو پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم تک بڑھا دیا جاتا ہے(البتہ یہ فطری بات ہے کہ وحی اور نبوت کے علاوہ) ان دو نظریات کے پیش نظر بہت سے مسائل وجود میں آتے ہیں کہ جن کا ظہور میں عموماً سیاسی افکار ہی میں ہوتا ہے ۔دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ان دونوں فرقوں کے سیاسی افکار اسلام کے بارے میں تمام دوسری بحثوں سے زیادہ ان کے فہم و ادراک اور مختلف زاویہ نگاہ سے متاثر ہو نے کی وجہ سے ہے۔
یہاں پر ایک بات یاد دلانا ضروری ہے کہ اس طرح کی بحثوں کے پیش کرنے سے غلط فہمی پیدا نہ ہوجائے مثال کے طور پر اگر ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں پھر وحدت اسلامی کے کیا معانی ہوسکتے ہیں ؟ یا یہ کہ وحدت اصل ہے یعنی اساسی حیثیت کی حامل ہے۔ لہٰذا ان بحثوں کا یہاں پر چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔اوّلاً ان تمام اختلافات کے باوجود ان دو فرقوں کے درمیان وسیع اور مسلم معیار جن میں شک و شبھہ نا ممکن ہے، ان کی برکت سے اور دوسرے عام اسلامی فرقوں سے بھی اس قدر مشترک بنیادی مسائل پائے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہ دین یعنی اسلام نے اس طرح باہم ملنے جلنے اور آپس میں اتحاد کے بارے میں شرعی ذمہ داری کے عنوان سے اس کی بہت زیادہ تاکید کی اور حکم دیا ہے۔ لہٰذا اصولی طور پر یہ مطالب ہماری بحث سے جدا ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان دو مذاہب کی گذشتہ تاریخ کے صحیح اور تجزیاتی درک و فہم اور ان دونوں کی موجودہ حالت کی صحیح چھان بین کے لئے لازم ہے کہ ان دونوں کی بہ غور شناخت کی جائے اور ان کے مختلف اجزا و عوامل کو ان لوگوں کی سیاسی فکر کو وجود میں لانے اور اس کو بال و پر عطا کرنے کے بارے میں جائزہ لیا جائے۔ جو کچھ کہا جا چکا ہے اور بعد میں کہا جائے گاوہ اس امر سے متعلق ہوگا اور اس مقصد کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔
پہلی فصل کے حوالے
(۱)مثال کے طورپر اس مقام پر عیسائیت کے اقدامات کے بارے میں رجوع کریں:
Vatican Counil ۲nd The Conciliar and Post Conciliar Documents,PP.۹۰۳-۹۱۱
(۲)اس سے زیادہ وضاحت کے لئے دیکھئے العقیدة و الشریعة فی الاسلام ص۲۵۰۔ ۲۶۰ اور البدعة: تحدیدہا و الموقف الاسلام منہا،نامی کتاب میں بھی رجوع کریں۔
(۳)اس سے زیادہ وضاحت کے لئے تیسری اور چوتھی فصل میں دیکھئے۔
(۴)برائے نمونہ، رجوع کریں۔
. Asaf Hussain,Islamic Movements in Egypt, Pakistan and Iran
(۵)اس بحث کے واضح ہونے کے لئے لازم ہے کہ معاشرہ اور تاریخ پر اسلام کی تاثیر کی کیفیت کو معاشرہ اور تاریخ پر معاشرتی اور تاریخی تغیرات کے پیدا ہونے میں اس کا کردار کیا ہے، ایک دین کی حیثیت سے دین اسلام کی دوسری خصوصیات کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ اس بارے میں کتاب ایدئولوژی و انقلاب، نامی کتاب کے ص۱۱۱۔ ۱۴۹، و نیز الفکر السیاسی الشیعی، کے ص۳۷۔ ۱۱۵ اور العقیدة و الشریعة فی الاسلام کے ص۱۳۳۔ ۱۷۷ پر بھی رجوع کریں۔
(۶)شیعہ اور سنی کے نظریاتی اختلاف کی روشنی میں مؤثر اختلاف کو حاصل کرنے کے لئے اس طولانی مدت میں شیعہ اور سنی معاشرہ پر موجودہ زمانے کی پوری مدت میں کیا اثر ڈالا ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کریں۔ Faith and Power PP.۳۱-۵۵ الفکر السیاسی الشیعی نامی کتاب کے ص۳۷۔ ۱۸۰، کتاب کے آخر میں بہترین اور قابل اعتنا مصادر (منابع) اس بارے میں پائے جاتے ہیں۔
(۷)بہترین مآ خذ میں سے ایک ماخذ جس پر توجہ کرکے بخوبی شیعہ و سنی کے دینی اور فکری، رجحانات کے ڈھانچہ میں فرق کوجانا جاسکتا ہے اور اسی طرح شیعہ حضرات اور اہل سنت کی عاطفی اور جذبات پر مبنی حساسیت کو بھی اور ان کے سوچنے کی کیفیت اور ان کی تاریخ پر نظر کو اور خصوصاً صدر اسلام کی تاریخ کو حاصل کیا جاسکتا ہے، کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں (جن سے یہ چیز اچھی طرح معلوم ہوسکتی ہے) جو ان سنیوں نے لکھی ہیں جو سنی سے شیعہ ہوگئے ہیں ان کتابوں میں اس سے بحث کی گئی ہے۔ نمونہ کے طورپر آپ محاکمہ تاریخ آل محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم مؤلفۂ قاضی بہجت آفندی، لماذا اخترت مذہب الشیعہمؤلفۂامین الانطاکی اور خصوصاً اس طرح کی آخری کتاب جس کو تونس کے روشن فکر سنی عالم جو بعد میں شیعہ ہوگئے، انہوں نے ثم اہتدیت کے عنوان پر لکھی ہے مؤلفۂ محمد تیجانی السماوی ۔ اسی طرح نظریة الامامة الشیعة الامامیةنامی کتاب کی طرف بھی رجوع کریں (مولف) احمد محمود صبحی، ص۱۵۔ ۶۸
(۸)الشیعة والحاکمون، ص۲۶۔۲۷؛
(۹)الفکر السیاسی الشیعی، ص۶۴۔ ۶۵
(۱۰)اس بات کو عبد الکریم الخطیب نے اپنی کتاب سد باب الاجتہاد و ما ترتب علیہ میں اچھی طرح توضیح دی ہے۔خصوصاً اس کے ص۳۔ ۸ پر رجوع کیجئے۔
(۱۱)حقیقت یہ ہے کہ علما اہل تشیع و تسنن اعتقادی، تاریخی، فکری اور معاشرتی اعتبار سے دو طرح کے حالات سے متاثر ہوکر وجود میں آئے ہیں اور ترقی حاصل کی ہے اور یہ بات خصوصاً آخری صدیوں میں اور خاص طورپر موجودہ زمانے میں زیادہ صحیح ہے۔ شیعہ مذہب میں علما اور روحانیت کو ایک مستقل حیثیت حاصل ہے۔ جیساکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مشکل تنہا یہ نہیں ہے کہ یہ معاشرہ اور ادارہ اقتصادی اور تشکیلاتی طورپر مستقل اور کسی سے وابستہ نہیں ہے۔ زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ یہ ادارہ عوام الناس اور حکومت دونوں کی طرف سے قانونی طورپر ایک مستقل حیثیت حامل ہے اور خود (علما) بھی اس بارے میں راسخ یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح شیعہ معاشرہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، یا کم از کم ایرانی معاشرہ، اس طرح ہے کہ وہ اس سے بے توجہی اور بے اعتنائی نہیں کرسکتا ہے۔
ایرانی معاشرہ کم از کم قاچاری نظام کے زمانہ کے بعد سے خصوصاً ان مواقع پر جو عوام سے متعلق ہیں اس طرح وجود میں آیا ہے گویا وہ ہمیشہ اس ادارہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے ضرورت مند اور محتاج ہے۔ اس حد تک کہ اس مقام پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اس سے قبل کہ یہ ادارہ (علما) عوام الناس کا ضرورت مند ہو یہ عوام ہیں جو مختلف اسباب کی بناپر اس (ا تحاداور کمیٹی) کے محتاج رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ کہا جائے کہ علما کا گروہ حقیقت میں ہمارے عوام کی مادی، دینی، نفسیاتی اور روحی مشکلات کو برطرف کر نے والا ہے تو کوئی مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ بہت سی اندرونی اور بیرونی مشکلات کے باوجود اب تک یہ چیز باقی ہے۔ یہ صنف کم سے کم گذشتہ دو تین صدیوں کے درمیان لوگوں کی قلبی (عاطفی) اور اخلاقی بہت بڑی تکیہ گاہ رہی ہے۔ وہ لوگ (عوام الناس) نہ صرف یہ کہ اس کے خواہش مند تھے کہ وہ اپنی ذاتی اور فردی زندگی کی مشکلات میں ان (علما) کی طرف رجوع کر یں اور اپنی مشکلات اور مصیبتوں کو حل کرنے کے لئے ان سے امداد کی درخواست کرتے تھے۔
ان باتوں (نکات) کا کامل جائزہ میں طوالت کا باعث ہے۔ لیکن اس مقام پر مسئلہ شیعوں کی روحانیت اور مرجعیت کی طرف پلٹتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ان اسباب اور تجربیات میں سے کوئی بھی مسئلہ اہل سنت کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے اور شاید اس کا وجود میں آنا ممکن بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے اعتقادی معیار جدا اور ان کا فردی، معاشرتی اور تاریخی تجربہ اور ہے۔ ان کے نزدیک ایک عالم کی حیثیت اسلامی اور فقہی مسائل کے ماہر سے زیادہ نہیں ہے جس طرح معاشرہ میں مختلف مشغلے اور پیشے پائے جاتے ہیں اور ہر ایک شخص کسی نہ کسی چیز میں مشغول ہے، علما بھی امامت جمعہ و جماعت اور دینی و فقہی مسائل کے مطالعہ میں مشغول ہیں اور ان مواقع پر ان کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔
افسوس کا مقام ہے کہ آخری زمانہ کے بدلاؤ اور تعلیمی نظام کی اصلاح نے ان لوگوں کو زیادہ قانونی، سرکاری اورمغرب پرست بنادیا ہے اور اس کے نتیجہ میں وہ لوگ عوام الناس سے بہت دور ہوگئے ہیں۔ شیخ کشک مشہور ترین اور عربی عوام کا محبوب ترین خطیب نے اپنے ایک خطبہ کے ضمن میں ۱۹اپریل ۱۹۸۱ئ کو علمائے ''ازہر'' اور تمام علمائے دین کو خطاب کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا (للکارا) ۱۹۶۱ئ میں ''اصلاح'' کے نام سے ایک ضربہ ''جامعۂ الازہر'' کو پہنچایا گیا کہ جس نے واقعاً اس (جامعہ ازہر) کو نابود کردیا۔ اے جامعہ ازہر والو! مجھے بتاؤ کہ جب تم اپنی سند کو لیتے ہو تو قرآن کا کون سا حصہ حفظ کرتے ہو اور کتنے سوروں کو ازبر (زبانی) پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ آج کل ''ازہر'' سے فارغ التحصیل ہوکر لوگ جب نکلتے ہیں تو وہ قرآن کو دیکھ کر بھی صحیح طریقہ سے نہیں پڑھ سکتے۔ ''جامعہ ازہر'' نے اتنا سخت ضربہ کھایا ہے یہ کب سے یہ طے پایا گیاہے کہ جامعہ ازہر سے شیخ یعنی وائس چانسلر کو فلسفہ کا ماہر ہونا ضروری ہے( ایک وائس چانسلر (شیخ) نے جرمن سے ڈاکڑیٹ (پی.ایچ.ڈی کی) ڈگری حاصل کی تھی) اس سے پہلے والے شیخ نے فرانس سے فلسفہ میں (پی.ایچ.ڈی) کی ڈگری حاصل کی تھی۔ آیا مسلمان حضرات اس قدر عقیم اور بے صلاحیت ہیں کہ وہ پی. ایچ. ڈی. کی ڈگری لینے کے لئے فرانس جائیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ بعد میں آنے والا شیخ کون ہوگا۔ شاید ایک فوجی اعلیٰ کمان کا افسر (جرنل) جامعہ ازہر پر قبضہ جمالے کوئی کیا جانے؟ لیکن بہرحال اصلاح کے زمانے سے، اسلام کے رہبر نے اس کی ہر طرح کی رہبری اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔'' اور بعد میں اس طرح اضافہ کرتا ہے: ''نئے مفکروں کا اس زمانے میں نئے طریقہ کے مطابق بغیر استاد یا شیخ کے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ براہ راست کتابوں میں رجوع کرتے ہیں لیکن کچھ بھی ان کے پَلّے نہیں پڑتا ،یعنی کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ان دنوں ایک ستر سالہ مؤمن واعظ کی جگہ ایک نوبالغ لڑکا لے لیتا ہے ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب کے چند کلمے اور کچھ صفحات پڑھ کر آیا محافظ ایمان ہوسکتا ہے۔ کتنی مضحکہ خیز نمائش! اے شیخ ازہر اور وہ تمام لوگو! جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اسلام کو تم نے چوپایوں کے چرنے کی جگہ (چراگاہوں) میں تبدیل کردیا ہے کہ جس کاجو بھی جی چاہے اس میں چرنے لگے۔'' پیامبر و فرعون، ص۲۱۹۔ ۲۲۲۔
ان تنقیدوں اور دوسری تنقیدیں جو کہ کی گئی ہیں اور کی جارہی ہیں اس کے باوجود یہ کہنا چاہئے کہ جو ناخواستہ طورپر ان معاشروں میں، سیاسی فعال زندگی سے دوری اختیار کرلی ہے اور یہ بہت زیادہ مشکلات خاص طور سے سنیوں کے مذہبی معاشرہ میں پیدا کردی گئی ہیں۔ ان (اہل سنت) کے معاشروں میں اسلامی تحریکوں کے منحرف ہوجانے کا اصلی سبب انھیں واقعات اور حادثات کی طرف پلٹتا ہے۔ البتہ اس کی تاکید کرنی چاہئے کہ یہ فاصلہ کا ہوجانا ان کی گذشتہ موقعیت کا فطری اور قہری نتیجہ ہے، یہاں تک کہ آگاہانہ ارادہ اور کبھی کبھی ان کا غیر ذمہ دارانہ اقدام سبب بنا ہے، اسلامی تحریکیں منحرف ہوگئی ہے۔ یہ ان کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے بل کہ ان کی تاریخ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی موجودہ آخری صدی کے حالات کا مسئلہ ہے جو تاریخ کی گہرائیوں میں اپنی جڑیں پھیلائے ہوئے ہے۔
یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ رشید رضا کے ایسا شیعہ مخالف انسان جو شیعوں سے پکی دشمنی رکھتا ہے علمائے شیعہ کی مؤثر فعالیت اور ان کے اساسی کردار اور ان کے اسلامی معاشرہ کی حفاظت کی کوشش کی صریحی طور پر قدردانی کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے مذہب کے علما کو بھی تاکید کرتا ہے کہ ان (شیعہ علما) کی طرح اپنا کردار پیش کریں اور فعالیت کو انجام دیں۔ اس کے لئے اندیشۂ سیاسی در اسلام معاصر، نامی کتاب کے ص۱۴۱۔ ۱۴۲، کی طرف رجوع کریں۔
اہل سنت کی روحانیت کے ڈھانچہ اور پوری تاریخ اسلام میں ان کے کردار کے بارے میں آپ اس کتاب کے مفید مقالہ کے سلسلہ میں آپ اس کتاب میں رجوع کریں۔
Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, PP.۸۱-۱۱۳
اور اسی طرح رجوع کریں، قابل مطالعہ کتاب الاسلام بین العلماء و الحکام عبد العزیز البدری کی تالیف کی طرف علمائے دین اور جدت پسندوں اور ترقی پسند لوگوں کی طرف سے تنقیدوں اور اعتراضات کے بازار گرم ہونے کے بارے میں نمونہ کے طورپر آپ رجوع کریں۔ عربی دنیا کے ایک مذہبی روشن فکر اور نفوذ رکھنے والے شخص خالد محمد خالد کی تنقیدوں میں سے ایک کتاب الشیعہ فی المیزان مغنیہ میں: ص۳۷۵۔؛ ۳۷۸
عرب کے غیر مذہبی فکروں میں سے ایک بہت معتبر ادیب احمد بہاء الدین کی تنقیدوں میں سے ایک کتاب الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیثکے ص۱۸۔ ۳۴، پر اساسی کردار کے بارے میں اس کا بے طرفانہ اور ہمدردانہ نظریہ خصوصاًقدیم عربی ادب کی حفاظت میں ان کا مؤثر حصہ دیکھنے کے لئے من حاضراللغة العربیة کے ص۲۴، ۲۵ پر رجوع کریں۔
(۱۲)واضح ترین بات جس کی طرف اوپر والی عبارت میں اشارہ ہوچکا ہے نمونہ کے طورپر شیخ جعفر کاشف الغطاء اور فتح علی شاہ کے روابط میں اس کو بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کی طرف رجوع کریں، رویا روئیتہای اندیشہ گران ایران بادو رویہ تمدن بورژ وازی غرب، ایران کے متفکرین اور مغربی مفکرین کے درمیان پہلی مرتبہ مقابلہ، کے ص۳۲۹، ۳۳۲ پر، دوسرے بہت سے نمونوں کی ''کول'' نشان دہی کرتا ہے۔
Roots of North Indian Shi,ism In Iran and Iraq., PP.۱۱۳-۲۰۴
(۱۳)، معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی نامی کتاب کے ص۱۲۶و ۱۲۵ پر رجوع کریںاور اسی طرح النظریات السیاسیة الاسلامیة کے،ص۷۱، ۷۲ پر بھی رجوع کریں۔
(۱۴)مک ڈونالڈ گولڈ زیہر ) ( Goldziher اس طرح نقل کرتا ہے: ''شیعہ کے درمیان اب بھی مجتہد مطلق پائے جاتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ (شیعہ حضرات) مجتہدین کرام کو امام غائب کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ اسی بناپر مجتہدین کرام کی موقعیت اور مقام ومنزلت بالکل علما اہل سنت سے مختلف ہے۔ انہوں نے شاہ پر آزادانہ طور پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول بھی (مہار) کرلیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کے علما مجموعی طورپر اس کی حکومت کے تابع اور اسی کے افراد شمار کئے جاتے ہیں۔''
Shorter Encyclopaedia of Islam, P.۱۵۸
(۱۵)علما کی صنف (جمعیت) کی طرح دوسرے ادارے بھی اس کے مقابلہ میں مثال کے طور پر مذہبی کمیٹیاں اور مذہبی انجمنیں جو ایران جیسے ملک میں وجود میں آئی ہیں، ہمیشہ معاشرہ کے اسلامی ہونے کی محافظت کرتے رہے ہیں، بہت سے اہل سنت کے مذہبی روشن فکروں نے اسلامی پارٹیوں (گروہ) کی تاسیس کی تجویز پیش کی ہے۔ اس فکر کی ابتدا میں ان کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارے اور انجمنیں قانونی اور معاشرتی طورپر اسلامی قوانین کی حفاظت کے لئے وجود میں آئیں نہ یہ کہ وہ سیاسی کر و فر میں مصروف ہوجائیں (ایرانی معاشرہ میں مرکزی حکومتوں کے مہار کرنے اور مغربی بے راہ روی کو روکنے اور ان کی جدت پسندی اور دین مخالف و قوم مخالف طاقتوں پر قابو پانے والی طاقت کے حامل یہی علمائے دین ہی تھے) معاشرتی اور یہاں تک کہ معیشت کے قدیمی ذرائع کے مراکز اور بازار کے بھی محافظ تھے۔لیکن یا یہ ادار ے تمام اسلامی ممالک میں نہیں پائے جاتے تھے یا اگر موجود بھی تھے تو ان کے اندر اتنی طاقت اور استقلال نہیں پایا جاتا تھا۔ ان ممالک میں جو چیزیں حکومتوں کو کنٹرول اور مہار کرتیں یا ان کو ڈراتی تھیں، وہ لوگوں کے عام افکار تھے۔ لیکن اول یہ کہ یہ سبب بر محل عکس العمل ظا ہر نہیں کر سکتے تھے اور دوسرے یہ کہ موجودہ حکومتوں کی تہدید اور پروپگنڈوں سے متأثر ہوجاتے تھے لہٰذا روشن فکر لوگ اور صالح و مذہبی علما نے اسلامی احزاب کی تاسیس اور بنیاد کی فکر میں پڑ گئے۔ مثلاً کتاب معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی کے مؤلف ایسے احزاب (گروہ) کی تاسیس کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ادا کرنا چاہتے ہوں اس کو واجب جانتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں: ''پس اگر کوئی حزب ایسے عمل پر اقدام کرے جس کا اشارہ آیت میں ہوا ہے تو یہ عمل بقیہ مسلمانوں کے اس عمل کے انجام نہ دینے کے گناہ کو ختم کردے گا، اس کے انجام نہ دینے کا گناہ بقیہ لوگوں کی گردن سے اُٹھا لیا جائے گا۔ کیونکہ یہ (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) واجب کفائی ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے کہ دوسرے احزاب کی تشکیل میں کوئی مانع قرار پائے۔ اس لئے کہ یہ منع کرنا واجب کے مقابلہ میں قیام کرنے کے مترادف اور حرام ہے۔'' اس کے بعد وہ اضافہ کرتے ہیں:'' جیساکہ واجب کے قائم کے لئے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسے قیام کی نسبت حاکم کی اجازت پر موقوف کردینا حرام ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کا اسلامی احزاب قائم کرنے کے لئے اسلامی حکومتوں کی اجازت ضروری نہیں ہے۔''اسی مقام پر ص۲۷۳اور ۲۷۴ پر رجوع کریں۔
ایک دوسرا مؤلف اس بارے میں اس طرح کہتا ہے: ''نقد اور اعتراض انھیں حقوق میں سے ایک حق ہے جس کو اسلام نے تمام اسلامی معاشرہ میں رہنے والوں کے لئے مقرر کیا ہے۔ لہٰذا اگر کچھ لوگ چا ہیں کہ لوگوں کو اپنے افکار و نظریات کی طرف دعوت دیں تو وہ لوگ اس کے ذریعہ احزاب اور کمیٹیاں بناسکتے ہیں۔''
نظام الحکم فی الاسلام کیص۹۲۔ مزید وضاحت کے لئے دیکھئے اخوان المسلمین و الجماعات الاسلامیّہ الحیاة السیاسیة المصریة، ۱۹۔ ۴۸؛ ۳۱۔ ۱۳۲پر، نیز معالم فی الطریق کیص۱۷۳، پررجوع کریں۔
(۱۶)پیامبر و فرعون، کے، ص۲۸۳۔ ۲۹۵پر رجوع کریں۔
(۱۷)جنوبی امریکہ میں انقلابی فکر کے بارے میں اور یہ کہ اس کی خصوصیات کس حدتک تیسری دنیا کے بہت سے خصوصاً اسلامی دنیا کے ممالک میں موجودہ انقلابی افکار کے خصوصیات سے کس قدر مختلف ہیں، اس کے لئے رجوع کیجئے فیدل و مذہب، کی طرف جو'' فری بتو ''کی تحریر اور خاص طورپر چگوارا کے ظریات اور خطابات کے مجموعہ کی طرف اس عنوان کے تحت Che Guevara and The Cuban Revolution اور اگر چگوارا کے بائیں بازو کے افکار کو جاننے کے لئے مثلاً ایران میں انھیں بائیں بازو کے افکار کا ہمزاد موجود تھا جو انقلاب کی کامیابی سے پہلے فدائیان خلق، کی راہ و روش اور ان کے نظریات کا حامل تھااس کتاب کا قیاس جدید نظریہ پردازوں کے بہت بڑے رئیس ''بیژن جزنی'' کی کتابوں کے ساتھ کیا جائے، زیادہ توضیح کے واسطے آپ رجوع کریں ایدئولوژی و انقلا ب کے ص۲۱۴، ۲۲۰اور ایران دیکتاتوری و پیشرفت (ایران آمریت اور ترقی) کے ص۳۷، ۲۴۲، کی طرف مراجعہ کیا جائے۔
Islam and the Search for Social Order in Modren Egypt
اسی طرح مصر کے معاشرہ کی فکری، سیاسی اور معاشرتی انقلاب کو بیسویں صدی کے نصف اول کے روشن فکروں میں سے ایک اہم ترین اور سب سے زیادہ اثر انداز محمد حسین ہیکل کی بایو گرافی کی روشنی میں ان کے بارے میں تحقیق کی جائے۔
(۱۸)نمونہ کے طورپر آن روزہا (وہ ایام) ترجمۂ حسین خدیوجم'' کی طرف رجوع کیا جائے۔
(۱۹)بطور نمونہ، طٰہٰ حسین کے نظریات کی طرف رجوع کریں جس کو انھوں نے اپنی جنجالی کتاب مستقبل الثقافة فی مصر(مصری ثقافت کا مستقبل) ۴۰ئ کی دہائی کے شروع میں تحریر کی ہے وہ اس کے ایک حصہ میں اس طرح تحریر کرتے ہیں: ''تحریک کا راستہ صاف ستھرا اور بالکل سیدھا ہے اور اس میں شک و شبہہ اور کسی بھی طرح کی کوئی کجی نہیں پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے یورپ والوں کی طرح اپنی زندگی ڈھال کر ان کی روش کو اختیار کریں اور ان کے راستہ پر چلنا چاہئے تاکہ جدید تمدن میں بالکل انھیں کی طرح ہوکر ان کے شریک ہوجائیں وہ چاہے اچھی ہوں یا بری خوشگوار ہوں یا تلخ چاہے وہ ان کی طرف سے ضروری ہوں یا ان کو برے لگتے ہوں، چاہے اس کی اچھائیاں ہوں یا خرابیاں۔ جو شخص اس کے علاوہ سوچے وہ یا تو فریب کار ہے اور یا فریب خوردہ (دھوکہ میں پڑا ہو) ہے'' مؤلفات فی المیزان، کے،ص۱۹ سے نقل کیا گیا ہے۔ اس سے ان کی تنقید اور اجمالی نظریات کی تحقیق کی جاسکتی ہے۔
E.Von Grunebaum. Islam, PP.۲۰۸-۱۶
(۲۰)المعالم الاسلامی و الاستعمار السیاسی و الاجتماعی و الثقافی، میں رجوع کریں خصوصاً اس کے ص۱۵۸۔ ۱۵۹پر رجوع کریں۔
(۲۱)محمد المبارک شام کا رہنے والا ہے جس نے موجودہ زمانہ میں اپنے وطن شام کے بارے میں زندہ توصیف کو اپنی کتاب الفکر الاسلامی الحدیث فی مواجھة الافکار الغربی کے تفصیلی مقدمہ میں تحریر کرتا ہے۔ ایک ایسی تعریف و توصیف جو درد و رنج سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا درد و رنج جو اس کی تہذیب و ثقافت، زبان و ادب رسومات اور اس کے دینی مظاہر اور اس کی تہذیب و ثقافت پر حملہ (ہجوم) سے پیدا ہوا ہے۔ خصوصاً اسلام در جہان امروز، (اسلام اور عصر حاضر) ''مؤلفۂ کانٹ ول اسمتھ'' کی کتاب کے، ص۱۱۴۔ ۱۶۱ پر رجوع کیجئے، جو عربوں کے مذہبی احساسات کے مجروح ہونے کو بڑی ہی ہمدردی اور دلسوزی کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اسی طرح سے نئے زمانہ میں مسلمانوں کے حالات کی تشریح کرتا ہے۔
مشرق وسطیٰ کے مطالعات کا بین الاقوامی جریدہ، شمارہ۴، ۱۹۸۱ئ۔
(۲۲)اس قسم کے چند نمونوں کو کتاب ناسیو نالیسم ترک و تمدن باختر، مؤلفٔ ضیاء کوک آلب،( جدید ترکی کے معنوی باپ) کی اس تصنیف میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جس کو سید حسین نصر اپنی کتاب علم و تمدن در اسلام، کی عالمانہ تمہید میں جو اس نظر و تفسیر پر ایک تنقید ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی طرح ایدئولوژی وانقلاب، کے ص۶۴۔ ۹۳ پر رجوع کریں۔
(۲۳)اس تاریخی حصہ میں مسلمانوں اور ان کے حالات اور فکری خصوصیات اور مسلمان روشن فکروں کی فکری خصوصیات معلوم کرنے کے لئے خصوصاً آپ اس تاریخی دور میں ملاحظہ کیجئے جہاں پر ضمنی طورپر ان کے نظریات پر تنقید بھی کی ہے۔ G. E. Von Grunebaum, Islam, ۱۹۴۹, PP.۱۸۵-۸۶
(۲۴)افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی ممالک کے مذہبی سماج کی طرف سے تہذیب نو کی طرف جھکاؤ کی بہ نسبت جوابدہی کے بارے میں اور اسی طرح ان کے نفسیات پر پڑنے والے اثرات کے محاذ سے بھی مسلمان جوانوں کے رجحانات کے بارے میں بہت ہی سرسری جائزہ لیا گیا ہے۔ اس بارے میں ''ایدئولوژی و انقلاب' کے صفحات ۱۶۹۔ ۱۷۸پر رجوع کریں ؛ '' پیامبر و فرعون'' کے ص ۲۷۳اور ۲۹۵ پر رجوع کریں اس طرح ایک سعد الدین ابراہیم مشہور مصری معاشرہ شناس جس نے اکثر مصر کی معاشرتی اور اسلامی تحریکوں کے بارے میں کام کیا ہے اس کی تحقیقات کی طرف رجوع کیا جائے اس کے مقالہ کے خلاصہ کو اور خود مؤلف اور اس کی کارکردگیوں سے روشناس کرایا گیا ہے خصوصاً اس کا وہ مقالہ اس An Anatomy of Egypt Militant Islamic Groups .کے عنوان کے تحت مطالعات مشرق وسطیٰ، مطبوعہ ۱۹۸۱ئ کے بین الاقوامی جریدہ کی طرف رجوع فرمائیں۔
(۲۵)ملاحظہ کریں معیشتی اور معاشرتی تبدیلیوں کی تاثیر کے بار ے میں تیسری دنیا کے جوانوں کی جدائی خواہی کی تحریک (اصالت خواہ ) کے بارے میں، ہند و پاکستان، نامی کتاب کے ص۱۴۱۔ ۱۹۱اور اسی طرح سعد الدین کی کتاب جو The New Arab Social Order .کے عنوان کے تحت ہے اس کی طرف رجوع کریں۔
(۲۶)بیشتر توضیح کے واسطے اس کتاب میں رجوع کریں۔
Islamic Future, The Shape of Ideas to Come, PP,۴۷-۵۹
(۲۷) ہند و پاکستان، کے ص۹۱، ۱۴۱،پررجوع کریں۔
(۲۸)یہ نکتہ اور اس سے وجود میں آنے والے عوارض کی طرف ہیملٹن گب اچھی طرح سے توضیح دے رہا ہے: Modren Trends In Islam, PP,۱۲۴-۱۲۷
(۲۹)نمونہ کے طورپر رجوع کریں: Inside the Iranian Revolution, PP,۳۹-۵۸ .،اور اسی طرح: ایدئولوژی و انقلاب، کے ص۱۵۰۔ ۱۸۴پر بھی رجوع کریں۔
(۳۰)مزید وضاحت کے لئے موج سوم، میں خصوصاً اس کے ص ۳۔ ۲۷۔ ۴۳۱۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۶۱۱۔
(۳۱) ( Idealogy ) مارکسیزم ایڈ یا لوجی کی بنیاد اور فکری عمارت کچھ اس طرح تھی کہ وہ اپنے ماننے والوں اور حاشیہ نشینوں کو ہر وہ شخص جو اس کامخالف ہے اور بنیادی طورپر اس کی افکار کے مخالف تھا ان کوطلب کرلیتا ان سے بیزاری سے پیش آنے کی دعوت دیتا۔ ان لوگوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ جو لوگ ان کی فکر سے ہم آہنگ نہیں تھے ان کے خلاف بڑی ہی سختی اور شدت کے ساتھ پیش آیا گیا ہے، نمونہ کے طورپر ملاحظہ ہو کتاب درزیر زمینی خدا، کا واقعہ ملاحظہ ہو جس میں چینی اور روسی کمیونسٹوں کے ذریعہ ترکستان الشرقیہ، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کا کس بے رحمی سے قلع قمع کیا گیا ہے اس داستان میں اس کی کیفت کو بیان کیا گیا ہے اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ سماچیان کے ساتھ قیام کے بارے میں خاص طور سے اس کے صفحات پر رجوع کیا جائے ، ۵۱، ۱۳۱،
جو چیز اس ملک کے استحکام اور اتحاد کی حفاظت کرتی تھی وہ عملی طورپر اس کے خلافمرکزی حکومت کا فولادی آہنین مشت موجود تھا حجری اور فولادی تہذیب اور عہد استالینی،ا ور جنگ جہانی دوم کے زمانہ والے اکتبر والے انقلاب کے زمانہ کی نسل ظلم ستیزی کے خلاف ارتباط پیدا کرتا اور زندہ قوموں کے آرمانی ثقافتوں کا ان کے ملتے جلتے اجزاء سے پیوند مارکسیسم کی نگاہ میں ایسی قوم جو مارکسیزم کو اس کے نزدیک لائی، صنعتی اور اقتصادی تغییرات اور انقلاب کا وجود میں نہ آنا اور اسی کے اتباع میں سیاسی اور فکری بدلاؤ جو عموماً ۷۰ئ کے آخری دہائی اور ۸۰ئ کی آخری دہائی میں وجود میں آیا اور آج یہ تمام تغییرات اور تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں نمونہ کے طورپر ملاحظہ ہو کتاب گفتگو با استالین, خاص طور سے اس کے ص۲۴۳، ۲۸۷ پر رجوع کریں۔
(۳۳)خصوصاً امپراطوری فروپاشیدہ، کے ص۲۴۷۔ ۲۹۵، پر رجوع کریں۔
(۳۴)فرانسوی مارکسیزم کے ص۳۰، ۴۹، پر رجوع کریں۔
(۳۵)طبقہ جدید، کے صفحات ۱۳۰، ۱۳۲، پر رجوع کریں۔
(۳۶)روسی مسلمان مبلغین کے ذریعہ اسلام اور مارکسیزم کے درمیان یکسانیت پیدا کرنا اور اس کے کم مدت اور طویل مدت میں حاصل ہونے والے نتائج، خاص طورپر'' امپراطوری فروپاشیدہ ''کے ص۲۶۱۔ ۲۷۸پرملاحظہ کریں۔
(۳۷)یہ مشکل تمام ان افکار سے متعلق ہے جو بعض دلیلوں کے سبب ان کے سمجھنے اور ان سے وابستگی کے علاوہ آگے بڑھ رہی ہے مارکسیزم بھی تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسی مشکلات سے روبرو رہی ہے۔توضیح کے لئے ملاحظہ ہو ''ایدئولوژی و انقلاب'' ص۲۱۵، ۲۱۶۔
(۳۸) Muhammedanism کے جیسی مختصر اور دقیق کتاب کی آخری فصل میں ملاحظہ کیجئے
ہیملٹن گب نے اپنی کتاب میں ایک زمانہ پہلے بڑی ہی دقت اور ہوشیاری کے ساتھ عصر حاضر میں اسلامی عقب نشینی کے ناممکن ہونے کے بارے میں بیان کیا ہے۔
(۳۹)اس تطبیق کا بہترین نمونہ Vatican Council ۲nd, PP,۹۰۳-۱۰۱۴ :
آپ کو یہ مل جائے گا کہ اسلام اور عیسائیت کا عکس العمل جدید تمدن کے مقابلہ میں اس کے اثر کو نئی تہذیب کے ماننے والوں پر بھی چھوڑا۔ اس بارے میں خصوصاً آپ روشن فکران عرب و غرب, کے ص۱۴، ۷ ۱،پر رجوع کریں۔
(۴۰)بلانٹ اپنی کتاب The Future of Islam, London, ۱۸۸۲ میں معتقد تھا کہ مستقبل لا مذہب مسلمانوں سے متعلق ہے یعنی سماج میں ان کا بول بالا ہوگا۔'' Islamic Futures,P,۲۵
(۴۱)موجودہ صدی میں مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ترقی پسند اور نئی فکر کے حامل افراد پروٹسٹان کی تحریک سے قوت لیکربغیر اس توجہ کے قیام کردیا کہ انھیں کے جیسا کوئی اقدام کر یں اہمیت کا حامل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بعض افراد کا' لوٹر' کی طرح عوام بعض گروہ کی طرف سے تعارف کرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ بھی اسی کی طرح کامیابی حاصل کرلیں گے اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایسا نہ ہوگا۔ اس کا ایک بہترین نمونہ عبدالرزاق ہے اس کے باوجود کہ اس کی کتاب الاسلام و الاصول الحکم تقریباً پوری کتاب تاریخی اور علمی حقائق پر استوار ہے لیکن چونکہ اہل سنت کے بنیادی اصول کی مخالف تھی لہٰذا اپنے لئے راستہ نہ بناسکی۔ اس لئے کہ اس کے اصول ایسے نہیں تھے جو زمانہ کے ساتھ ساتھ پُرانے ہوجائیں اور وہ بھُلا دیئے جائیں۔
یہاں مناسب ہے کہ وہ چیز جو اس زمانہ کی معتبر اور معروف ترین نشریات میں سے یعنی المقتطف نامی جریدہ جو اس کتاب اور اس کے مؤلف کی شان میں تحریر کیا گیا ہے میں اُسے نقل کر رہا ہوں: ''اس کتاب نے جو غوغا اپنے مؤلف کے خلاف مچایا جو جامعہ ازہر کے علما میں سے ہیں اور شرعی عدالت کے قاضیوں میں سے ہیں، ان کے خلاف جنجال برپا کردیا اس نے ہم کو اس شور و ہنگامہ کی یاد دلادی جو عیسائیت میں دینی مصلح اور ان کے پیشوا لوٹر کے خلاف برپا کیا گیا تھا ۔وہ ایسا شخص تھا جس کے اقدام کا نتیجہ اور زیادہ تاثیر عیسائی ممالک کے دینی، ادبی اور مادی حلقوں میں تھاہماری نظروں میں جو کچھ عبد الرزاق نے تحریر کیا ہے وہی اثر پڑنے والا ہے جو لوٹر کی تحریر کی وجہ سے اثر پڑا ہے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ لوٹر اور اس کے ساتھیوں نے کہا اور کیا وہ پورا کا پورا درست تھا، اسی طرح اس وجہ سے بھی نہیں کہ ہم عبد الرزاق کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ عبد الرزاق اور ان کی طرح کے لوگوں نے جوکچھ کہا ہے، وہ سب کچھ صحیح اور اس میں خطا و لغزش کا گذر نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ بعض متفکرین کا شبہہ آمیز تنقیدی موقف بحث و تحقیق اور چھان بین تک پہونچا دیتا ہے اور پردوں کو چاک کرکے حقائق کو آشکار کر دیتا ہے۔ ہم ابھی تک نہیں بھولے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ کے خلاف سب نے مل کر کیا کیا ہنگامہ کیا ،لیکن آ ہستہ آہستہ امو سلادھار بارش تھم گئی یہاں تک کہ انھیں (شیخ محمد عبدہ کو) امام کا لقب مل گیا ۔سب لوگوں نے ان کی اقتدا کی اور ان کے راستہ کو اپنا لیا۔ المقتطف اکتوبر ۱۹۲۵ئ کے شمارہ کے ص۳۳۲، پر محمد عمارہ کی کتاب الاسلام و اصول الحکم کے مقدمہ کے صفحہ ۲۴، سے نقل کیاگیا ہے۔
Johnsen,"International"Islam The Economist,۳,jan,۱۹۸۰
ماخوذ از Asaf Hussain, Islamic Movemeuts: P.۱۲th
(۴۳)ان حقائق کو بہت سے انگریزوں نے اگرچہ وہ دشمنی اور کینہ سے بھرے انداز اختیار کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ Islamic Futures, PP.۴۳-۴۴
Ibid. PP.۲۷-۳۵ اور اسی طرح The Dagger of Islam, PP.۴-۹: ۶۹-۸۲
کہ اس درمیان مؤلف نے مغرب پرست عیسائیوں اور عربی دنیا میں دنیا پرست مسلمانوں کے فرق کو جدید تمدن سے ملنے پر واضح کیا ہے اس کے واسطے رجوع کریں The Dagger of Isran, p. ۲۷-۳۵
(۴۴) عیسائیت کا تمدن کے ساتھ روبرو ہونے اور یہ کہ آج کل کے انسانوں کے واسطے کیا پیغام رکھتا ہے اور کیا پیغام رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ رجوع کیجئے آج کے عیسائیوں کے بزرگ علما میں سے ایک بزرگ عالم کی طرف جس نے مندرجہ ذیل عنوان پر لکھا ہے۔
On Being a Christian, PP.۲۵-۵۱:۸۹-۱۱۲: ۵۵۴-۶۰۱
(۴۵)اس بارے میں بہترین نمونہ سید قطب الدین کی کتاب معالم فی الطریق ہے۔ اس کتاب کے ابتدائی اور اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ان لوگوں کی جرئت مندانہ اور پوری قدرت کے ساتھ آخری رد ہے جو مؤلف کی تعبیر کے مطابق شکست خوردہ اور سست عناصرہیں (المہزومون روحیاًو عقلیاً)اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آج کل کی جدت پسندی اور چٹک بھڑک کو اسلام میں نمایاں کردیں اور اسلام کی شجاعت اور بہادری کی روح کو بالکل سے ختم کردیں۔ اگرچہ یہ کتاب ایک ایسے تیز گام گروہ کے دستورالعمل کے عنوان سے جن لوگوں نے اسلامی معاشرہ کی تاسیس کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے ان کے واسطے لکھی گئی ہے ملاحظہ ہو اس کے ص۵۰، ۵۱ ،کی طرف۔ لیکن گویا اس کی اصلی ذمہ داری تمام ان لوگوں کی واقعی اور ہمہ جانبہ مخالفت کا قد علم کرنا ہے جو اسلامی تہذیب اور اس کی حقیقت کواہمیت نہیں دیتے ہیں۔ الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالافکار الغربی نامی کتا ب کی چوتھی طباعت کے مقدمہ کی طرف بھی رجوع کریں اس کا مؤلف صریحاً کہتا ہے:'' ایسے مشرق پسند لوگوں کی کوششوں کا خطرہ جو ہمیشہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے دین کو معتدل کریں اس طرح کہ وہ جدید تمدن کے ساتھ سازگار ہوجائے، مسلماً مارکس کے نظریہ کے تحت چلنے والے نظام کے خطرہ سے کم نہیں ہے'' قابل ذکر بات یہ ہے کہ مؤلف نے یہ بات ایسے وقت میں کہی جب مارکسیزم نے اپنا ڈیرہ تمام جگہ ڈال دیا تھا۔ زیادہ انقلابی اور جاندار نمونوں کو معلوم کرنے کے لئے مصر و شام کی اخوان المسلمین کمیٹی کے الدعوة و النذیر نامی جریدہ کے مختلف شماروں کی طرف رجوع فرمائیں۔
(۴۶)یہاں پر لازم ہے کہ اگرچہ اہم نقطہ کو اجمالاً تحریک اسلامی کے آئندہ روابط کے بارے میں یاددہانی کرادوں۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس بارے میں سنجیدگی اور حق گوئی کے طورپر حقیقت کو بہت کم بیان کیا گیاہے اور یہ اس تحریک کی کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری ہے بہرحال کوشش کریں گے کہ ہم چند اہم نکات کو بیان کریں۔
موجودہ اسلامی تحریک کی بنیادی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی تمام مشکلات کا حل صرف ایمان اور ایثار کی روشنی میں تلاش کرناچاہتی ہے عصر حاضر کی زندگی کی اہم ضروریات کو تقریباً نظر انداز کردیتی ہے اور ان ضرورتوں کو مغربی تہذیب و تمدن سے بہت کم جدا کرتی ہے۔ مغربی تمدن بلکہ بہتر ہے کہ تمدن جدید کا نام دیں ،کیونکہ اب یہ تمدن فقط مغرب سے متعلق نہیں ہے، اب یہ تمدن عالمی تمدن ہوگیا ہے اور اس انقلاب میں سبھی لوگوں کا کردار اور حصہ ہے، یہ مسئلہ کا ایک رخ ہے اور آج کی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لوازم ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ دنیا میں عقیدہ کاحامل کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی مومن اور موحد کلی طورپر اس تمدن اور تہذیب کی کاملاً طرفداری نہیں کرسکتا۔ یہ چیز بہت واضح اور روشن ہے اس میں کسی قسم کی بحث و گفتگو کی ضرورت نہیں ہے ۔لیکن یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ آج کی دینا میں زندگی بھی چند اصول و ضوابط کی پابندی کی محتاج ہے ان اصول کی طرف توجہ دیئے بغیر زندگی نہیں کی جاسکتی یا کم از کم باعزت اور مستقل طورپر زندگی گذارنا بس دشوار کام ہے۔ پابندی اور غورو فکراور پیہم کوشش کرتے رہنا اپنی ذمہ داری کو جاننا نظم اور قانون مندی، کام کی طرف رغبت، انتظام سنبھالنا، قانون کی فرمابرداری اور قانون شکنی کے لئے عذر نہ تراشنا۔ ذمہ داری کو قبول کرنا اور غیر ذمہ دارانہ مداخلت سے پرہیز کرنا اور اپنی ہی حدتک محدود رہنا اور اپنی قدرت اور وسعت سے زیادہ توقع نہ رکھنا، نعاشرتی طورپر اپنے آپ کو ہم آہنگ کرکے اس کا تعاون کرنا اور آخرکار علم و عقل کی بنیاد پر فکر کرنا اور محاسبہ کے اعتبار سے پختہ ارادہ ہے اور تصمیم کرنا۔ البتہ اس مقام پر جہاں پر علم و عقل اور محاسبہ کو مداخلت کرنی چاہئے وہ مقامات انھیں لوازم میں سے ہیں۔ اگر گذشتہ زمانہ میں ان چیزوں کی طرف توجہ کئے بغیر معاشرہ کا ادارہ کرنا ممکن بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل (علم و عقل کے بغیر) بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور تعجب کا مقام یہ ہے کہ اسلام نے بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں صریحی اور تاکیدی حکم دیا ہے،لیکن ان آخری صدیوں میں مسلمان لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے رہے ہیں کہ دوسری ہر ملت و امت سے بہت کم ان چیزوں کے پابند رہے ہیں۔ ان چیزوں پر پابندی نہ کرنے کی بہت سے تاریخی، معاشرتی، اخلاقی، تربیتی اور نفسیاتی اسباب تھے کہ ہمیں ان کو اچھی طرح غور و فکر کرکے پہچان لینا چاہئے۔
اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل مسلمانوں کا اسلام کے بارے میں عمیق ذاتی اور فردی نظریہ رکھنا ہے۔ ماضی میں ایک اچھا شخص وہ سمجھا جاتا تھا ،جو عبادی احکام کو بجالانے کے علاوہ مثال کے طورپر اہل خیرات بھی ہو۔ مسجد، مدرسہ، پانی کے ذخیرہ انتظام اور پُل اور اس کے ایسی چیزیں بناکر لوگوں کے لئے وقف کردینا تھا۔ موجودہ دور میں لوگوں کی دین فہمی معاشرتی اور انقلابی میلان کے زیراثر قرار پاگئی ہے، اس زمانہ میں اچھا شخص اُسے کہا جاتا ہے جو مثال کے طورپر بے دینوں، مفسدوں اور جباروں سے زیادہ مقابلوں کے مختلف میدانوں میں بہترین استقامت کے جوہر دکھائے۔ بیشک یہ تمام چیزیں حقیقی ایمان کی علامتیں ہیں۔ لیکن مشکل اس مقام پر ہے کہ اس طرح کی علامتوں کے علاوہ، دینی ایمان کے دوسرے مظاہر کی طرف اساسی اعتبار سے یکسر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ان کی نظر میں کسی شخص کے اچھے ہونے کا یہ معیار نہیں ہے کہ مثال کے طورپر وہ اچھے طریقہ سے غور و خوض اور حوصلہ کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہوجائے اور یا لگاتار کام میں لگے رہ کر امانت داری کے ساتھ کام کو آخر تک پہنچائے یا لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا تعاون کرے جو آج کی صنعتی اور تکنیکی زندگی کا لازمہ ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام میں مشغول ہوجائے کسی بات کو اچھے طریقے سے کان دھرکے سُنے اور مختلف بہانوں کے ذریعہ کام سے جی نہ چرائے اور وہ امور جو اس سے متعلق نہیں ہیں ان میں مداخلت نہ کرے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے مفاہیم اور مطالب ہمارے درمیان جانے پہچانے نہیں ہیں، دین اور دینی ذمہ داری سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہاں تک کہ یہ بھی کہنا چاہئے کہ اس قسم کے مسائل نہ فقط پہچانے ہوئے نہیں ہیں بلکہ عملی طورپر ان کے مخالف ہیں جو حاکمیت رکھتا ہے اور اس کو اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ نمونہ کے طورپر اگر ''چالاکی'' کے مفہوم کو ہمارے عرف کے درمیان بیان کیا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کے مصادیق کون لوگ ہیں تو بخوبی معلوم ہوجائے گا کہ کسی حدتک ذہن و فکر و روح پر حاکم مفاہیم ہیں چاہے فردی یا ذاتی ہوں یا معاشرتی ہوں، جو آج کی دنیا میں ضروریات زندگی سے تضاد اور اختلاف رکھتے ہیں، اس سے بدتر یہ ہے کہ اس قسم کے مفاہیم نے دین میں اپنی جگہ بنالی ہے اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جو ان کو دین، ایمان اور اخلاص کے خلاف گردانتے اور جانتے ہیں۔ جب تک یہ مشکل کم سے کم اطمینان بخش انداز پر حل نہ ہوگی، معاشرہ ترقی کے زینوں کو طے نہیں کرسکتا۔ جیساکہ اس کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے کہ یہ مشکل صرف ہماری مشکل نہیں ہے بلکہ کم و بیش تمام اسلامی معاشروں اور عصر حاضر کی اسلامی تحریک کے لئے یہ مشکل ہے۔ ہماری مشکلات کا حل فقط خود جوش پیدا ہونے والی فداکاری میں نہیں ہے ان معنی میں ایثار اور فداکاری جو آج کل رائج ہیں اس سے ہماری مشکل حل نہ ہوگی۔ اور بیشک یہ شرط لازم و ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ یہ ایثار اور فداکاری ان اصول و اقدار کے ساتھ ہونا چاہئے جو اس تاریخی دور میں زندگی کے لئے ضروری ہے اور ان اصول و اقدار کا آپسی ارتباط ضروری ہے، اس میں اس طرح رابطہ ہونا چاہئے کہ ہماری اور اس امت اسلامی کی سرفرازی اسی رابطہ کی مرہون منت ہے۔ یہ پیوند اس طرح ہونا چاہئے کہ نہ دینی بنیادوں کو کوئی نقصان پہونچیاور نہ ہی یہ مفاہیم اتنے زیادہ پست ہوجائیں کہ ہر قانون شکن، فریضہ ناشناس، بے نظم، آرام طلب، لاپراوہ اور جہالت اور ہر طرح کی بات کو کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی توجیہ کرے یا ان کو قانونی اور جائز قرار دے۔ اسلامی دنیا کے اس وسیع دائرہ میں قدرے تسامح کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اسلامی ممالک جو ایران کے مشرقی سمت میں واقع ہیں، وہ اس مشکل سے کم تر روبرو ہوئے ہیں اور جتنابھی مشرق کی طرف بڑھتے جائیں، یہ مشکل کم ہوتی جاتی ہے۔ ترکی اور اصولی طورپر ترک زبان لوگ چاہے وہ ایران میں ہوں یا بیرون ایران، مختلف اسباب کی وجہ سے ایرانیوں سے کم اس مشکل سے روبرو ہوئے ہیں۔ عربی دنیا میں یہ مشکل ایران ہی کی طرح سنجیدہ، پیچیدہ اور عمیق ہے اگرچہ ان ممالک میں سے ہر ایک ملک میں گذشتہ حالات کے اعتبار سے قوی اتحاد کا استحکام، استعماری تجربہ اور موجودہ حکومت کی نوعیت کے اعتبار سے، اس مشکل میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ اس کی بیشتر وضاحت کے لئے آپ '' افریقہ میراث گذشتہ و موقعیت آئندہ'' کے ص۸۱۔ ۸۶،پر رجوع کریں اور اسی طرح دو کتاب ضیاء الدین سردار کی ہیںجو دنیائے اسلام کے معاشرتی، معیشتی اور ثقافتی مسائل کے معروف ماہر ہیں، وہ کتابیں اس عنوان کے تحت ہیں:
The Future of Muslim Civilization, Islamic Futures ,
(۴۷)گذشتہ زمانہ کے بعض علما اور اسی طرح عصر حاضر کے صاحبان قلم اس فرق کی طرف عالمانہ طورپرتوجہ کر رہے ہیں۔ قدیم زمانہ کے علما میں سے آپ رجوع کریںکتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل کے مصنف ابن حزم،ج، ع، ص۹۴۔ ان کے بیان کا کچھ حصہ اس طرح ہے: ''یہ صحیح نہیں ہے کہ، آپ اپنی روایتوں کے ذریعہ ان( شیعوں) کے خلاف دلیل پیش کریں۔ کیونکہ وہ لوگ ہماری روایات کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی روایتوں کے ذریعہ ہمارے اوپر احتجاج نہیں کرسکتے کیونکہ ہم ان کی روایات کو صحیح نہیں جانتے یہ ضروری ہے کہ مباحثہ کے دونوں فریق ایسی چیز کے ذریعہ استدلال کریں (احتجاج کریں) جو ایک دوسرے کو قابل قبول ہو چاہے اس سے دلیل پیش کرنے والا خود اس کا قائل ہو یا قائل نہ ہو...''
اور دور جدید کے صاحبان قلم یعنی متأخرین کی طرف آپ رجوع کرنا چاہیں تو معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی کے ص۱۳۱۔ ۱۳۸اور کتاب الفکر السیاسی الشیعی کے ص۱۱۶۔ ۱۸۰، پر رجوع کریں ۔
دوسری فصل
فہم تاریخی
صدر اسلام کی تاریخ پر ایک نظر
اہل سنت اور شیعوں کی سیاسی فکر کی تصویر کشی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سبب، تاریخ اسلام پر ان دونوں یعنی اہل سنت اور شیعوں کے زاویۂ نگاہ کی کیفیت ہے۔ البتہ اس بحث کی اہمیت فقط اسی میں محدود نہیں ہے جس کی مدد سے ہم ان دونوں کے سیاسی افکار کے معیار کا پتہ لگا لیں بلکہ بنیادی طورپر ان دونوں مذہبوں کے دینی فہم کلی طورپر اور اس کی تمامیت کے لحاظ سے اس فکر کے زیراثر ہے۔ اگرچہ اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ ایسے نظریہ کی تاثیر ان دونوں کی سیاسی فکر کو وجود میں لانے کے لئے اس کی تاثیر دوسرے مباحث میں ہونے والی تاثیر سے زیادہ ہے۔
جیسا کہ اس سے پہلی والی فصل میں کہا جاچکا ہے کہ مسئلہ صدر اسلام کی تاریخ، خصوصاً خلفا ئے راشدین کے زمانہ کی تاریخ صحابہ و تابعین کے زمانہ کی تاریخ، اہل سنت کے درمیان بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ حالانکہ شیعوں کے نزدیک تاریخ کا یہ زمانہ دوسرے تمام زمانوں کی تاریخ سے کوئی امتیاز نہیں رکھتا ہے اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقط نظری اعتقاد کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت اس کے واسطے کسی خاص دینی اہمیت کے قائل ہیں اور شیعوں کے نزدیک اس کی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ فقط اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ ایسے نظریہ نے ان دونوں فرقوں کے ماننے والوں کو دین کے سمجھنے میں بہت شدت کے ساتھ متأثر کردیا ہے۔ جہاں تک کہ اہل سنت اسلام کو، کلی طورپر، اسی مخصوص زمانہ کی تاریخ کے معیار پر پرکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ اس تاریخی دور کو وہ تعلیم اسلامی اور اس کی عینیت کا مظہر سمجھتے ہیں۔ اور شیعہ لوگ تاریخ کے اس حصہ کے برخلاف اسلامی معیار کے مطابق پرکھتے اور دیکھتے ہیں؛ لہٰذا اس مخصوص زمانہ کی تاریخ کے متعلق تنقیدی موقف اپناتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس دقیق نکتہ کا سمجھنا ان دونوں گروہوں کے دینی افکار کے سمجھنے میں اور خاص طور سے ان دونوں کی سیاسی فکر کا سمجھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے؛ لہٰذا پہلے اسی بحث کو شروع کررہے ہیں۔
اہل سنت تاریخ کے شروعاتی دور کے واسطے اور کم سے کم خلفائے راشدین کے آخری دور تک، ایک خاص دینی شان اور حیثیت ، بلکہ خدا ایک داد تقدس کے قائل ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ عقیدہ کیوں، کس طرح اور کس زمانہ میں ظاہر ہوا اور اس نے دینی فہم پر کیا اثر چھوڑا اور خصوصاً سیاسی افکار اور معاشرتی و تاریخی تبدیلیوں پر کیا اثر ڈالا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام (اس مقام پر تاریخ سے مراد رحلت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم سے لے کر خلفائے راشدین کے آخری دور تک ہے اور عام طورپر اہل سنت متفقہ طورپر اس (خلفائے راشدین کی خلافت کے) زمانہ کو دین کا بہت زیادہ اہمیت والا زمانہ سمجھتے ہیں) صدر اسلام کے مسلمانوں کی نظر میں یہ زمانہ خصوصیت کے ساتھ دین کے لئے بے اہمیت زمانہ تھا ۔ وہ لوگ نہ فقط یہ کہ ایسی اہمیت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے بلکہ یہاں تک کہ وہ اس کے کسی امتیاز کے بھی قائل نہیں تھے بعد میں پیش آنے والے واقعات اور حوادث نے ایسے عقیدہ کو جنم دیا۔
دوسرے لفظوں میں اس دور کی تاریخ کچھ اس طرح وجود میں آئی اور بعد میں اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھا جانے لگا،یہ دونوں دور بہت زیادہ مختلف تھے۔ اہل سنت کی دینی فکر اور اس طرح ان کی سیاسی فکر بھی اسی نظریہ کے تابع تھی نہ کہ اس کے وجود میں آنے کی۔ اب دیکھتے ہیں اس کی داستان کس طرح تھی اور کن کن نشیب و فراز سے گذری اور کہاں تمام ہوئی اور بنیادی طور پر ایسا کیوں ہوا۔ اس بحث کی وضاحت کے لئے ہم مجبور ہیں کہ اس کے وجود میں آنے کی کیفیت کی چھان بین اور تجزیہ کریں اور اس کے بعد اس نظریہ اور عقیدہ کے پیدا ہونے کی کیفیت کو بیان کریں۔
اس مقام پر حقیقی نکتہ، جیساکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ تھا کہ اس زمانہ کے تمام مسلمانوں کی نظر میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم اور ان کے عہدۂ نبوت کے علاوہ کسی شخص کے لئے کوئی خاصمقام و منزلت اور حیثیت کی حامل نہیں تھی کہ وہ خاص تقدس کا حامل کہا جائے۔(۱) (بعد میں ہم بتائیں گے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کے دستور کے مطابق حضرت علیـ کے لئے ایک بلند و بالا مقام و منزلت کے قائل تھے۔) یہاں تک کہ خلافت اور خلفا بھی کسی خاص شان و حیثیت کے حامل نہیں تھے۔ اس زمانہ کے واقعات کے اجمالی مطالعات نے ہم کو اس نتیجہ تک پہنچا دیاہے۔
ابوبکر کا انتخاب
پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعدابوبکر کی خلافت کا انتخاب کیا گیا۔ لوگوںپیغمبر کے خلیفہ اور جانشین ہونے کے عنوان سے ابوبکر کو اپنے دنیاوی امور کے لئے منتخب کرلیا گیا (صرف خلیفۂ رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم (نہ کہ اس سے زیادہ) یعنی معاشرہ کو ادارہ اور ان کے امور کو منظم کرنے والے کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ البتہ یہ بات نہ بھولنا چاہئے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے سیاسی،اورمعاشرتی اور دنیاوی امور کا مفہوم اس زمانے سے مختلف تھا۔(۲)
اسلام اس زمانے میں معاشرہ میں اسی زمانہ کے اصول و قوانین اور اپنے مقدسات کے مطابق تغییرات وجود میں لایا تھا معاشرتی (دینی، سیاسی)( دینی اور معیشتی) اداروں کی بنیاد ڈالی تھی جو فی الحال سایہ فگن تھے۔ ابوبکر خلافت کے لئے منتخب ہوئے تاکہ ایسے معاشرہ میں ادار ے کی ذمہ داری کو سنبھال لیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس کے دینی اور دنیاوی امور کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا تھا ۔یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے والے پیوند کے ذریعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور اہمیت کا حامل یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ شروع ہی سے اس طرح وجود میں آکر پلا بڑھا اور پروان چڑاھا تھا اور اس کے دینی اور دنیاوی عناصر ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کی نظر میں ان عہدوں کے لئے صلاحیت کو پرکھنے کے لئے کسی خاص شرائط کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف مسلمان ہونا اور خصوصاً ان تمام امور کا ذمہ دار ہونا ہی اس کی صلاحیت کے احراز کے لئے کافی تھا۔(۳)
مثال کے طورپر نماز جماعت اور جمعہ معاشرتی اداروں میں سے ایک ایسا ادارہ ہے جو نو مسلم معاشرہ کا مذہبی سماج تھا۔ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے زمانہ میں یہ دونوں نمازیں آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی موجودگی میںچاہے وہ مدینہ میں ہو یا دوران سفر ہو ںیا کہ میدان جنگ میں ہوں آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کی اقتدا میں ادا کی جاتی تھیں اور جن جگہوں پر حضرت موجود نہ ہوتے تھے اس شخص کی اقتدا میں نماز ادا کی جاتی تھی جس کو آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت نے امیرا ور اپنا جانشین مقرر اورمعین فرمایا ہو مثلاً جنگ کے موقع پر نماز جماعت اور جمعہ لشکر کے سردار کی اقتدا میں ادا ہوتی تھی اور مدینہ میںآنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کی عدم موجودگی میں آپ کا وہ جانشین نمازوں میں امامت کرتا تھا جس کو خودآ نحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم مقرر فرماتے تھے۔
اسی طرح جیساکہ بیت المال بھی آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے حضور میں آپصلىاللهعليهوآلهوسلم ہی کے ہاتھوں میں تھا اور حضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی عدم موجودگی میں امیر لشکر یا اس جانشین کے ہاتھ میں ہوتا تھا جس کو آنحضرت معین فرماتے تھے۔ فیصلہ دینے اور حَکَم بننے اور سیاسی انتظامی (فوجی) امور کے ادارہ میں بھی عیناً وہی دستورالعمل تھا۔ لیکن ان منصبوں کا احراز کرنا اس وقت کے مسلمانوں کی نظر میں اس معنی میں نہیں تھا کہ جو بھی فرد ان منصبوںکا عہدہ دار ہو، اس کی کوئی خاص دینی حیثیت ہو اور وہ خاص مقام و منزلت کا حامل بھی ہو ان دنوں کے مدینہ کے مسلمانوں کا تجربہ اس مفہوم کو ذہن میں راسخ کر رہا تھا کہ حاکم اپنی جگہ حاکم ہے، چاہے اس کی ذمہ داری کا دائرہ وسیع ہو یا محدود ہو، ان عہدوں اور منصبوں کو وہ اپنے ذمہ لیتا ہے اسی وجہ سے کبھی بھی یہ فکر پیدا نہ ہوئی کہ ایسے کاموں کی ذمہ داری کا سنبھالنا حاکم کو ایک خاص دینی منزلت اور مرتبہ عطا کر کے اسے مزید ترقی دے دے گا۔
علی عبد الرزاق نے اپنی معروف کتاب کی ایک فصل میں ان واقعات کو مفصل اور تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے جوواقعات پیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد رونما ہوئے وہ اپنے تحلیل و تجزیہ کے بعض ان حوادث کے بارے میں جو ابوبکر کے انتخاب سے پیدا ہوئے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں: ''... اس دن (یعنی پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے روز) مسلمان اس بات کے مشورہ میں مشغول ہوگئے کہ وہ لوگ ایک ایسی حکومت جس کو وجود میں لانا ضروری تھا اس کے بارے میں مشغول ہوگئے ۔ واقعاً یہی سبب تھا کہ ان کی زبان پر امارت و امرا اور وزارت و وزرا کے ایسے کلمات جاری تھے اور قدرت و شمشیر، عزت و ثروت، شان و شوکت اور عظمت اور اپنی بزرگی کی باتیں کررہے تھے۔ اور ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی مگر صرف اس لئے کہ حکومت اور ایک سلطنت کو وجود میں لانے کی تمام کوششوں میں غرق ہوجانا ہی اس کا اصلی سبب تھا، جس کا نیتجہ یہ ہوا کہ مہاجرین و انصار اور بزرگ صحابہ کے درمیان رقابت پیدا ہوگئی۔ یہاں تک کہ ابوبکر کی بیعت کرلی گئی اور وہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے۔
اگر ان حالات پر غورو فکر کیا جائے جن حالات کے تحت ابوبکر کی بیعت کرلی گئی اور یہ کہ وہ کس طرح مسند خلافت پر براجمان ہوگئے؛ تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ بیعت محض ایک سیاسی اور حکومتی بیعت تھی اور جدید حکومتوں کی تمام خصوصیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ وہ بھی دوسری حکومتوں کی طرح برپا کی گئی۔ یعنی قدرت اور تلوار کے زور پر قائم کی گئی۔
یہ ایک نئی حکومت اور سلطنت تھی جس کو عربوں نے قائم کیا۔ لہٰذا یہ سلطنت ایک عربی سلطنت اور حکومت تھی۔ لیکن اسلام، جیساکہ آپ جانتے ہیں کہ تمام بشریت سے متعلق ہے۔ نہ عربی حکومت ہے اور نہ ہی عجمی ہے۔ لیکن یہ حکومت ایک ایسی عربی حکومت تھی جو دینی دعوت کے نام پر برپا کی گئی تھی۔ اس کا نعرہ اس دعوت کی حمایت اور اس کا قیام تھا۔ شاید اس دینی دعوت کی ترقی میں بھی واقعاً ایک بڑا اثر موجود تھا؛ بلا شک وشبہہ اسلام میں تبدیلی لانے میں کلیدی حیثیت کا حامل رہی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود، پھر بھی ایک ایسی عربی حکومت تھی کہ عربوں کی قدرت کو مستحکم کررہی تھی اور ان کے مصالح کی تلاش میں مصروف تھی۔ زمین کے کونے کونے کوان لوگوں(اعراب) کے قبضہ میں دے دیا اور اس کو اپنی خدمت میں لے لیا۔ بالکل دوسری طاقتور اور فاتح قوموں کی طرح... اس زمانہ کے مسلمانوں کی فہم یہ تھی کہ اس کے انتخاب کے ذریعہ مہذب اور دنیاوی حکومت قائم کرلیں گے اورا سی وجہ سے خلافت کے خلاف مخالفت اور علم بغاوت بلند کرنے اور اس کے خلاف خروج کو جائز جانا۔ وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ اس بارے میں ان کا اختلاف صرف دنیاوی امور میں سے ایک امر میں ہے اور دینی امور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ان لوگوں نے ایک سیاسی مسئلہ پر اختلاف کیا تھا جس کا ان کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ اختلاف ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کررہا تھا۔ نہ ابوبکر اور نہ ہی اس کے خاص لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اس فکر میں نہیں تھے کہ مسلمانوں کی رہبری کا حاصل کرنا ایک دینی مقام ہے اور نہ ہی ان کے خلاف بغاوت دین کے خلاف بغاوت اور خروج کے مترادف ہے۔ ابوبکر صریح انداز میں یوں کہا کرتے۔تھے:'' اے لوگو! میں بالکل تمہاری ہی طرح ایک شخص ہوں اور نہیں معلوم شاید تم لوگ مجھ کو ان کاموں کی ذمہ داری میرے سر عائد کر دو جن کے انجام دینے کی طاقت صرف پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم رکھتے تھے۔ خداوندعالم نے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کو دنیا والوں پر منتخب کیا اور ان کو ہر بلا و آفات سے محفوظ کر دیا اور ان کوعصمت بخشی اور میں تو صرف ان کا تابع ہوں اور کسی نئی چیز کا وجود میں لانے والا نہیں ہوں۔
نیا رنگ اختیار کرنا
لیکن بعد میں آہستہ آہستہ بہت سارے اسباب کی بناپر ابوبکر کے انتخاب کو دینی رنگ دے دیا گیا اور لوگوں پریہ پیش کیا کہ وہ دینی عہدہ پر فائز تھے اور وہ اپنے اس منصب پر پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے نمائندہ تھے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان یہ فکر پیدا ہوگئی کہ ان کی حکومت کا مفہوم دینی مقام ومنزلت اور حیثیت کا حامل ہے اور پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی نیابت ہے۔ اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان یہ فکر پیدا ہوئی وہ ایک لقب تھا جس کو ابوبکر پر چسپاں کر دیا گیا اور اس کو خلیفۂ رسول اللہ کا نام دے دیا گیا۔''(۴)
چنانچہ اسی فکر کی بنیاد پر جو ایک حاکم کے متعلق موجود تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ابوبکر کی خلافت کے لئے اقدام کیا۔ ان کی نظر میں وہ (ابوبکر) دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام انسان تھا اور ایسے منصب پر لایا گیا تھا جو ہر طرح کی دینی شان اور مقام و منزلت سے عاری تھا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ منصب اور اس کے فرائض اور قاعدتاً اسلامی نوخیز سماج کی تشکیل نو اور اس کے وہ ادارے جن کی تعیین اور حدبندی دین کے ذریعہ ہوچکی تھی، لیکن یہ واقعہ اس زمانہ کے مسلمانوں کی نظر میں اس سے زیادہ مفہوم نہیں رکھتا تھا کہ خداوندعالم کا منشا یہ ہے کہ مسلمان لوگ ایسے معاشرہ اور حالات میں زندگی بسر کریں اور ہرگز اس معنی میں نہیں تھا کہ ایسے عہدوں کو حاصل کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ خاص دینی حیثیت کے حامل ہوں۔ البتہ یہاں پر گفتگواس طرح کے طرزفکر اور تصور سے ہے جو اس کے بارے میں مسلمانوں کے افکار تھے، نہ یہ کہ مثلاً پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اس کی تاکید اور بیان فرمایا تھا۔ اس زمانہ کی تبدیلیوں کو جاننے کے لئے خاص طور سے لازم ہے کہ اس فہم اور اس فکر کے وجود میں آنے کی کیفیت اور اس کی تاثیر کے بارے میں تحقیق اور اس کی چھان بین کی جائے۔(۵)
ہماری اس بات کی تصدیق کے لئے سب سے بہتر دلیل ابوبکر کا انتخاب اور اس کا مسند خلافت پر مستقر ہونے کی کیفیت ہے۔ اگرچہ اس کا انتخاب ایک مدت کے بعد خصوصاً حضرت علی ابن ابی طالب کے بیعت کرنے کے بعد عام طورپر مقبولیت پاگیا، لیکن شروعاتی دنوں میں اس کے انتخاب نے بہت بڑا جنجال کھڑا کردیا تھا۔ اس کے مخالفین ایک طرف انصار تھے جو مہاجروں کی حکومت کے آگے اپنی گردنیں جھکانے کے لئے تیار نہیں تھے(۶) اور دوسری طرف قریش تھے، ان میں سے سر فہرست ابوسفیان تھا، جو ابوبکر کے خاندان کو اس سے پست تر سمجھتے تھے کہ قریش کے اعلیٰ خاندانوں پر حکومت کرے لہٰذا وہ لوگ حضرت علی ـ اور پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے چچا عباس کی تلاش میں تھے کہ ان کو اپنا حاکم اور خلیفہ بنائیں ۔(۷) دوسرا گر بنی ہاشم اور حضرت علیـ کے ماننے والوں کا تھا جو آپ کے سچے دوست اور اپنی جانیں قربان کردینے والے تھے وہ البتہ یہ لوگ چند خالص دینی وجوہات کی بناپر اس کے انتخاب (سقیفہ بنی ساعدہ) کے مخالف تھے(۸) اور یہ ایک ایسا نیا واقعہ تھا جو مدینہ میں موجود تھا۔ مسلمانوں کے بہت سے خاندان جو مدینہ کے باہر رہتے تھے (مدینہ کے اندر کے) اس انتخاب کے مخالف تھے اور بعد میں ''اہل ردہ'' کے نام سے مشہور ہوگئے۔ اگرچہ ان قبائل میں سے بعض واقعاً مرتد ہوگئے اور اسلام سے اپنا منھ موڑ لیا تھا، لیکن ان میں سے بعض گروہ صرف ابوبکر کے منصب خلافت پر پہنچنے کے طریقہ، کیفیت اور اس کے انداز پر اعتراض کررہے تھے اور اس سے زیادہ مخالف نہیں تھے۔ اگرچہ بعد میں زمانہ اور تاریخ کی مصلحت اس بات کی متقاضی تھی کہ یہ لوگ بھی ارتداد سے متہم ہوجائیں۔(۹)
اس میں جو چیز بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ ابوبکر کے مخالفین اور موافقین کی ہنگامہ ساز اور جنجالی بحثیں ہیں۔ بجز ایک مختصر اقلیت کے جو حضرت علیـ کے ماننے والے تھے اور پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی سفارشوں اور خود حضرت علی ـ کی دینی شخصیت اور اس عہدہ کی لیاقت اور شائستگی اور اس عہدہ کے احراز کی خاطر اساساً اس عہدہ (امامت) کی اہمیت کی وجہ سے اس کے لئے زور دے رہے تھے، دوسروں کی گفتگو اس مدار کے علاوہ کسی دوسرے مدار کے اردگرد چکر کاٹ رہی تھی۔ بحث یہ نہیں تھی کہ پیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی جانشینی کس معنی اور کن خصوصیات اور حالات کی محتاج ہے اور کون اس کا حق دار ہے اور اس کے حصول کی لیاقت رکھتا ہے۔ ہر گروہ اپنے دلخواہ امیدوار ( Candidate ) کی طرفداری کررہا تھا۔دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ مسئلہ فقط سیاسی اور قبیلہ ای رقابت کی حدتک باقی رہ گیا تھا جس کی کوئی دینی حیثیت نہیں تھی، اتنی زیادہ پست ہوگئی تھی۔(۱۰)
جیساکہ ہم نے بیان کیا کہ صرف حضرت علی ابن ابی طالب اور آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم ہی کے چاہنے والوں کی مخالفت تھی جو دینی رنگ لئے ہوئے تھی، ان کی باتیں بعد میں آنے والے زمانہ میں خود آنحضرت کے ذریعہ بطور مبسوط و مفصل اور مزید صراحت کے ساتھ بیان ہو ئیں (خصوصاً آنحضرت کی خلافت کے زمانہ میں خطبۂ شقشقیہ ان نمونوں میں سے ایک ہے) وہ یہ تھا کہ اولاً تم لوگوں نے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے تاکیدی دستورات اور فرامین کو کیوں نظر انداز کردیا، دوسرے یہ کہ اس شائستہ مقام کی کچھ خصوصیات ہیں جو آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت( حضرت علی ـ) کے علاوہ کسی دوسرے شخص میں نہیں پائی جاتیں جو اس عہدہ کے لئے اولیٰ ہو۔ لہٰذا آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے علاوہ کسی اور میں اس منصب کو اپنے اختیار میں لینے کی کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔(۱۱)
آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت نے ابوبکر کے طرفداروں سے خطاب کرکے فرمایا: جو آپ سے اس لئے بیعت لینا چاہتے تھے فرمایا: ''خدا کے لئے! خدا کے لئے! اے مہاجرو!پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی قدرت و سلطنت کو ان کے گھر سے باہرمت لے جاؤ اور اسے اپنے گھروں میں مت لے جائو۔ اس کے اہل کو خلافت سے اور ہر وہ چیز جس کا وہ حق دار ہے، اس سے منع مت کرو۔ اے مہاجرو!خدا کی قسم ہم اہل بیت لوگوں کے مقابلہ میں اس (خلافت) کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اہل بیت ہیں اور ہم اس کے لئے تم سے زیادہ سزاوار ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنے والا (قرآن) اور خداوندعالم کے دین کا فقیہ، رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم کی سنت کا عالم اور رعایا کے امور سے آگاہ، برائیوں کا ختم کرنے والا اور ان کے درمیان برابر کا تقسیم کرنے والا ہمارے درمیان ہے؟ خدا کی قسم وہ شخص ہمارے درمیان ہے۔ اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ گمراہ ہوجاؤگے اور اس طرح حق سے دور ہوجاؤ گے''۔(۱۲)
خاندانی چپلقش
صرف یہ ایک ایسا کلام تھا جس کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ دوسرے لوگ بھی اپنے دفاع کے لئے منصب خلافت کے بارے میں، صلاحیت اور لیاقت کے علاوہ دوسری چیزوں کی نشان دہی کررہے تھے اور ان لوگوں میں خاندانی مقابلہ آرائی کا جذبہ بیدار ہوگیا تھا اور سبھی لوگ خاندانی برتری کا راگ الاپ رہے تھے اور اسی پر سارا زور صرف کررہے تھے۔ ایک طرف مہاجرین و انصار کے درمیان شدید رسہ کشی تھی اور دوسری طرف مہاجرین کے درمیان داخلی رسہ کشی موجود تھی ان میں کا ہر ایک کسی نہ کسی پرچم تلے چلا گیا تھا۔ بنی امیہ عثمان کے اردگرد اور بنی زہرہ عبدالرحمٰن ابن عوف کے اردگرد اور بنی ہاشم بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے اردگرد جمع ہوگئے تھے۔(۱۳) ابوسفیان ابوبکر کی خلافت سے راضی نہیں تھا، ایک مختصرجملہ کے ذیل میں اس زمانہ کے حالات و واقعات کی بخوبی تصویر کشی کرتا ہے: ''خدا کی قسم، میں گرد و خاک دیکھ رہا ہوں (گرد و خاک سے اشارہ یہ ہے کہ جنگ اور حملہ کے وقت گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو گرد و خاک بلند ہوتی ہے) جس کو خون کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بٹھا سکتی ہے۔ اے عبد مناف کی اولادو! ابوبکر کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ تمہارے مقدر کو اپنے ہاتھوں میں لے؟ کہاں ہیں وہ دو شخص جن کو مستضعف ذلیل بنا دیا گیا ہے؟ کہاں ہیں علیـ و عباس؟''(۱۴) بہرحال اس زمانہ میں ایسے حالات تھے کہ حضرت علیـ کی مخالفت حضرت زہرا کی مخالفت کے تحت الشعاع قرار پاگئی تھی۔ کیونکہ حضرت علی ابن ابی طالب اگر مخالفت پر زیادہ اصرار کرتے تو آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو قتل کردیا جاتا(جیساکہ صراحت کے ساتھ مخالفین نے آپ سے کہا کہ اگر مخالفت کرو گے تو قتل کردیئے جاؤ گے) لیکن حضرت فاطمہ زہرا کو خصوصی موقعیت حاصل تھی، آپ کا تعلق صنف نسواں سے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی تنہا یادگار تھیں یہ موقعیت حضرت امیرا لمؤمنین علی بن ابی طالب کی ایک طرح سے حفاظت کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زہرا کی شہادت کے بعد حضرت علی ـ نے ظاہراً اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیئے اور آپ کی اتباع میں بنی ہاشم اور آپ کے خاص اصحاب نے بھی آنحضرت کی تأسّی کی۔(۱۵)
یہ وہ حالات تھے کہ اسی دوران میں ا بوبکر کی خلافت مستقر ہوگئی۔ اس انتخاب کی کیفیت اور ان بیانات کی حقیقت جو اس (بیعت) کی تائید اور تکذیب میں دیئے گئے وہ خلافت کے بارے میں اس زمانہ کے مسلمانوں کی ذہنیت کا پتہ دیتے ہیں۔ اگرچہ ابوبکر کی شخصیت جانی پہچانی ہوئی تھی، لیکن وہ چیز جس نے اس کی موقعیت کو اس کی برقراری تک پہونچادیا، وہ ان کی ذاتی خصوصیات اور دینی حیثیت اور مقام و منزلت نہیںتھی، جس کے متعلق بعد میں مختلف افکار کی بناپر بہت زیادہ شاخسانے ان کے بارے میں بیان کر دیئے گئے اور ان صفات اور مقام و منزلت کو اس کے لئے جعل کر دیا گیا، بلکہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی جانشینی کے بارے میں مسلمانوں کا بہت ہی سادہ اور معمولی تصور تھا۔ مسلمانوں کی نظر میں یہ منصب ہر قسم کی دینی حیثیت اور اس کی بلند مرتبہ برتری و بزرگی سے خالی تھا۔(۱۶)
البتہ اس میں دوسرے اسباب و عوامل بھی دخیل تھے جو شاید ان میں سے سب سے اہمیت کے حامل تھے وہ ایسے خطرات تھے جو مدینہ کے باہر سے اپنے دانت تیز کرہے تھے۔ ان میں سے اہل ردہ کی طرف سے بغاوتیں اور عربستان کے مرکزی و جنوبی علاقوں میں رہنے والے قبائل کے درمیان ایک حدتک دھمکی محسوب ہوتی تھیں یہاں تک کہ باہمی کشمکش نے خود مدینہ کو بھی حتمی طورپر سنجیدہ دھمکیوں کی زد پر لئے ہوئے تھا (یہاں پر اہل ردہ سے مراد وہ لوگ ہیںجن لوگوں نے واقعاً اسلام سے منھ موڑ لیا تھا اور یہاں تک کہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرلیا تھا اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ابوبکر کی خلافت قبول نہ کرنے کی بناپر وہ لوگ اس نام سے مشہور ہوگئے۔) اور دوسرا خطرہ روم اور ایران کا خطرہ تھا ان میں سے پہلا یعنی ''روم'' کا خطرہ ہولناک ،بہت زیادہ سنجیدہ اور حتمی تھا مجموعی طور پر یہ تمام امور اس بات کا باعث ہوئے لوگوں کی عام کہ نگاہیں مدینہ کے باہر کی طرف مرکوز ہوجائیں اور اندرونی اختلافات کو کم از کم' وقتی طور'پر بھلا دیا جائے اور ایسی صورت میں مسلمانوں کا تمام ہم و غم اور ذکر و فکر فقط اپنی موجودیت کا دفاع باقی رہ جائے۔ اس زمانہ کے آشفتہ اور بیم و ہراس سے بھرے ہوئے اس زمانہ کے حالات کو واضح کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ فقط مرتدین (مرتد ہوجانے والوں) کو پسپاکرنے کے لئے بارہ سو مسلمان جن میں زیادہ تر تعداد قاریان قرآن اور حفاظ کی تھی وہ سب کے سب قتل کردیئے گئے۔(۱۷) اس وقت کے مدینہ کی محدود آبادی اور تمام مسلمانوں کی آبادی کا لحاظ کرتے ہوئے قتل ہونے والوں کی اس تعداد سے اس زمانہ کے کشیدہ اور پریشان کُن حالات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔(۱۹)
ابوبکر کی خلافت کے زمانہ میں اہل ردہ کی بغاوت کو کچل دیا گیا اور حجاز (سعودی عر بیہ) کے حالات میں بہتری ہونے لگی۔ لیکن بیرونی خطرات اسی طرح اپنی شدت کے ساتھ باقی رہے اور مسلمانوں کو فکرمند اور پریشان کئے ہوئے تھے خصوصاً وہ لوگ جو علاقہ میں اس زمانہ کی دو بڑی طاقتوں کے مزدور شاہی نوکر جو مسلمانوں کے ہمسایہ تھے اور ہر لمحہ ان کے حملہ کا امکان تھا۔(۲۰)
ان سب باتوں کے قطع نظر پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنی آخری ایام میں لشکر کو رومیوں کے خلاف جنگ کے لئے اسامہ ابن زید کی سرداری میں مستعد کردیا تھا۔ اگرچہ ظن غالب کے طور پر، اس سے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کا اصلی مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو مدینہ سے دور رکھا جائے جن کے بارے میں اس بات کا امکان تھا کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد خلافت و امامت کے بارے میں آپ کی وصیت سے منحرف کرنے کے لئے میدان کو ہموار کریں گے، لیکن بہرحال رومیوں کی جانب سے خطرہ حتیٰ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کو د ھمکی دے رہا تھا ابوبکر نے 'اہل ردہ' سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسامہ کی سرداری میں ایک لشکر کو رومیوں سے جنگ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ البتہ یہ واقعہ، جس کا خود انھوں نے اظہار کیا ہے، زیادہ تر پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی پیروی اورتأسّی میں تھا نہ کہ خطرہ کو برطرف کرنے کے سبب ا ایسا کیا۔اگرچہ ایسا خطرہ بھی لاحق تھا جس نے مسلمانوں کو فکرمند کر رکھا تھا۔(۲۱)
عمر کی سیاسی جد و جہد
ابھی ایسے ہی حالات تھے کہ ابوبکر کا انتقال ہوگیا۔ ان کی وصیت کے مطابق عمر خلیفہ بن گیا۔ بالکل انھیں وجوہات کی بنیاد پر جیسے ان کے پہلے والوں نے خلافت حاصل کی تھی ویسے ہی انھوں نے بھی خلافت حاصل کرلی۔ لوگوں کی توقع یہ تھی کہ وہ ان کے دنیاوی امور کو اپنے ذمہ لے لیگا، اس سے زیادہ اور کوئی توقع نہ تھی اور عمر اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنے کے لئے میدان میں اُتر آئے اور اس طرح وہ (خلافت کے لئے) قبول کر لئے گئے۔ ان کی پر سکون اندازاور بڑی ہی خاموشی سے اس کے قبول کرلیئے جانے کے متعدد اسباب تھے۔ ان میں سے بعض اسباب اس زمانہ کے حالات اور ابوبکر کی جانشینی کے تجربہ کی طرف اور بعض اسباب اس کی شخصیت اور ذاتی خصوصیات سے وابستہ ہیں۔(۲۲) پھر بھی اس مقام پر بھی (خلیفہ اور خلافت کی) اس کی دینی شان اور حیثیت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اگرچہ بعد میں اس (دینی فضیلت)کے بارے میں بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کی گئیں۔ نہ تو وہ اپنے واسطے کسی دینی مقام اور حیثیت کے قائل تھے اور نہ ہی اس کو ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کا سہارا لیا۔ نہ ہی اس زمانہ کے عام لوگ اس کے لیئے کسی دینی حیثیت اور شان کے قائل تھے اور نہ ہی اس کا مسند خلافت پر آنا ان خصوصیات کے سبب وجود میں آیا تھا۔ اگرچہ عمر زیادہ تر دینی اور دنیاوی امتیازات جو اس کے حکومت کے لئے ضروری تھے ان سے (ایسی دنیا کہ ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے حاصل بناپر حاصل کرسکتا ہے) بہرہ مند تھا۔ لیکن پھر بھی اس کا دینی فضیلت اور شان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ امتیازات جو اسے حاصل تھے وہ حکومتی منصب پر ہونے کی بناپر وجود میں آئے تھے اور نہ یہ کہ وہ خود حاکم کی ذاتی دینی صلاحیتوں سے متعلق تھے۔ بیشک اقتدار حاصل کرنے میں خود عمر کی ذاتی خصوصیات اور اس کی بقا کے لئے قدرت مندانہ کردار دینی مقام و منزلت سے کہیں زیادہ مؤثر تھا۔(۲۳)
حقیقتاً عمر کے خلافت قبول کرنے کا وہی انداز تھا جو ابوبکر کی خلافت کے قبول کرنے میں اختیار کیا کیا تھا اور اس کو بھی قانونی حیثیت دینے میں بھی ابوبکر کی ہی روش کا نتیجہ تھا چاہے جتنا ابوبکر کا خلافت کے لئے انتخاب کیا گیا ہو اور عمر کی خلافت ان کی وصیت کا ہی نتیجہ تھی۔ لیکن اہمیت کا حامل یہ ہے کہ جس وقت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی جانشینی کے لئے ابوبکر کے انتخاب کا موضوع اس طرح پیش کیا گیاکہ عمر کی خلافت کا راستہ کھلا چھوڑ دیا۔ اس سے قطع نظر ابوبکر کا خلیفہ بننا حقیقت میں تین آدمیوں کا خلافت تک پہونچنا تھا جن میں ابوبکر سرفہرست قرار پائے۔اور بقیہ دو افراد میں ایک عمر تھے اور دوسرے ابوعبیدہ جراح تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمر اپنے عمر کے آخری وقت میں چاہ رہے تھے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کریں، اس مقام پر کف افسوس مل رہے تھے کہ ابوعبیدہ کیوں زندہ نہیں رہ گئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انھیں کو یہ منصب سونپ دیتا۔(۲۴)
البتہ اس کی شخصی خصوصیات کو بھی اس بارے میں کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو عربوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا اور اُسے یہ معلوم تھا کہ ان کی کس طرح رہبری کرے۔ جیساکہ وہ ضرورتوں اور اضطرار کی اچھی طرح تشخیص دے لیتا تھا۔ جبکہ وہ خلافت پر بٹھائے گئے تو لوگوں سے اس طرح خطاب کرکے کہا: '' عرب کی مثال اس سدھائے ہوئے اونٹ اور گھوڑے کی ہے جو اپنے راہنما کا اتباع کرتی ہے۔ اور راہنما اس کو جس طرف لے جانا چاہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں جس طرف لیجانا چاہوں گا، اس طرف تم کو لے جاؤں گا۔''(۲۵)
اہم ترین بات یہ کہ وہ ٹھیک اسی زمانے میں میدان (خلافت) میں آئے کہ اس زمانہ کا معاشرہ اس کے جیسے خصوصیات کے مالک شخص کا ضرورت مند تھا ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ اس زمانے سے پہلے یا بعد میں جب انھوں نے خلافت کو سنبھالا، اقتدار کو حاصل کیا ہوتا تو، یا تو شکست کھا جاتے یا پھر کم از کم ایسے مقام و منزلت کو حاصل نہ کرپاتے۔ ان کی خوش قسمتی اس میں تھی کہ بہت ہی مناسب وقت میں بروئے کار آئے اور ایسے زمانہ میں زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ اس(عمر) کے زمانہ کی طبیعت اس کی فکری اور اخلاقی خصوصیات، نفسیات اس کے مطابق اور اس سے ہماہنگ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جس طرز کی حکومت اس نے کی تھی، اس کے علاوہ کسی اور طرز پر حکومت کرتے۔ حضرت عمر کی حکومت ان کی خصلتوں اور خصوصیات کے تحقق پانے کا فطری نتیجہ تھا۔ یہ ان کی طبیعت تھی جواپنے زمانہ کی روح کے ساتھ سازگار اور ہماہنگ تھی اس لحاظ سے کہ ان کی سیاست اسی طبیعت کی مخلوق تھی لہٰذا زمانہ کی ضرورتوں سے مطابقت رکھتی تھی۔ ان کی تند خوئی اور سخت گیری کی روح نے سیاسی مظاہرہ کے واسطے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی اور حقیقتاً اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ نہ اس زمانہ کے مسلمانوں کامعاشرہ اس بات کا ضرورت مند تھااور نہ ہی اس زمانہ کے عربوں کو ایسی روش اچھی لگتی تھی۔ خلیفہ بھی اخلاقی اور نفسیاتی لحاظ سے اس زمانہ کے عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان تھا اور یہی ان کی کامیابی کی کنجی (کلید) تھی۔(۲۶)
بیرونی دھمکیاں
البتہ اس مقام پر بھی ابھی باہری دھمکیوں کے خطرات کے بادل پہلے ہی کی طرح منڈلا رہے تھے اور شاید ایک طرح سے اس سے زیادہ سخت اور زیادہ دھمکی آمیز تھے۔ اگرچہ حجاز کے اندر کوئی اس سے ٹکر لینے والا موجود نہ تھا مگر اس زمانے میں روم اور ایران دونوں ہی دین اور نظام نو کی روزافزوں قدرت بڑھنے کے متعلق زیادہ حساس ہوگئے تھے اور اس درمیان ایران کچھ زیادہ ہی حساسیت دکھا رہا تھا اور مسلمان لوگ واقعاً ان دھمکیوں سے متأثر ہوگئے تھے۔
فطری طورپر ایسے حالات میں ان خطرات کو اپنے سے دفع کرنے کے علاوہ عمومی افکار کسی اور چیز پر مرکوز نہیں تھی۔ پھر بھی نگاہیں اندرون ملک سے سرحد سے باہر کی طرف مرکوز ہوگئی تھیں اور اندرونی کشمکش و اختلافات سے نپٹنے اور اس کے تعاقب کی بھی فرصت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ خطرات اس قدر قطعی اور حتمی تھے کہ عمر نے متعدد بار مصمم ارادہ کیا کہ اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھانے کے لئے ایران کے جنگی محاذ پر جائے کہ ہر بار حضرت علیـ نے ان کو اس اقدام سے روک دیا۔ ان سب سے قطع نظر ایران اور روم سے مسلمانوں کی جنگ صرف خطرہ کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے تھی جو خطرے ایرانیوں اور رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کو لاحق تھے جن کو اس زمانہ میں عموماً اُن کی جانب سے محسوس کئے جارہے تھے نہ کہ فتح اور ملک گیری کے لئے اور یہ احساس وہمی اور خیالی نہیں تھا بلکہ حقیقی تھا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اس سے کہیں زیادہ کمزور محسوس کررہے تھے کہ اتنی بڑی طاقتوں کے مدمقابل اُٹھ کھڑے ہوں، چہ جائیکہ ان پر فتح اور کامیابی حاصل کرلیں۔ خاص طورپر ایرانی اور رومی بادشاہوں کی گوش مالی کی داستان خاص طورپر ساسانی بادشاہوں اور ان کے داخلی کٹھ پتلی حکام (کی گوشمالیوں کی داستان) ابھی تک ان کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں کو خیرہ کردینے والی شان و شوکت پر مسلمان لوگ اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اس زمانہ کی تاریخی سندوں کی جانچ پڑتال اور گہرے مطالعہ اور شک و تردیدجو ایسے اقدام کے لئے موجود وہ سب باتیں اس آخری نکتہ کو بخوبی بیان کرتی ہیں۔(۲۷)
ان لوگوں اور ان کے پڑوسیوں کے درمیان پہلا فوجی مقابلہ محدود پیمانہ پر تھا۔ لیکن یہ اس خاصیت کا حامل تھا کہ اس فوجی مقابلہ کے ذریعہ انھوں (مسلمانوں) نے اپنے مخالفین کے اندرونی نظام کی سستی اور کمزوری کو محسوس کرلیا اور جو چیزیں اس واقعہ میں مدد کرتی تھیں، وہ بعض مقامی فوجی سرداروں کی جنگ طلبی تھی جولوگ اس جنگ کو جاری رکھنے پر مائل تھے اور درحقیقت خلیفہ دوم کو بھی انھوں نے ہی ایران و روم کے خلاف پوری آمادگی کے ساتھ جنگ کے لئے اکسایا، روم کو بھی تشویق کیابلکہ اس کام کے لئے انھیں بھڑکایا۔ لیکن ان (عمر) کو اور بہت سے مسلمانوں کو فتح و کامرانی کے آخری لمحات تک شکست فاش کا اندیشہ لاحق تھا۔(۲۸)
یہ حقیقت عمر کے زمانۂ خلافت کے نصف اول تک برقرار تھی، جو کچھ بعض لوگوں نے ان (عمر) کے مستحکم ارادہ اور ایران و روم سے جنگ و جہاد سے متعلق تمام مسلمانوں کے بارے میں تحریر کیا ہے اکثر اپنے فاتح افراد کی شان و شوکت اور قدرت اور دلیری کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔حقیقت یہ ہے کہ حالات بدل گئے تھے اگرچہ مدائن اور بیت المقدس کی فتح کے بعد ورق پلٹ گیا یعنی حالات تبدیل ہوگئے اور شک و شبہہ اور اندیشہ ختم ہوگیا اور اس کے بعد ان دونوں طاقتوں سے بے خوف و خطر ترقی کے راستہ پر لگ گئے۔ البتہ عمر کی خلافت کے نصف دوم میں حالات بالکل بدل گئے، اس لئے کہ مدائن اور بیت المقدس کو فتح کیا جاچکا تھا اور ایران اور مشرقی روم کی شہنشاہیت کا خاتمہ ہوچکا تھا۔ دینی جوش و جذبہ اور امنگیں اور سماجی جوش و ولولہ روبزوال تھا۔
اس مقام پر لازم ہے کثیر مال غنیمت کا تذکرہ کیا جائے جس کو عربوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کثیر مال و دولت اور بہت سارے اسیروں کی کثرت عین اس عالم میں کہ وہ لوگ مترقی تہذیب و تمدن کے مالک تھے، ناگاہ سعودی عرب کے وسیع اور بدوی معاشرہ میں وارد ہوئے اور انہوں نے تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لیا۔ اگرچہ اتنی کثرت سے مال غنیمت کے ورود کے آثار بعد میں زمانۂ عثمان میں اس کے اثرات ظاہر ہوئے لیکن عمر کے زمانہ خلافت کا آخری نصف حصہ بھی ان دھماکوں کے نتائج سے محفوظ نہ رہ سکا۔ عمر کی سختی اور اس کی ہیبت کے باوجود، بہت سے حوادث کو عمر کی خلافت کے آخری دور میں پتہ لگایا جاسکتا ہے جو ان ناراضگیوں کی حکایت کررہا تھا ان انقلابات اور تبدیلیوں کے سبب وجود میں آئے تھے اور اس نے ان کے مقابلہ میں سخت ردعمل کا مظاہرہ کیا تھا۔(۲۹)
وہ اپنے اقتدار کے بہترین زمانے میں قتل کردیئے گئے ۔اگر ان کی خلافت زیادہ مدت تک رہتی تو سریع اور تیز تبدیلی پر توجہ کرتے ہوئے جو رونما ہوئے تو ان کا نفوذ اور ان کی قدرت کم ہوجاتی تو پھر ایسی ممتاز اور شجاعانہ موقعیت جس کے کئے بعد میں اہل سنت قائل ہوگئے ہیں، اسے حاصل نہیں کرسکتے تھے۔
عمر نے جن بہت زیادہ مختلف حالات میں قدرت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا ان حالات میں انہوں نے اس کو خیرباد کہہ دیا۔ ان حالات میں معاشرہ بسیط، مسد ود اور آنکھیں بند تھیں بیرونی دھمکیوں نے آپسی چپلقش، رسہ کشی اور مخالفتوں کو بروئے کار لانے کے لئے مجال باقی نہیں رہ گئی تھی، لیکن اس زمانہ میں نہ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا اور نہ ہی ویسی دھمکیاں تھیں۔ مسلمان لوگ بھی مالدار ہوگئے تھے اور اسی طرح قدرت بھی ایک بڑی شہنشاہیت میں تبدیل ہوگئی تھی اور ایک دوسری دنیا کا تجربہ کررہے تھے۔(۳۰)
یہ تبدیلیاں اور انقلابات بہت زیادہ مئوثر واقع ہوئے تھے اس دوران خاص طورپر معاشرہ کی شخصیات جو اکثر خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، ان پر اس کا زیادہ اثر پڑا۔ عمر اپنی خلافت کے آخری ایام میں ان کا شکوہ کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے خداوندعالم سے اپنی موت کی دعا کرتے تھے۔ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں سے انہوں نے یوں خطاب کیا: ''میں نے یہ سنا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے جدا کرلیا ہے اور اپنی خاص نشستیں برپا کرتے ہو یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کے اصحاب میں اور ان کے ہم نشینوں میں سے ہے۔ خدا کی قسم یہ نہ تو تمہارے ذاتی فائدہ میں ہے اور نہ ہی تمہارے دین و عزت و شرف کے فائدہ میں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعد میں آنے والی نسلیں یہ کہتی دکھائی دیں گی کہ یہ فلاں شخص کی رائے ہے اور اس طرح اسلام کو تقسیم کرکے متفرق کردیں گے۔ تم لوگ جمع ہوکر ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر بیٹھو جو تمہاری الفت اور دوستی کے لئے مفید ہے اور تم لوگوں کو لوگوں کے درمیان مزید مقتدر اور با شکوہ بنادے گی۔ اے خدا!انہوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے اور میں نے بھی ان کو مضطرب کردیا ہے۔ وہ مجھ سے عاجز آگئے ہیں اور میں ان سے عاجز ہوں اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون پہلے خاک کی نقاب اوڑھ لے گا یعنی اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک شخص زمام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے گا۔ اے میرے خدا! تو مجھے اپنے پاس بلالے۔''(۳۱)
ایک نئی موقعیت
عمر اپنی آخری عمر میں ایسی مشکلات سے دست و گریباں تھے ۔ ان کا نفوذ اور اثر گھٹ گیا تھا اور یہ صرف اس کی ذات سے متعلق نہیں تھا جو نئی موقعیت کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ معاشرہ بالکل بدل گیا تھا اور یہ تبدیلی اپنے ساتھ بہت سی توقعات و ناراضگیوں کو وجود میں لائی تھی اور وہ (عمر) ان سب چیزوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا اور ان کو تحمل بھی نہیں کرسکتا تھا۔ آخری مرتبہ جب وہ سفر حج سے واپس ہوا تو لوگوں کو خطاب کرکے اس طرح کہا:'' مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ فلاں شخص (اس سے مراد عبد الرحمن ابن عوف تھے) نے کہا ہے کہ اگر عمر مرجائے تو میں فلاں شخص کی بیعت کرلوں گا...، ہرگز کوئی شخص اس بات پر کہ (ابوبکر کی بیعت اس کے باوجود کہ ناگہانی اور بغیر سوچے سمجھے انجام پائی ، لیکن تشکیل پاگئی اور وہ کامیاب بھی ہوگیا) دھوکہ میں نہ آجائے۔ ہاں ان کی بیعت ایسی ہی تھی، لیکن خداوندعالم نے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچالیا۔ لیکن تمہارے درمیان کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی اطاعت کے لئے سب لوگ اپنا سر جھکادیں...''(۳۲)
ہماری اس بات کا بہترین شاہد عمر کی وصیت کی وہ کیفیت ہے جس کا قیاس اپنے سلف (ابوبکر) کے مقابلہ میں کیا ہے۔ ابوبکر نے عمر کو معین کیا اور وہ قبول بھی کرلیا گیا، لیکن عمر نے ایسا نہ کیا اور وہ ایسا کربھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ ابوبکر معاشرہ پر تنہا اور مطلق العنان حکومت کرتے تھے اور وہ بڑے ہی سکون کے ساتھ اپنی باتیں کہنے پر قادر تھے اور دوسرے لوگ بھی ان کی باتوں کو قبول کرلیتے تھے۔ اس لئے نہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے بلکہ وہ لوگ بھی اتنے ہی فکر مند تھے کہ وہ بھی اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں قدرت کا اختیار میں لینا کسی امتیاز اور مقام و منزلت کا حامل نہیں تھا۔ خلیفہ بھی دوسرے افراد کی طرح ایک فرد شمار کیا جاتا تھا۔ جو شخص بھی کوئی کام یا ذمہ داری سنبھالتا وہ بھی خلیفہ ہو جاتا۔ مزید یہ کہ فقیر اور محدود معاشرہ میں مثال کے طورپر ابوبکر کی حکومت کے زمانہ کا معاشرہ جس میں حاکم بھی کسی مادی امتیاز کا حامل نہیں تھا۔ (یعنی معاشرہ کی اقتصادی حالت بہت ہی خراب تھی) لہٰذا اقتدار کی جنگ نہیں تھی اور جنگ کے حالات بھی فراہم نہیں تھے۔
لیکن عمر کے مرنے کے وقت کی داستان کچھ اس طرح تھی کہ نہ ہی وہ خطرات تھے اورنہ ہی وہ محدودیت تھی اور نہ ہی فقرو تنگ دستی کا غلبہ۔ یہ بات فطری تھی کہ بااثر افراد اور مختلف گروہ قدرت پر قبضہ جمانے کے لئے ایک دوسرے کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ ابھی بھی خلیفہ ہونے کے اعتبار سے اس کا کوئی خاص مقام نہیں تھا، لیکن ان مقام کو حاصل کرتے ہی وہ ایسی موقعیت کا حامل ہوجاتا تھا کہ اگر وہ چاہے تو بہت سی نعمتوں کا حامل اورہو مالک جائے، لہٰذا اس کی طرف لوگ اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے۔(۳۳)
اور یہ کہ عمر نے اپنے سے پہلے والے خلیفہ کے برخلاف کسی خاص فرد کے بارے میں وصیت نہیں کی غالباً یہ بھی اسی حقیقت کی پیداوار تھی۔ ورنہ نہ تو وہ ابوبکر سے کمزور تھے اور نہ ہی ان سے کلامی اعتبار سے نفوذ کم تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حالات اس کے حق میں مساعد نہیں تھے اور اس نے اپنی ذاتی فراست اور ہوشمندی کے ذریعہ ان تبدیلیوں کا پتہ لگالیا تھا۔ لہٰذا وہ مجبور ہو گیا کہ وہ مخصوص انداز کی وصیت کریں۔ اور ایسی وصیت جس کی کسی شخص نے تقلید نہیں کی شاید ایسا ہوبھی نہیں سکتا تھا؛(۳۴) اس کے باوجود کہ وہ اپنے پیرو اور طرفداروں کے نزدیک ایسی مقتدر شخصیت کے حامل تھے اسی بناپر انہوں نے مختلف مواقع پر ان کی تقلید کی کوششیں کیں۔
عمر کے فرزند، عبد اللہ اپنے باپ کی وصیت کی داستان کو اس طرح نقل کرتے ہیں: ''عمر ابن خطاب کی موت کے وقت، عثمان و علی، عبدالرحمن و زبیر اور سعد وقاص ان کے نزدیک آئے اور طلحہ اس وقت عراق میں تھے۔ اس نے کچھ دیر ان لوگوں پر نگاہ کی اور اس کے بعد کہا: میں نے تم لوگوں پر تمہاری حکومت کے بارے میں غور و فکر کیا۔ ان لوگوں میں کوئی فرق نہیںپایا جاتا ہے سوائے وہ اختلاف جو تمہارے درمیان پایا جاتا ہے۔ پس اگر کوئی رخنہ اور اختلاف تمہارے درمیان پایا جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف سے ہے۔ حکومت چھ لوگوں کی طرف پلٹتی ہے۔ عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، طلحہ ا ور قوم سعد پر لازم ہے کہ تم تین لوگوں میں سے کسی ایک کو (خلافت کے لئے) چُن لیں، پس اے عثمان! اگر اقتدار تمہارے ہاتھ میں گیا، تو خاندان ابی معیط، کو لوگوں پر مسلط نہ کرنا۔ اور اے عبدالرحمن! اگر حکومت تمہارے ہاتھ میں آجائے تو اپنے عزیز و اقارب کو لوگوں پر مسلط نہ کرنا ۔ اگر اے علی! تمہارے ہاتھوں میں یہ اقتدار آجائے تو بنی ہاشم کو عوام پر مسلط نہ کرنا۔ اس کے بعد کہا تم لوگ اُٹھو اور آپس میں مشورہ میں مشغول ہوجاؤ اور آپس میں ایک شخص کو منتخب کرلو۔ پس سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنا شروع کردیا...''(۳۵)
یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کررہی تھیں کہ حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ مدعیان خلافت بھی بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس کے خواستگار تھے اور ان کے ماننے والے بھی ان کے دفاع میں اپنے منافع دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ یہ تمام مشکلات جس وقت عمر خلیفہ بنے اس وقت بھی موجود تھیں لیکن نہ تو اس حدتک تھیںاور نہ ہی اتنی زیادہ فیصلہ کن اور خطرناک تھیں۔
منقول ہے کہ حضرت علیـ نے عبدالرحمن ابن عوف کی اس بات کو جس میں ان سے چاہا جارہا تھا کہ وہ منصب خلافت پانے کے بعد شیخین کی سیرت پر عمل کریں، اُسے رد کردیا اور فرمایا: ''زمانہ بدل گیا ہے۔''(۳۶) اگر یہ روایت ضعیف اور جعلی بھی ہو تب بھی کم از کم اس زمانے کے ناگفتہ بہ اور بگڑتے ہوئے حالات کی نشان دہی کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر جعلی چیز کچھ نہ کچھ حقیقت کو اپنے اندر سموئے رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تا تو پھر وہ مشتبہ نہیں کہی جائے گی۔
عثمان کا اقتدار حاصل کرنا
آخرکار عثمان کو حکومت مل ہی گئی اس کی کامیابی خود اس کی ذاتی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایسی پارٹی کی کامیابی تھی جن لوگوں نے اس کو آگے کیا تھا اس لئے کہ وہ عمر کی معین کردہ ان چھ اشخاص پر مستمل کمیٹی میں کمزور اور نہایت بے لیاقت انسان تھا ۔ عثمان کی کمزوری اور بے لیاقتی کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ بعض ان وجوہات اور دلائل کے سبب جن کو خلفا اور خود عثمان کے فضائل کے ذیل میں بعد میںگڑھ دیا گیا ہے جیساکہ ہم نے ان کو پہلے بھی ذکر کیا ہے اور بعد میں بھی ذکر کریں گے کہ یہ سب فضائل جعلی ہیں، ان میں سے ایک بھی فضیلت ان کی ذاتی صلاحیت اور لیاقت کی طرف نہیں پلٹتی وہ تمام فضیلتیں نبی اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے نسبت کی بناپر اس سے تعلق ہیں یا اس کی روحی اور نفسانی حالات سے متعلق ہیں۔(۳۷)
اگرچہ عثمان ایک بے لیاقت اور کمزور شخص تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حالات یہاں تک کہ وہ چیزیں جو ان کی قدرت اور ان کی لیاقت سے بھی متعلق نہیں تھیں، وہ بھی ان کی لیاقت میں تبدیل ہوگئیں تھیں۔ باہری خطرہ کے نہ ہونے کے سبب اور بغیر زحمت کے کثرت سے مال و دولت کا آجانا اور ایک پچھڑے معاشرہ کے عواقب اور نتائج بہت زیادہ تھے وہ بھی ایک ایسا قبیلہ جو اپنے قبیلہ کے اندر آپس میں لڑنے میں مشہور تھاس اختلاف کی بناپر غمزدہ تھا ایک ایسی پارٹی اور اس کے بڑھتے ہوئے نفود اور اثرات جس کا نمائندہ خود خلیفہ تھا بلکہ وہ اس پارٹی کا بازیچہ تھا اور وہ اپنی ذاتی مصلحتوں کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا تھا۔ ایسی ایک طاقتور اور مقتدر مرکزیت کا فقدان اور اسی طرح سب کے لئے قبول اور قابل احترم نہ ہونا، خود غرضی، خود خواہی و خودپسندی اور ریاستوں کے حکام کے بارے میں لاپرواہی برتنے نے، مزید حالات کو پیچیدہ اور دشوار بنادیا تھا۔ خود خلیفہ کی کمزوری نے بھی پیچیدہ اور دشوار حالات پیدا کردیئے تھے اور خلیفہ کی کمزوری اس کو مزید بڑھارہی تھی یعنی آگ میں تیل کا کام کر رہی تھی۔ کیونکہ خلافت کے تمام دعویدار ایسے وقت میں اپنی لالچی نظریں جمائے ہوئے تھے، اس کے متعلق خود اپنے آپ کو بدرجہ ہا لائق و سزاوار اور حق دار جانتے تھے۔ حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے تھے کہ عوام کی اکثریت بھی اس سے تنگ آگئی تھی اور اپنے لگاتار اور پے در پے اعتراضات کے بعد چند مرتبہ مدینہ آئے اور علانیہ طور پر خلیفہ پر اعتراض کیا جو اثر انداز نہ ہوئے یہاں تک کہ آخرکار ان کو قتل کر ڈالا گیا۔
اس مقام پر یہ مناسب ہے کہ یہاں ابن خلدون کے کچھ بیانات کا ذکر کریں جو انھیں انقلابی حالات اور اس تبدیلی سے متعلق ہیں، ۔صدر اسلام کی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لئے اس کے نظریات سے واقفیت خاص طور سے عمر کی خلافت کا نصف آخر اور اس کے بعد کا دور بالاخص خلافت عثمان کا زمانہ اور حضرت امیرا لمؤمنین امام علی ـ کے ایام خلافت کے بارے میں جاننے میں ایک اچھی خاصی مدد کرے گا لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ ان کے بیان کے طولانی ہونے کے باوجود اس میں سے کچھ اہم حصوں کا بیان کریں۔
عمیق اور تیز بدلاؤ
''...اس اعتبار سے تمام قوموں سے زیادہ دنیاوی امور اور اس کے نازو نعمت سے دور تھے۔ چاہے ان کے دین کی رو سے ہو کہ ان کو دنیاوی نعمتوں سے پرہیز کی دعوت دیا کرتا تھا اور چاہے بادیہ نشینی اور ان کے رہنے کی جگہ کے اعتبار سے ہو اور معیشت کی سختی، دشواری اور تنگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے اوراسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کی وجہ سے ہو۔ جیساکہ قبیلۂ مضر کھانے پینے کے اعتبار سے دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ معیشت کی تنگی اور غذاکے اعتبار سے سب سے زیادہ پریشان حال تھے چاہے وہ لوگ جو حجاز میں رہتے تھے کہ وہ سرزمین کھیتی باڑی اور حیوانات کے پالنے کے اعتبار سے بالکل خالی تھی اور آباد اور کھیتی باڑی والے علاقے اور اس کی زمین کے دوسرے محصولات گھروں اور جائے وقوع کے دور ہونے کے سبب ا ن تمام نعمتوں تک ان رسائی نہیں تھی۔ ان موارد کے علاوہ ایسے علا قوں کے محصولات ان قبیلوں سے مخصوص تھے جو کورہ علا قوں کو اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے، مثال کے طورپر ربیعہ اور یمن کے قبیلہ۔ اسی وجہ سے کبھی بھی ان آباد سرزمینوں کی فراوان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے ۔اور عموماً ان نعمتوں کو بچھو اور خبزدوک (یعنی گندے اور بدبودار جانور )کھا جایا کرتے تھیاور عِلْہَز کے کھانے پر فخر کیا کرتے تھے اور وہ اونٹ کا بال ہے جس کو پتھر کے اوپر خون میں لت پت کرکے پکاتے ہیں۔ قریش کی بھی حالت مکان اور کھانے کے اعتبار سے قبیلہ مضر، سے ایک طر ح سے نزدیک تھا یہاں تک کہ عرب کی عصبیت متحد ہوکر ایک دین کے پرچم تلے آگئی ۔کیونکہ خداوندعالم نے ان لوگوں (عربوں) کو حضرت محمد مصطفیصلىاللهعليهوآلهوسلم کی نبوت سے سرفراز کیا۔ اسی وجہ سے ایران اور روم پر لشکر کشی کی اور ان سرزمینوں کو جسے خداوندعالم نے اپنے سچے وعدہ کے مطابق ان کے لئے مہیا کردیا تھا، انہوں نے اس کا مطالبہ کیا اور سلطنت کو بزور بازو حاصل کرلیا اور اپنے دنیاوی امور کے لئے اقدام کردیا۔ نتیجہ خوشحالی اور توانگری کے ایک وسیع و عریض ٹھاٹھیں مارتے سمندر کو حاصل کرلیا؛ اس قدر کہ بعض جنگوں میں ایک گھڑ سوار کا حصہ تیس ہزار سونے کے دینار یا اس کے قریب تھا، اسی سبب وہ ایک ایسی دولت کے مالک ہوگئے جس کی کوئی حد نہ تھی۔ لیکن وہ (عرب) لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود اپنی اسی سخت زندگی پر باقی رہے، جیساکہ عمر اپنے لباس کو حیوانات کی کھال سے پیوند لگاتا تھا اور اسی مقام پر مولائے کائنات حضرت علیـ کہا کرتے تھے اے زرد اور سفید سکو! (سیم و زر) کسی دوسرے کو دھوکہ دینا۔ ابوموسیٰ مرغ کھانے سے پرہیز کیا کرتے تھے ۔کیونکہ عربوں کے درمیان مرغ کی کمی کی بناپر اس کے کھانے کا رواج نہیں تھا۔ ان (عربوں) کے یہاں مطلق کسی قسم کی آٹا چھاننے کی چھلنی بھی نہیں ملتی تھی اسی لئے وہ لوگ گندم کے آٹے کو اس کی بھوسی سمیت کھایا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس ثروت کے سبب جو ان کے ہاتھ لگی تھی دنیا کے مالدار ترین افراد شمار ہوتے تھے۔
اس بارے میں'' مسعودی کا بیان ہے: ''عثمان کے زمانے میں پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اصحاب نے بہت ساری دولت و املاک کو حاصل کرلیا تھا۔ جیساکہ جس روز عثمان قتل کئے گئے، اس دن ان کے خازن کے پاس ایک لاکھ پچاس ہزار دینار اور دس لاکھ درہم آپ کے خزانہ میں موجود تھے اور وادی القریٰ (مدینہ سے قریب ایک جگہ) اور حنین (مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے) میں اور دوسرے علاقوں میں ان کی جائداد کی قیمت دولاکھ دینار کے برابر تھی اس کے علاوہ بہت سے اونٹ اور گھوڑے بھی موجود تھے ۔زبیر کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کا آٹھواں حصہ پچاس ہزار دینار تھا اور اس نے اپنے مرنے کے بعد ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار کنیزیں چھوڑی تھیں۔ طلحہ کو عراق کے محصولات میں سے ہرروز ہزار دینار کا محصول اور شراة کے علاقہ سے اس سے زیادہ مقدار میں پیسہ اس کے پاس آتا تھا۔اسی طرح عبدالرحمن ابن عوف کے اصطبل میں ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ اور دس ہزار بھیڑیں موجود تھیں۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کا ایک چوتھائی حصہ چوراسی ہزار دینار سے بھی زیادہ تھا۔ زید ابن ثابت نے سونے چاندی کی اتنی زیادہ مقدار میں اینٹیں چھوڑیں تھیں جن کو کلہاڑی سے کاٹ کر الگ کیا جاتا تھا اور یہ ان اموال و املاک کے علاوہ تھا جن کی قیمت ایک لاکھ دینار کے آس پاس پہونچ تی تھی۔ زبیر نے ایک ایک گھر بصرہ اور مصر و کوفہ میں اور اسکندریہ میں بہت سے، گھر اپنے لئے بنوائے تھے۔ اسی طرح طلحہ نے ایک گھر کوفہ میں اور دوسرا گھر مدینہ میں بنوایا اور ان کو چونے کے مصالح اور ساکھو کی لکڑی سے پختہ کروایا (ساج ایک درخت ہے جو صرف ہندوستان میں پایا جاتا ہے (اس کو وہاں ساکھو کے نام سے جانا جاتا ہے)اس کی لکڑی سیاہ اور سیدھی ہوتی ہے اور مٹی میں سڑتی گلتی نہیں) سعد ابن وقاص نے اپنے واسطے ایک گھر عقیق میں بنوایا (عقیق چند جگہوں کا نام ہے جو مدینہ، یمامہ، تہامہ، طائف اور نجد وغیرہ) اس کی چھت بلند تھی اور اس میں ایک وسیع و عریض صحن بھی تھا اور اس کی دیواروں پر کنگورے بنوائے جس کے اندرونی اور بیرونی حصہ کو گچکاری (چونے سے پلاسٹر) کی گئی تھی۔ یعلی ابن منبہ نے پچاس ہزار دینار اور کچھ زمین و پانی اور ان کے علاوہ بھی دوسری کچھ چیزیں چھوڑیں اور ان کی جائداد اور دوسرے ترکہ کی قیمت تین لاکھ درہم تھی اور یہ مسعودی کے بیان کا آخر تھا۔''
پس جیساکہ ہم نے دیکھا جس مال و دولت کو قوم عرب نے حاصل کیا تھا وہ بھی اسی طرح کی تھی اور ان کی اس روش پر ہم مذمت نہیں کرسکتے ۔کیونکہ ان کی ثروت حلال کی کمائی تھی جسے انھوں نے مال غنیمت اور فیٔ کے طورپر حاصل کیا تھا اور اس ثروت کا استعمال کرنے میں انہوں نے فضول خرچی سے کام نہیں لیا تھا، بلکہ جیساکہ ہم نے کہا کہ وہ اپنی زندگی کے رسوم و آداب میں اقتصاد اورمیانہ روی کی رعایت کرتے تھے۔ اس وجہ سے زیادہ ثروت کے رکھنے پر ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ۔اگر زیادہ ثروت کا حصول برا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ثروت کا رکھنے والا فضول خرچی کی طرف مائل ہوتا ہے حداعتدال اور میانہ روی سے خارج ہوجاتا ہے ۔ لیکن ایسی صورت میں کہ مالدار لوگ میانہ روی کو اختیار کریں اور اپنی ثروت کو راہ حق اور امور خیر میں خرچ کریں اس وقت مال و دولت اور ثروت کی زیادتی اور مالداری، ان کو نیک کاموں اور حق کے راستے کو اختیار کرلے اس دنیا کے مراتب کو حاصل کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ جب اس قوم کی سادگی اور بادیہ نشینی رفتہ رفتہ ختم ہوگئی، جیساکہ ہم نے کہا کہ تعصبات کے تقاضے کی بنیاد پر جب حکومت و سیاست اور جاہ طلبی کی فطرت نے سر اُٹھایاتو انھوں نے قہرو غلبہ حاصل کرلیا، لہٰذا ان کی ملک گیری بھی خوشحالی اور مالی آسائش اور زیادہ ثروت کے حاصل کرنے کے حکم میں ہے یعنی اس غلبہ اور دنیا کو حاصل کرنے کے لئے باطل طریقہ اور راستہ کو اختیار نہیں کیا اور اپنے قدم کو دیانت، اصول و مذاہب حق و حقیقت کی راہ سے ایک قدم بھی زیادہ نہیں رکھا۔(۳۸)
ایک عظیم بحران
یہ وہ حالات تھے جوعثمان کے دور خلافت میں موجود تھے اور بعد میں امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب کو میراث میں ملے۔ جیساکہ ہم نے بیان کیا کہ اکثر یہ حالات عموماً اس زمانہ کے متمدن اور ثروت مند لوگ تیزی کے ساتھ اور پے در پے فتح کی وجہ سے وجود میں آئے ۔لیکن بغیر کسی شک و تردید کے اس شدید، عظیم بحران کو ہوا دینے اور مزید کاری بنا نے میں خود عثمان کا بھی ایک مؤثر حصہ تھا۔ شہرستانی صاحب جو کہ عثمان کے بہت ہی دفاع کرنے والوں میں سے ایک ہیں، ان کے مسند خلافت پر پہنچنے کی داستان اور ان کی بہت سی غلطیا ںاور لوگوں کا ان سے روگردانی کر لینا اور آخرکار ان کے قتل ہوجانے کے بارے میں اجمالاً اس طرح نقل اور تجزیہ کرتے ہیں: ''سبھی لوگوں نے عثمان کی بیعت پر اتفاق کرلیا۔ معاشرہ کے امور منظم ہوگئے اسلام کی دعوت ان کے زمانہ میں بھی ویسی ہی جاری رہی۔ بہت سی فتوحات بھی حاصل ہوئیں اور بیت المال میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔ وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی اور سخاوت مندی کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے قریبی رشتہ داروں یعنی بنی امیہ نے ان کو بربادی کے دہانہ پر کھڑا کردیا۔ لوگوں پر ظلم و ستم کیا وہ خود بھی ظلم و ستم کی چکی میں پِس گئے۔ ان کے زمانے میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوئے کہ وہ سب کے سب نبی امیہ کی وجہ سے تھے۔ ان میں سے ایک حَکم ابن امیہ کو مدینہ واپس بلانا تھا جس کو رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم نے مدینہ سے نکلوادیا تھا اور وہ طرید رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم سے معروف تھا۔ عثمان نے ابوبکر کے ایام خلافت اور عمر کے ایام خلافت میں ہی اس کے مدینہ واپس بلانے کی سفارش کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی اور عمر نے اس کو اس کے محل سکونت سے چالیس فرسخ اور دور چلے جانے کا حکم دے دیا۔ ابوذر کو ربذہ کی طرف شہربدر کردیا (مدینہ سے نکال دیا) اور اپنی بیٹی کا عقد مروان ابن حکم سے کردیا اور افریقہ کے مال غنیمت کا خمس اس (مروان) کو بخش دیا جو دولاکھ دینار سے زیادہ تھااور اس میں سے اپنے رضاعی بھائی، عبداللہ ابن سعد ابن سرح کو واپس بلایا اور پناہ دیا جس کے خون کو پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم نے بے اہمیت اور مباح قرار دیا تھا (اس کے خون کا نہ کوئی قصاص ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دیت ہے) مصر کی مملکت کو اسے بخش دیااور عبداللہ ابن عامر کو بصرہ کی ولایت دیدی تھی۔ وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی ایسے تھے جن کی بناپر یہ ان میں پھنس گئے۔ مثلاً اپنی مسلح افواج کے سرداروں میں سے معاویہ کو شام کا امیراور عبداللہ ابن عامر کو بصرہ کا والیاور مصر کا والی عبداللہ ابن ابی سرح کو بنایا تھا یہ تمام کے تمام ان (عثمان) کو ذلیل و حقیر سمجھتے تھے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے یہاں تک کہ جو کچھ تقدیر میں تھا وہ ہوکے رہا اور آخرکار اپنے ہی گھر میں قتل کردیئے گئے۔''(۳۹)
اگر عثمان کے انتخاب اور ان کے قتل کے معاملہ کا گذشتہ دونوں خلفا سے تقابل کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ نہ تو خلفا کا انتخاب یہ بیان کرتا ہے کہ خلفا لوگوں کے نزدیک دینی شائستگی رکھتے تھے اور نہ ہی یہ بیان کرتا ہے کہ یہ عہدۂ خلافت اس زمانہ میں کسی خاص دینی اہمیت کا حامل تھا۔ وہ اس لئے خلیفہ منتخب ہوگئے چونکہ ان کو چھ افراد پر مشتمل کمیٹی کا حاکم عبد الرحمن ابن عوف نے چُنا تھا اور وہ اس لئے قتل کئے گئے کہ انھوں نے معترضین کے اعتراض اور شکایات کو نظر انداز کردیا اور ان کی ایک نہ سنی اور اپنی طرف سے عوام کو دیئے گئے کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کیا۔
ایک عمومی نظریہ
اب دیکھتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والے کون تھے اور کیوں اعتراض کیا؟
وہ مختلف علاقوں کے مسلمان تھے جو اپنے حکام کی بے دینی، لاپرواہی اور ظلم سے تنگ آگئے تھے اور خلیفہ کے پاس شکایت لے کر آئے تھے لیکن وہ (خلیفہ) ان حقیقتوں سے لاپرواہی برت رہے تھے۔ وہ لوگ خلیفہ کو دین اور دین کے اصول و قوانین کی حفاظت کی دعوت دے رہے تھے کیونکہ وہ معتقد تھے کہ خلیفہ نے اپنے تمام بدکردار اور لاپرواہ رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کو مسلمانوں پر حاکم بنادیا ہے اور کی مسئلہ حقیقت بھی یہی تھی۔(۴۰)
دوسری طرف سے مسلمانوں کا یہ اعتراض اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا نظریہ خلیفہ بلکہ خلافت کی بہ نسبت کیا تھا ان کے اعتراضات کے معنی پہلے ہی مرحلہ میںیہ تھے کہ خلیفہ راہ راست سے منحرف ہوگیا ہے اور اس کو اس کی یاددہانی کرانی چاہئے۔ اس کے بعد ان کا اصرار اس معنی میں تھا کہ خلیفہ اپنی غلط روش پر اڑا ہوا ہے لہٰذا اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے مقابلہ میں قیام کرتے ہوئے اس کا جم کر مقابلہ کیا جائے۔ یہ قیام اور پائیداری اس حد تک پہونچ گئی کہ اس کے گھر کا محاصرہ کرلیا گیا اور آخرکار اس کو قتل کردیا گیا۔ لیکن ابھی یہ ماجرا کی انتہا نہیں تھی۔ عثمان نے اپنے شخصیت کو اتنا گرادیا تھا کہ لوگ انھیں مسلمان کہنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے یہاں تک کہ ان کو تین روز تک دفن نہیں کیا اور ایک مدت کے بعد ان کو ایک نامناسب مقام پر سپرد خاک کیا گیا۔(۴۱)
اگر ان کے بارے میں یہ طے پاجائے کہ ان کے زمانہ کے مسلمانوں کا ان کے ساتھ برتاؤ سے بعد والی نسلوں کو فیصلہ کی بنیاد قرار دیکر اس سے متاثر ہوں تو ان کا مرتبہ ایک عام مسلمان سے بھی کہیں زیادہ کم ارزش قرار پائے گا، لیکن بعد میں معاویہ کا بعد کا کار نامہ یہ کہ ان کو بری کرنے اور ان کے چہرہ کو تقدس بخشنے کے واسطے ان کو پہلے دونوں خلفاء کے ہم پلہ اور خلیفہ برحق قرار دیا۔ یہ نقطہ ہمیشہ اہل سنت کے کلامی اور اعتقادی نظام میں ضرر رساں نقاط میں سے ایک ہے۔ وہ چیز جس نے اہل سنت کے نزدیک عثمان کو عملی طورپر تمام خلفائے راشدین کے ہم پلہ بنادیا، تو یہ معاویہ اور اس کی نسل کا ایک وسیع پروپیگنڈہ تھا۔ اور جو لوگ صدر اسلام کی تاریخ کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ اس پروپیگنڈہ اورروایات کے گڑھے جانے نیز عثمان کے غیر شرعی ا قدامات سے، باخبر ہیں، انھوں نے اپنی زبان کو اس کے طعنہ و مذمت میں کھولی ہے۔ (یعنی عثمان و معاویہ وغیرہ کی مذمت اور لعن طعن کیا ہے) گذشتہ لوگوں کے درمیان، عام طورپر معتزلہ اسی طرح کی رائے کے حامل ہیں اور موجودہ دورمیں عام طورپر مذہبی روشن فکر لوگ نیز دوسرے وہ لوگ ہیںجو انقلابی رجحان رکھتے ہیں اور خاص طورپر جو لوگ مسلحانہ فعالیت رکھتے ہیں، انہیں نظریات کے حامل ہیں۔ آئندہ ہم اس کے متعلق تفصیل سے تحریر کریں گے۔(۴۲)
بہرحال مسلمانوں کا عثمان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اس بات کا بہترین نمونہ ہے کہ ان کا منصب خلافت اور خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے۔ اور وہ شخص جو اس مقام کو حاصل کررہا ہے وہ کیسا تھا جس وقت ان کو اس عہدہ پر فائز کیا گیا،کسی نے بھی اعتراض کے لیے اپنی زبان نہیں کھولی۔ انھوں نے عملی طورپر عام مقبولیت حاصل کرلی مقبولیت کے لحاظ سے عمر کی مقبولیت کے برابر مقبولیت حاصل کرلی۔(۴۳) لہٰذا بعد کے اعتراضات پہلی مقبولیت کے نہ ہونے کی بناپر نہ تھے کہ اعتراضات (عثمان) کی ان غلطیوں کا نتیجہ تھے، جس نے اس (عثمان) کو اتنا گرادیا کہ ان کے تمام کے تمام دوست اور ان کے کل کے ساتھی اور متحدین ان کے مد مقابل کھڑے ہوگئے۔
اس سلسلہ میں بہترین دلیل زہری نے بیان کی ہے جن کا شمار پہلی صدی کے علما اور فقہا میں ہوتا ہے کہ سیوطی ان کے بارے اس طرح نقل کرتے ہیں: ''عثمان نے بارہ سال خلافت کی۔ پہلے چھ سالوں میں کسی نے ان پر اعتراض نہ کیا ۔قرشی(خاندان قریش کی طرف منسوب) ان کو عمر سے زیادہ دوست رکھتے۔ تھے کیونکہ عمر سخت مزاج تھے لیکن یہ (عثمان) ان سے نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کے بعد اپنے امور میں سست ہو گئے اور دوسرے چھ سالوں میں کاموں کو اپنے قریبی رشتہ داروں اور متعلقین کے حوالے کردیا۔اور بہت سارا مال و دولت بھی ان لوگوں کو بخش دیا اور لوگوں کو ان کا یہ اقدام برا لگا لہٰذا ان کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے۔''(۴۴)
اگر اس زمانہ کے مسلمانوں کی نظر میں خلافت اور خلیفہ کی کوئی شان یا وہ کسی مقام کا حامل ہوتا بعد میں لوگوں نے اس کی توصیف بیان کر ڈالی، پھر اس کے مقابلہ میں کم از کم اس کیفیت سے قیام نہیں کرنا چاہئے تھا۔ جبکہ خاص طورپر عثمان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا تھا۔ یعنی عثمان ان لوگوں میں سے تھے کہ بعد میں لوگ جن کے لئے بلند ترین معنوی اور دینی فضیلت اور منزلت کے قائل ہوگئے۔عثمان کا ماجرا اس بات پر بہترین گواہ ہے کہ بعد کے زمانہ کے مسلمانوں نے خلیفہ اور خلافت بالخصوص خلفائے راشدین کی قدر و منزلت کے متعلق ایک دوسرے تصور کے قائل ہوگئے اور ان کو صدر اول کے مسلمانوں کے عقاید بلکہ اسے اسلامی عقیدہ قرار دیا اور اس طرح اس کو پیش کیا ، جس کے بارے میں شک و شبہہ پیدا ہونے کا امکان بہت کم ہوجائے۔(۴۵)
حضرت علیـ اور قبولِ خلافت
ایسے مشکل حالات میں لوگوں کی ناراض اکثریت نے علی ابن ابی طالب کی خدمت میں پناہ لی اور آنحضرت علیہ اسلام کے انکار کے باوجود آپ کو مسندخلافت پر بٹھادیا۔ درحقیقت یہ پہلی بار تھا کہ لوگوں کی اکثریت نے خود جوش طور پر داعیٔ بیعت کے عنوان سے ایک لائق ترین فرد ، ایسے شخص کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ عمر اور عثمان نے اپنے پہلے والے خلفا کی وصیت کے مطابق خلافت حاصل کی۔ اور ابوبکر کے بارے میں بھی مسئلہ علی ابن ابی طالب کی طرح نہیں تھا۔ شروع میں چند گنے چنے افراد نے ان کی بیعت کی اور بعد میں تیزی کے ساتھ کچھ حوادث کا پیش آ نا( جس کا سبب مہاجرین و انصار اور اوس و خزرج کے درمیان پوشیدہ و آشکار رقابتیں نیز بیرونی دھمکیاں بھی تھیں) جو اس بات کا سبب بنا کہ ان کی شخصیت اور موقعیت مستحکم ا ور پائیدار ہو جائے ۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عمر بعد میں مختلف مواقع پر کہا کرتے تھے :'' ابوبکر کی بیعت ناگہانی اور بغیر سوچے سمجھے ہوگئی کہ خداوندعالم نے مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ پس قتل کردو اس شخص کو جو اس شر کی طرف پلٹنا چاہتا ہے (یعنی جو ابوبکر کی طرح بیعت کروانا چاہتا ہے)(۴۶)
حضرت علی ـ نے بدترین حالات میں قدرت اور منصب خلافت کو سنبھالا اور ان مشکلات کو تحمل کرنے پر مجبورہوئے جن مشکلات کو پیدا کرنے میں آپ کا ذرا سا بھی ہاتھ نہ تھا۔ بنیادی طور پر آنحضرت کی بیعت کے لئے لوگوں کا ہجوم صرف اس لئے تھا کہ یہ مشکلات حل ہوجائیں۔ ان لوگوں کی نظر میں ان مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والا واحد شخص صرف اور صرف آنحضرت کی ذات والا صکات تھی، تقریباً تمام بیعت کرنے والوں کی چاہت بھی یہی تھی۔(۴۷) ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی کہ جنھوں نے ذاتی صلاحیت کی بنا پر آپ کو خلافت کے لائق سمجھتے ہوئے اور وصیت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی پیروی کرتے ہوئے آنحضرت کی بیعت کی تھی۔ اگرچہ بعد میں اُنہیں کم افراد کے چھوٹے سے گروہ کی مدد سے آنحضرت بڑی بڑی مشکلوں پر فائق آگئے۔
حقیقت یہ ہے کہ سابق خلفا میں سے کسی ایک نے بھی ایسے مشکل حالات میں منصب خلافت کو نہیں سنبھالا۔ کچھ مدت کے بعد جو لوگ عمر کی خلافت کے آخری ایام سے اس عہدۂ خلافت پر قبضہ کرنے کی فکر میں پڑ گئے تھے اور عثمان کے دور ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کررکھا تھا۔ مخالفت کا پرچم بلند کردیا۔ اس مخالفت کی تاخیر کی وجہ لوگوں کی وسیع اور قاطع اکثریت کا خوف تھا جو حضرت علیـ کے گرد جمع ہوگئے تھے ا ور اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ہوتا اور منصب خلافت کو سنبھالتا ، تب بھی یہ افراد مخالفت کے لئے اُٹھ کھڑے ہوتے۔ کیونکہ معاشرہ ہی غیر منظم اور بکھرا ہوا تھا۔ گویا تمام کے تمام، یا کم از کم معاشرہ میں نفوذ رکھنے والے، خود کو اس معاشرہ میں گم کئے ہوئے تھے۔ نہ تووہ خود ہی کو اور نہ ہی اپنی حیثیت کو ہی پہچانتے تھے اور نہ تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے ہی کوئی توقع رکھتے تھے۔(۴۸)
بہ عنوان نمونہ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے مخالفین کے سرداروں کو مدنظر رکھئے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی لیاقت اور قابلیت سے اونچی یہاں تک کہ اپنی ذاتی شخصیت سے بھی زایادہ توقع رکھتے تھے اور اگر حضرت علیـ سے ان کی مشترک مخالفت حاکم اور خلیفہ کے عنوان سے نہ ہوتی تو پھر وہ ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہوجاتے۔ کیا یہی طلحہ و زبیر نہیں تھے جنھوں نے جنگ جمل میں لشکر کے امام جماعت بننے کے لئے ایک دوسرے کی عبا کو کھینچ ڈالا ۔اور اپنے گھوڑوں کے چہرے پر تازیانے مارے ؟(۴۹) اور کیا اصحاب جمل میں سے مروان ابن حکم نہیں تھا جو طلحہ کے قتل اور اس سے انتقام لینے پر متہم تھا اور کم از کم یہ تھا کہ ُاس کے مرنے پر اس نے خوشیاں منائی تھیں؟(۵۰) آیا معاویہ ان لوگوں کو اور وہ لوگ معاویہ کو برداشت کرسکتے تھے؟ اس کے علاوہ آیا یہ احتمال موجود نہیں تھا کہ بااثر لوگ غیر جانب دار افراد جن لوگوں نے نہ حضرت علیـ کی بیعت کی اور نہ حضرت کے مقابل صف آراء ہوئے اگر کوئی دوسرا شخص منصب خلافت پر فائز ہوتا تو ایسی صورت میں یہ بے طرف اور معاشرہ میں نفوذ رکھنے والے افراد اس کے مدمقابل شمشیر بکف نظر آتے؟ لیکن یہ حضرت علیـ کی شخصیت اور آ پ کا بے نظیر سابقہ تھا جو ایسے قیام سے مانع ہوا چاہے جتنا وہ لوگ حضرت کے ساتھ اور ان کے حامی نہ رہے ہوں۔(۵۱)
جیساکہ ہم بیان کر چکے ہیں کیا کہ مسئلہ معاشرتی ، اخلاقی اور روحی انتظام کے بکھر جانے کا تھا۔ خود کو اپنے آپ کے گُم کردینے کا مسئلہ اورقابلیتوں اور صلاحیتوں کے مشتبہ ہوجانے سے متعلق تھا حتی خود ان لوگوں کے نزدیک بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علیـ اس وقت کے ا ن نامناسب اور بکھرے ہوے حالات کو منظم نہ کرسکے۔ دوسرا کوئی بھی شخص اس نامنظم اور بکھرے ہوئے اور خود پرچم بغاوت بلند کیئے ہوئے معاشرے کو منظم نہیں کرسکتا تھا۔ بلکہ اس کے لئے مسلسل سعی و کوشش اور ناکوں چنے چبانے کی ضرورت تھی تب جاکر وہ بے نظم معاشرہ نظم اور حکومت کو برداشت کرپاتا۔ البتہ افسوس کی بات ہے کہ اس نشیب و فراز کے بعد معاویہ کے ذریعہ معاشرہ میں یہ نظم و نسق برقرار ہوگیا۔
حضرت اس زمانہ کے حالات اور معاشرہ میں بے شمار تبدیلیوں کو اپنے ایک مختصر اور پُرمعنی جملہ میں یوں بیان فرماتے ہیں:''حضرت علیـ کے دورخلافت میں ایک روز کسی نے آپ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا۔ آخر اتنے سارے لوگوں نے آپ کے متعلق اختلاف کیا حالانکہ پہلے دو خلفا پر ان کا اتفاق تھا؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا:'' چونکہ وہ لوگ مجھ جیسے افراد پر حکومت کرتے تھے اور میں تجھ جیسے افراد پر حکومت کرتا ہوں۔''(۵۲)
روحی پریشانیاں
حقیقت کچھ ایسی ہی تھی۔ حالات بالکل بدل گئے تھے۔ حضرت علیـ کی اکثر مشکلات بھی انھیں حالات کی تبدیلیوں کی پیدا وار تھیں۔ ایک فقیر و محدود اور مسدود معاشرہ پر، جدید آفاق کا کھل جانا اور ایک مقامی ا ور محدود حکومت کا ایک وسیع و عریض مملکت و سلطنت میںتبدیل ہو جانا جو ایران کی شہنشاہیت کو مکمل طورپر اور روم کی بادشاہت کے ایک وسیع حصے کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی، نہ فقط نئی مشکلات اور سخت وسنگین حالات اپنے ہمراہ لائی تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم یہ تھا کہ اس نے ابتدائی دور کے مسلمانوں کے اخلاق و افکار اور معنویات و توقعات اور آرزؤں اور تمناوؤں کو بھی اپنے زیراثر قرار دیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ نہیں چاہتے تھے اور شاید ان خصوصیات کی بناپر جس کو انہوں نے حاصل کیا تھا وہ لوگ دینی قوانین، احکام اور معیار کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔ بلکہ وہ لوگ اس دین کو چاہتے تھے جس کی ان لوگوں نے خود تفسیر کی ہو۔ ایک ایسے دین کو چاہتے تھے جو ان کے مقاصد اور ان کی تمناؤں کو پورا کرسکے نہ کہ اس کے برعکس اور چونکہ ایسا ہی تھا یعنی ان کی آرزوؤں اور چاہتوں کے بر خلاف تھا۔ لہٰذا وہ علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت کو برداشت نہیں کرسکتے تھے حسب ذیل نمونہ اس مسئلہ کو پوری طرح بیان کررہا ہے۔
جنگ صفین کے وقت، امام اور آپ کے برجستہ اصحاب اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی طرح جنگ کو روک دیں۔ان میں سے جس نے اس بات کی سب سے زیادہ کوشش کی تھی وہ عمار تھے انھوں نے کوشش کی تاکہ مغیرہ ابن شعبہ کو وعظ و نصیحت کریں اور امام کی حقانیت کو اس پر واضح کردیں ۔لیکن وہ انجان بن رہا تھا اور حقیقت کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا (مغیرہ امام کو اور آپ کے تمام سابقہ حالات کو بخوبی جانتا تھا یہاں تک کہ آپ کی خلافت کے شروع میں ہی اس نے حضرت سے کہا کہ طلحہ و زبیر اور معاویہ کو ان کے عہدوں پر باقی رکھئے تاکہ لوگ آپ کی بیعت پر متفق ہوجائیں اور اتحاد و اتفاق بر قرار اور محفوظ رہ جائے اور پھر آکا جیسے جی چاہے حکومت کیجئے۔ اور جب یہ دیکھا کہ امام نے اس کی بات اور اس کے مشورہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو وہ دوسرے روز آکر اس طرح کہنے لگا: ''میں نے غورو فکر کے بعد یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا اس میں مجھ سے غلطی ہوگئی ہے اور حق وہی ہے جو آپ نے سوچا ہے۔''(۵۳) امام نے عمار کو مخاطب کرکے فرمایا:'' اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دو! کیونکہ وہ دین سے کچھ نہیں لیتا مگر وہی چیز جو اس کو دنیا سے نزدیک کردے۔ وہ مسئلہ کو عملی طورپر اپنے اوپر مشتبہ کرلیتا ہے تاکہ ان شبہوں کو اپنی خطا کے واسطے عذر قرار دے''۔(۵۴)
البتہ یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ لوگ نہ صرف یہ امام کو تحمل نہیں کرسکتے تھے ،بلکہ کسی دوسرے شخص کو بھی برداشت نہیں کرسکتے تھے۔ ان کی مشترک مخالفت صرف اس بناپر تھی کہ قدرت اورمنصب امام کے ہاتھ میں تھا اور ان کی زیادہ تر ناجائز خواہشات کے پوری اور عملی نہ ہونے سے امام بالکل بے توجہ تھے ، اسی سبب نے ان کے اندر اتحاد پیدا کردیا تھا اور کم از کم ان میں آپس کے اختلا ف کو آشکار ہونے سے مانع تھا۔ البتہ خاص حساس مواقع پر اس اتحاد کا شیرازہ بکھر جاتا تھا۔ یہ وحدت ٹوٹ جاتی اور اختلاف و کشمکش نمایاں ہوجاتا تھا۔(۵۵)
بہرحال آنحضرت اپنے پورے دورخلافت میں اس بات پر مجبور ہوگئے کہ وہ اپنے مخالفین سے مقابلہ کریں اور وہ لوگ جو جنگ کے لئے آمادہ ہیں، ان سے مقابلہ کے واسطے اُٹھ کھڑے ہوں۔ یہ جنگیں ان نقصانات کے ظاہر ہونے کا فطری نتیجہ تھیں کہ اپنی گذشتہ تاریخی سابقہ جو اسلام سے ماقبل ہے اس تک پہونچتی تھی اور یہ مسئلہ عمر کے دورخلافت کے درمیانی ایام میں پیدا ہوا۔ اور آہستہ آہستہ (اندر اندر) پکتا رہا اور یہ دور بھی امام کی شہادت(۵۶) اور معاویہ کے حکومت حاصل کرنے پر ختم ہوگیا۔
وہ افراد بہت زیادہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام کی یہ مشکلات آپ کے ایام خلافت میں دین و عدالت کی بنیادپر مبنی دقیق اور سخت رویہ کی وجہ سے وجود میں آئی تھیں۔ اگرچہ یہ بات درست ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام مشکلات کی بنیاد یہ نہیں تھی۔ بلکہ ان میں سے بہت سے مشکلات کی بنیاد کو اس زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور ماحول میں تلاش کرنا چاہئے۔ ایک ایسا ہمہ گیر اور گہرا بدلاؤ پیدا ہوا تھا جس نے اپنے اندر ہر چیز اور ہر شخص کو غرق کردیا تھا۔ فقط چند باایمان ا ور بااخلاص مسلمان تھے جو ان حالات کے بہاؤ میں غرق نہیں ہوئے تھے۔ وہی لوگ جو حضرت علی ـ سے متحد اور ہم آہنگ اور اپنے خون کے آخری قطرہ تک آپ کی ہمراہی میں اور آپ کے ہم رکاب رہے اور ان میں سے بہت سیافراد تینوں جنگوں میں درجۂ شہادت پر فائز ہوگئے۔(۵۷)
معاشرہ اور سماج کا درہم برہم ہونا
اس درہم و برہم حالات کو نہ صرف یہ کہ حضرت علیـ بلکہ کوئی دوسرا بھی منظم نہیں کرسکتا تھا۔ قدیم اور جدید صاحبان قلم کے قول کے بالکل برعکس اگر بالفرض پہلے دونوں خلفا بھی آنحضرت کی جگہ ہوتے تب بھی حالات میں اتنی تبدیلی نہیں آسکتی تھی۔(۵۸) ان دونوں کی کامیابی معاشرتی انسجام اور اتحاد کو برقرار رکھنے میں ،اس زمانہ کے حالات کی مرہون منت تھی نہ کہ ان کی ذاتی خصوصیات یا ان کی مجموعی سیاست کا ثمرہ رہی ہوں۔ بغیر کسی شک شبہہ کے اگر امام کو گذشتہ خلفا کے دور میں مسند خلافت پر بٹھا دیا جاتا تو ان دونوں سے کہیں زیادہ وہ کامیاب ہوتے ۔یہ بات کسی حدتک عثمان کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ ان کی ناکامی فقط ان کی غلط خصوصیات کی بناپر وجود میں نہیں آئی تھی ۔احتمال قوی کی بناپر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اگر ان (عثمان) کے ماقبل دونوں خلفا میں سے کوئی بھی ان کی جگہ برسر اقتدار آتا، تب بھی حالات کی تبدیلی میں کوئی خاص فرق نہ پڑتااور اسے بھی کم و بیش انھیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جن سے عثمان دوچار ہوئے ہیں۔
وہ مؤرخین یہ بھول بیٹھے کہ پہلے ہی در جہ میں عثمان کی مشکلات انھیں مشکلات کا سلسلہ تھیں جن سے خود عمر اپنی خلافت کے آخری دور میں دست و گریباں تھے اور یہ ساری مشکلات اس نئے ماحول اور حالات ضمنی عوا ر ض کا نتیجہ تھے جو جدید فتوحات کے ذریعہ پیدا ہوئے تھے۔ عمر نے اپنی عمر کے آخری ایام میں یہ احساس کرلیا تھا کہ وہ اپنے نفوذ و اختیارات سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اب خلافت کے ابتدائی سالوں کی طرح قدرت اور رعب و دبدبہ کے ساتھ حکومت نہیں کرسکتے۔ اس حقیقت کا قبول کرنا ان کے واسطے بہت مشکل امر تھا جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انھوں نے کئی مرتبہ موت کی تمنا کی۔
لیکن گویا امام علیـ پر تنقید کرنے والے یہ سب مسائل بھول گئے ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ انھوں نے اپنی تجزیہ و تحلیل میں تیز گام بنیادی انقلابات اور حالات میں تیزی کے ساتھ بدلاؤ کو نظر انداز کردیا اور خلفا میں ہر ایک کی کامیابی کی مقدار کو فقط فردی سیاستوں، خصلتوں اور خصوصیات کی بنیادپر چھان بین کی ہے۔(۵۹)
چنانچہ معاویہ بھی جو مدارات، ہوشیاری(کیاست) اور سیاست میں مشہور تھا اگر بلافاصلہ قتل عثمان کے بعد حکومت کی باگ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ، اسے بھی ایسے ہی مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جن سے حضرت علیـ دوچار تھے۔(۶۰) بیشک اصحاب جمل علیـ کی بہ نسبت معاویہ کے ساتھ زیادہ شدو مد اور سختی کے ساتھ جنگ کے لئے اُٹھ کھڑے ہوتے کیونکہ وہ آنحضرت کی دینی اور ذاتی لیاقت اور یہاں تک کہ اپ کی عمومی بیعت کے شرعی اور قانونی ہونے کا یقین رکھتے تھے اور صرف بہانہ تراشی کرتے تھے۔ وہ لوگ خود ان چیزوں کو جانتے تھے اسی وجہ سے عائشہ نے چند مرتبہ پلٹ جانے کا پکا ارادہ کیا لیکن ہر بار لوگوں نے جھوٹ بو لکر ان کو اس کام سے روک دیا۔(۶۱) بعد میں وہ خود اپنے اس کام سے سخت پشیمان ہوئیں۔(۶۲) زبیر بھی جنگ کے آخری لمحوں میں محاذ جنگ کو ترک کردیا اور وہ اس بات کے لئے تیار نہ ہوئے کہ حضرت علیـ سے جنگ کریں۔(۶۳) لیکن معاویہ ان لوگوں کی نظر میں نہ یہ کہ فقط ہر قسم کی لیاقت و خوبی سے عاری تھا بلکہ وہ لوگ خود کو اس سے بہتر اور برتر سمجھتے تھے۔ اس سے بھی قطع نظر، ظن غالب کی بنیاد پر سعد ابن ابی وقاص اور ان کے جیسے دوسرے لوگ جو نہ تو امام کی حمایت کے لئے اور نہ ہی آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے، وہ معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ان لوگوں کے لئے قابل قبول نہ تھا کہ وہ لوگ اس (معاویہ) کو عثمان کے بعد بلافاصلہ مسند خلافت پر بیٹھا دیکھیںاور وہ لوگ اس کے تابع رہیں معاویہ اپنی مطلقہ قدرت اور حکومت پانے کے ایک عرصہ کے بعد بھی ان سے ڈرتا تھا اور ان لوگوں کو یزید کی ولیعہدی کی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ سمجھتا تھا۔(۶۴)
اور یہ کلام ایک دوسری طرح سے ان لوگوں کے بارے میں بھی صحیح ہے جنھوں نے خلافت امام کے آگے سرتسلیم خم کردیا تھا۔ قیس ابن سعد ابن عبادہ کے ایسے لوگ، قطعی طورپر اگر امام میدان خلافت و سیاست میں موجود نہ بھی ہوتے، تب بھی وہ معاویہ اور اس کے جیسے دوسرے افرادکے مقابلہ میں کھڑے ہوجاتے۔ ان لوگوں کی مخالفت معاویہ کے ساتھ اس بنا پر نہ تھی کہ وہ امام کے دوستوں کی صف میں آگئے تھے اور امام معاویہ کے مد مقابل اٹھ کھڑے ہو ئے تھے ان لوگوں کی معاویہ سے ایک سنجیدہ اور بنیادی مخالفت تھی۔ کیونکہ وہ لوگ امام کو خلیفہ بر حق جانتے تھے، لہٰذا آپ کے پرچم تلے اس کے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اگر ایسا علم اور پرچم نہ بھی ہوتا تب بھی مسئلہ میں کوئی تبدیلی نہ آتی کیونکہ معاویہ امام کی شھادت کے بعد بھی ان لوگوں سے ڈرتا تھا۔(۶۵)
اسی طرح خوارج جیسی مشکل بھی خواہ مخواہ وجود میں آگئی۔ خوارج داستانِ حکمیت کی پیداوار نہیںہیں یہ حادثہ زخم کو تازہ کرنے کا ایک سبب تھا کہ حتی زمانۂ پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم میں بھی جس کا وجود تھا۔ وہ لوگ خشک اور تند مزاج بدّو تھے کہ بنیادی طورپر دین کے متعلق ایک دوسرا نظریہ رکھتے تھے( دین کے متعلق تنگ نظری اور سخت گیری کے شکار تھے۔ )اور اپنی اسی کج فہمی ا ور ایسے ادراک کی بنیاد پر خود پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی ذات پر بھی اعتراض کربیٹھے۔ مشہور ہے کہ ایک روز قبیلہ بنی تمیم کے افراد میں سے ایک شخص جو بعد میں خوارج کے سرداروں میں سے ہوگیا اور جنگ جمل کے معرکہ میں مارا گیا(ذوالخو یصرہ) جس وقت آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم مال غنیمت تقسیم فرمارہے تھے، آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم پر اعتراض کربیٹھا اور کہنے لگا ''اے محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم ! عدالت کی کیوں رعایت نہیں کی؟'' پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم غضب میں آگئے اور فرمایا: ''میں نے عدالت کی رعایت نہیں کی! تو میرے علاوہ عدالت کو کہاں پائے گا؟'' اس کے بعد فرمایا یہی لوگ وہ گروہ ہونگے جو دین سے خارج ہو جائیںگے ا س وقت ان لوگوںکے خلاف جنگ کرنے کے لئے اُٹھ جانا۔(۶۶)
ضروری تھا کہ ایک زمانہ گذرجائے اور حالات تبدیل ہو جائیں تاکہ رفتہ رفتہ یہ کج فکر بچکانہ ذہنیت رکھنے والے بدو سخت گیر افراد ایک گروہ کی شکل میں جمع ہوکر موجودہ نظام کے مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں ۔یہ تصور کرنا بالکل غلط ہے کہ یہ لوگ جنگ صفین اور داستانِ حکمیت کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ اسلامی معاشرہ کے اندر ایک سرطانی غدہ کی حیثیت رکھتے تھے کہ آخرکار ایک نہ ایک روز اس کو پھوٹنا ہی تھا البتہ حضرت علیـ کے زمانہ میں حالات کچھ اس طرح ہوگئے تھے کہ اس کا مناسب ترین موقع اس دور میں آپہونچا۔
قطعی طورپر اگر معاویہ حضرت علیـ کی جگہ قرار پاتا تو یہ لوگ زیادہ قدرت اور قوت کے ساتھ وسیع پیمانہ پر میدان میں نکل آتے، ان کا اعتراض حضرت علی ابن ابی طالب پر یہ تھا کہ کیوں تم نے حکمیت کو مان لیا اور اب اپنے اس عمل سے توبہ کرو۔ صرف یہی ایسا ایک اعتراض تھا جو وہ کرسکتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں حضرت علیـ کبھی بھی اسلام کے صراط مستقیم اور عدالت سے خارج نہیں ہوئے اور یہی وجہ تھی کہ ان خوارج میں سے بہت سے امام اور ان کے اصحاب کی توضیحات سے اپنی راہ سے عدول کرگئے ، نہروان کی جنگ میں، جنگ سے منھ موڑ کرچلے گئے ۔لیکن کیا ان کا یہ رویہ معاویہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا؟
معاویہ جیسا شخص خوارج کی نظر میں ظلم و بربریت اور کفر و بے دینی کا مظہر تھا ۔جیساکہ وہ لوگ (خوارج) اِس(معاویہ) کے قدرت میں آنے کے فوراً بعد اُس کے اور اس کے ناخلف اخلاف کے مدمقابل کھڑے ہوگئے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ اس راہ میں انھوں نے شجاعت اور بہادری کی یادگار قائم کردی عباسیوں کے ابتدائی دور تک ان کی جنگ اور استقامت اور صف آرائی جاری رہی اور آخرکار وہ بغیر کسی فوجی طاقت کا مقابلہ کئے ہوئے، حالات کے بدل جانے سے نابود ہوگئے اور وہ لوگ بھی جو باقی رہ گئے تھے انھوں نے اپنے باقی فکر و عمل اور اعتقاد میں اس طرح کی اصلاحات اور اعتدال پیدا کر لیا کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے مانند ہوگئے۔(۶۸)
مشکلات کا سرچشمہ
نتیجہ یہ کہ علی ابن ابی طالب کی مشکلات کا سرچشمہ صرف ان کی عدالت خواہی ہی نہ تھی۔ بلکہ ان میں سے اکثر مشکلات اس زمانے کے حالات کی طرف پلٹتی ہیں۔ اگر حضرت علیـ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی ان مشکلات سے روبرو ہوتا۔ اگر بعد میں معاویہ تک حکومت اور قدرت پہونچ گئی پھر بھی زیادہ ترمشکلات ان حالات کی بناپر ہے جو حضرت علیـ کے دور خلافت کے بعد رونما ہوئیں نہ معاویہ کی ذاتی اور شخصی خصوصیات کی بناپر۔ اور خلافت کے عموماً بڑے دعویدار اور معاویہ کے رقیب امام کے مد مقابل صف آرا ہوکر قتل ہوگئے تھے۔ اور اس زمانے کے تلخ تجربوں نے لوگوں کو خستہ و فرسودہ کردیا تھا اور اب مائل نہ تھے کہ نفوذ رکھنے والے اور خلافت کے دعویداروں کی آواز پر لبیک کہیں ۔گویا اس معاشرہ میں سکون حاکم ہوچکا تھا اور وہ خود بخود رام ہوگیا تھا اور اس کا مد و جزر تھم چکا تھا اور ایک ایسی قدرت کی جستجو میں تھا جو ان کے لئے امن و امان کا نوید لائے اور اس زمانے کے لوگوں کی نظر میں یہ فقط معاویہ ہی تھا جو اپنے اندھے و بہرے اور اندھی تقلید کرنے والے شامی اطاعت گزاروں کی مدد سے یہ کام کر نے پر قادر ہوگیا تھا۔ اگرچہ بعد میں اس نے لوگوں کو قبرستان جیسے امن و سکون کے تحفہ سے نوازا جو تمام آزادیوں اور انسانی کرامتوں کو سلب اور تمام اصول و اسلامی معیاروں کو پامال کرنے کے مترادف تھا۔(۶۹) یہ علی ابن ابی طالب کے خلافت تک پہنچنے اور آنحضرت کے ساتھ ہونے والی مخالفتوں کی اجمالی داستان تھی۔ عثمان کی بے لیاقتی، کینہ توزی، خاندان پرستی اور ان کے فوجی سرداروں کی ظلم و زیادتی اور لاپرواہی نے لوگوں کی چشم امید کو آنحضرت کی طرف مبذول کر دیا تھا اس حدتک کہ لوگوں نے بیعت کرنے کے واسطے ایسا ہجوم کیا کہ آپ کے دونوں فرزند اس ہجوم اور بھیڑ میں پِس کر زخمی ہوگئے۔ لوگ خود آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی طرف لپکے اور ان کی طرف دوڑے (نہ کہ حضرت نے چاہا اور ان کو اپنی طرف بلایا ہو ۔) اب اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم کہیںکہ آنحضرت لوگوں کی طرف سے قبول کر لئے گئے۔ انھوں نے بیعت سے پہلے ہی، اپنا انتخاب کرلیا تھا۔
البتہ اس کے علاوہ بھی دوسرے اسباب موجود تھے مثلاً'' مونٹ گمری واٹ'' معاویہ کی کامیابی اور حضرت علی ـ کے لئے پیش آنے والی مشکلات سے روبرو ہونے کے بارے میں اس طرح کہتا ہے: ''معاویہ کی حمایت ان شامی عربوں کے ذریعہ ہوتی تھی۔ جو کئی سال سے اس کے فرمانبردار اور اطاعت گذار تھے عام طورپر وہ صحرا سے نہیں آئے تھے بلکہ وہ ایسے خاندان سے متعلق تھے جو ایک یا دو نسل سے شام ہی میں مقیم تھے لہٰذا وہ ان بدّؤں کی بہ نسبت زیادہ پائیدار اور بھروسے مند تھے جوعلی ابن ابی طالب سے وابستہ تھے۔شامی عربوں کی بہترین کیفیت معاویہ کی کامیابی کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔''(۷۰)
آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے مخالفین اور معارضین (مقابلہ کرنے والے) حقیقت میں دہشت گرد اور شدت پسند تھے فقط انھیں کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی جگہ پرہوتا وہ لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے۔ ان لوگوں کا اعتراض صرف یہ تھا کہ حکومت میں ان لوگوں کا کوئی خاص عہدہ یا مقام کیوں نہیں ہے۔ وہ چیز جس نے ان لوگوں کو ایک متحدہ محاذ پر لاکر کھڑا کردیا تھاوہ امام سے مخالفت تھی نہ یہ کہ ہم عقیدہ ا ور ہم مسلک ہونے کی بنیاد پر۔ یہی وہ لوگ تھے جنھوں نے پروپیگنڈے ، دھمکیوں اور لالچ دینے(تطمیع) کا سہار الیکر عوام الناس کی صف اتحاد میں تفرقہ اندازی کرکے چاہے ان لوگوں کے درمیان تفرقہ اندازی کرتے جنھوں نے امام سے براہ راست بیعت کی تھی یا پھر ان کو قانونی طورپر اپنا برحق خلیفہ تسلیم کرتے تھے، ا ان لوگوں کے درمیان اختلاف کا بیج بویا اور آخر کار ایک گروہ کو اپنا پیرو بنا ہی لیااور امام ـکے مدمقابل کھڑا کردیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چند لوگوں کے علاوہ سب نے امام کی خلافت کو قبول کرلیا تھا اور ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا امام بعنوان خلیفہ منتخب کرلینا گذشتہ دونوں خلفا کی بہ نسبت زیادہ وسیع اور اکثریت کا حامل تھا۔(۷۱)
البتہ ہم پہلے یہ بیان کرچکے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی خلافت پر پہنچنے کی داستان پہلے تین خلفا سے مختلف تھی اگرچہ عمومی طورپر لوگوں نے آپ کی بیعت کرکے آپ کے گرد جمع ہوگئے تھے اور گذشتہ خلفا کی طرح آپ کو دیکھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ حضرت علیـ ان کے دنیاوی امور کی بھی ذمہ دار ہوں لیکن آپ کے ماننے والوں اور پیروی کرنے والوں میں کچھ ایسے بھی افراد تھے جنھوں نے آپ سے بیعت اس واسطہ کی تھی آپ کو وہ پیغمراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے برحق جانشین اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی طرف سے منسوب اور منصوص جانتے تھے۔ (یعنی پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم نے خاص طورپر آپ کو جانشین بنایا تھا) آپ کی بیعت اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کا کوئی رہبر ہو جو ان کے دنیاوی امور کی دیکھ بھال کرے اور اس کے انتظام کو اپنے ہاتھوں میں لے لے، بلکہ آپ کی بیعت اس لحاظ سے کی تھی کہ وہ لوگ اپنے دنیاوی اور دینی امور میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے صحیح جانشین کی بیعت کئے ہوئے ہوں۔ یعنی ایسے شخص کی بیعت جو وسیع اور عمیق معنوں میں منصب امامت کی لیاقت رکھتا ہو ۔ایسی امامت جو نبوت اور رسالت ہی کا ایک سلسلہ ہو بلکہ یہ امامت، رسالت و نبوت کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ اگرچہ ایسے (مخلص) افراد کی تعداد بہت کم تھی لیکن وہ لوگ سایہ کی طرح ہمیشہ امام کے ہمراہ تھے اور لوگوں کو امام کی طرف بلاتے رہے اور آنحضرت کے ساتھ جنگوں میں بہت اساسی کردار ادا کیا اور عموماً انھیں جنگوں میں درجۂ شہادت پر فائز ہوگئے۔(۷۲)
حقیقت کی بدلتی ہوئی تصویر
خلفائے راشدین کی تاریخ کی حقیقت یہ تھی جیساکہ وہ محقق ہوئی۔ اگر اس کا پہلا حصہ چین و سکون کے ساتھ اور اس میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں پائی جاتی ہے تو وہ صرف بیرونی خطرات میں لوگوں کی توجہات کے مشغول ہوجانے کی بناپر ہے، ابتدائی زمانہ میں بیرونی خطرات کی طرف توجہ کے مرکوز ہونے کے ساتھ ساتھ اندرونی دھمکیاں اور معاشرہ کا فقر اور اس کی محدودیت نے اپنے میں مشغول کر رکھا تھا، اگر اس کے بعد کا زمانہ پُرآشوب اور بحرانی ہے تو بھی اس کی پیدائش کا واحد سبب وہ حالات ہیں جو اکثر بیرونی خطرات کے ختم ہوجانے اور ثروت کی بھرمار کی بنا پر پیدا ہوئے ہیں۔ خلفا کا انتخاب عام لوگوں کی نظر میں اس زمانہ میں ایک معمولی چیز تھی۔ ان لوگوں کی نظر میں یہ لوگ (خلفا) بھی معمولی افراد تھے اور ان کا منصب بھی کوئی خاص فضیلت نہیں رکھتا تھا اور خود وہ(خلفا) بھی اپنے کو کسی اور زاویۂ نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔
جس وقت ابوبکر کہتے تھے کہ '' مجھ کو چھوڑ دو(سمجھنے کی کوشش کرو) میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں'' اور یا کہ وہ کہتے تھے :'' میرے اوپر ایک شیطان مسلط ہے'' اور میں کہیں راستہ سے کج ہوگیا (راہ راست سے بھٹک گیا) تو مجھے راہ مستقیم پر لگادو تو یہ مذاق نہیں فرمارہے تھے اور نہ ہی تواضع و انکساری کررہے تھے۔ وہ واقعاً ایسا ہی سوچتے تھے اور دوسرے لوگ بھی ان کو اسی نظر سے دیکھتے تھے۔ جس وقت عمر کہتے تھے: مجھ سے ہوشیار رہو اگر میں نے کہیں غلطی کی ہو تو مجھے ٹوک دو ۔'' یہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ کہتے تھے اور جس وقت فلاں عرب اُٹھ کر کہتا تھا :''خدا کی قسم اگر تم کج رفتاری کرو گے تو تمہیں شمشیر کے ذریعہ سیدھا کردیں گے۔'' حقیقت میں یہ چیز اس زمانہ کے لوگوں کا خلیفہ کے ساتھ برتاؤ کے طریقے اور بنیادی طورپر مقامِ خلافت کے متعلق لوگوں کے نظرئے کو بیان کرتی ہے۔(۷۳)
لیکن بعد میں ،جیساکہ ہم بیان کریں گے، ایک دوسرے طریقہ سے دیکھا گیا اور اس کی تصویر کشی کی گئی۔ رفتہ رفتہ انسانی، مادی اور دنیاوی رنگ کو کھوکر معنوی اور روحانی حاصل کرلیا یہاں تک کہ دینی تقدس کے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ دور جو صدر اسلام کے مسلمانوں کی تاریخ کا دور تھا درحقیقت خود اسلام کی تاریخ کی تمامیت اور خالصیت کی صورت میں پیدا ہوگیا لہٰذا مختلف اسلامی ادوار کی تاریخ میں بلکہ خود دین کے مقابلہ میں اس کا ہم پلہ قرار دیاگیا یہاں تک کہ وہ تاریخیں دین کی مفسر اور مبین ہوگئیں اور دوران پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی منزلت کے برابر منزلت حاصل کرلی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حالات میں تبدیلی کیوں اور کیسے وجود میں آئی؟ اور اس کے نتائج کیا ہوئے؟
معاویہ کے مطلق العنان ہو نے کے بعد امام حسنـ بھی خاموشی پر مجبور ہوگئے، اس کے بعد معاویہ نے کچھ ایسے اقدامات کے لئے ہاتھ پیر مارے جن کی بناپر بعد میں تاریخ اسلام میں اہم تغیرات رونما ہوئے یہاں تک کہ اسلام کے متعلق مسلمانوں کے فہم و ادراک میں بھی تبدیلی پیدا ہوگئی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ خود جانتا تھا کہ اس کے ان اقدامات کا نتیجہ کیا ہوگا۔ شاید وہ اپنے حدتک دوسرے مقاصد کی تلاش میں رہا ہو ،لیکن بہرحال اس کے اقدامات کے نتیجہ میں مسلمانوں کے فہمی و کلامی اور اعتقادی ڈھانچہ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ اس طرح کہ اگر ہم کہیں کہ ان اقدامات کی طرف توجہ کئے بغیر جامع اور مکمل اسلام کی متعلق مسلمانوں کے فہم و ادراک میں تبدیلی کو سمجھا نہیں جاسکتا تو ہماری یہ بات غلط گوئی نہ ہوگی۔ (یعنی معاویہ کے اقدامات نے اہم تحولات پیدا کئے اور مسلمانوں نے انھیں اسلام سمجھا اگر ان کو نظر انداز کردیا جائے تو مسلمانوں کی فہم او ر ان کی کلامی و اعتقادی بنیاد میں کمی واقع ہوجائے گی۔)(۷۴)
معاویہ کی قدرت و طاقت کے اوج کے وقت بھی اس کے حائز اہمیت مخالفین موجود تھے البتہ وہ ان لوگوں کی کامل اور دقیق شناخت بھی رکھتا تھا۔ وہ حسب ذیل افراد تھے: عبداللہ ابن زبیر، عبدالرحمن ابن ابوبکر، عائشہ، سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ ابن عمر، قیس ابن سعد ابن عبادہ اور تمام انصار اور علی ابن ابی طالب کے خالص شیعہ۔ لیکن بجز شیعوں اور خوارج کی مخالفت کے کہ اس میںاعتقادی پہلو تھا بقیہ تمام مخالفین اور ناسازگاریاں سیاسی پہلو رکھتی تھیں۔ وہ اتنا ہوشیار، چالاک، لوگوں کی پہچان رکھنے والا اور موقع شناس انسان تھا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے مقابلہ کے لئے اٹھ سکے اور ان کو لالچ دیکر یا ڈرادھمکا کر سکوت پر آمادہ کر سکے لہٰذایہ لوگ اس کے لئے قابل تحمل تھے ۔ وہ چیزجو اس کے لئے برداشت کے قابل نہ تھے یہاں تک کہ وہ ان سے ڈرتا تھا وہ علی ابن ابی طالب کا سنگین سایہ اور آپ کا قدرت مند جاذبہ تھا۔
البتہ امام اس وقت درجۂ شہادت پر فائز ہو گئے تھے وہ خود حضرت علیـ سے نہیں ڈرتا تھا بلکہ آپ کی شخصیت سے ڈرتا تھا ایسی شخصیت جو اس کی حکومت و سلطنت کی شرعی اور قانونی اور اس کے مطلق العنان ہونے میں رکاوٹ اور سنگ راہ تھی اگر وہ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی شخصیت اور تقدس کے حریم کو نابود کر سکتا، وہ اپنا اور اپنے خاندان کا تاریخی انتقام بھی لے لیتا، اپنے اور اپنے خاندان کے غلبہ کو باقی رہنے اور اسکی مشروعیت کو حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا مانع تھا اسے بھی درمیان سے ہٹا دیتا۔(۷۵)
حضرت علیـ سے مقابلہ آرائی
سب سے پہلا اقدام امام پر سب ولعن کا رواج دے نا تھا۔ لیکن کچھ مدت گزر جانے کے بعد میں جان لیا کہ فقط یہ کافی اور کارساز نہیں ہوسکتا لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ ایک آئین نامہ کے ذریعہ اپنے حکام سے یہ چاہے کہ جو مناقب علی ابن ابی طالب کے بارے میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے نقل کئے گئے ہیں انھیں کے مشابہ فضیلتیں دوسروں کے بارے میں گڑھ کر ان کی ترویج کریں اور ٹھیک یہیں سے تحول اور تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر اسلام اور اس کے افراد کو تقدس کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ مدح صحابہ، عصر صحابہ، خلفائے ثلاثہ، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، ازواج پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم اور صدر اول کی اہم اور صاحبان نفوذ شخصیتوں کے بارے میں حدیثیں گڑھی جانا شروع ہوجاتی ہیں۔ یہ حدیثیں عام لوگوں کے دل و دماغ اور یہاں تک کہ علما اور محدثین کے ذہن اور ان کے دماغ میں گھرکر گئیں اور کبھی بھی ان کے ذہن سے یہ بات نہیں نکلی اور نہ ہی اس میں شک و شبہہ پیدا ہوا کیونکہ اس بات کے ذہن سے نکلنے یا اس میں شک کے لئے کوئی راستہ نہ تھا اور یہاں تک کہ یہ عقاید بعد کے زمانہ میں بھی کچھ اسباب کے تحت جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے وہ قوی ہوگئے ۔
ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں ایک فصل تحریر کرتے ہیں جس کو'' اہل بیت(ع) پر ڈھائے جانے والے بعض مظالم اور اذیتوں کے بیان'' کے عنوان کے تحت اس سے متعلق ایک مفصل حدیث امام محمد باقرـ سے نقل کرتے ہیں جس میں آنحضرت جو کچھ شیعوں کے ائمہ اور ان کے ماننے والوں پر گذری ہے اس کو مختصر طورپر بیان فرمایا ہے :'' ہم ہمیشہ مورد آزار واذیت اور ظلم واقع ہوئے اور قتل کئے گئے ، ہمیشہ قید و بند، تحت تعقیب اور محرومیت میں مبتلا رہے ہیں ۔میری اور میرے چاہنے والوں کی جانیں محفوظ نہ تھیں۔اسی حال میں جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے اور حقیقت سے نبردآزما لوگ میدان میں کود پڑے ان کے جھوٹ بولنے اور حقیقت سے نبردآزمائی کی بناپر ان لوگوں نے برے امیروں، قاضیوں اور حکام کے نزدیک ہر شہر میںاپنی حیثیت بنالی۔ وہی لوگ حدیثیں گڑھ کے اس کو شائع کرتے تھے ۔ جو ہم نے انجام نہیں دیا تھا اور اس کے بارے میں نہیں کہا تھا اس کی نسبت ہماری طرف دے دی گئی یعنی ہم سے روایت کرڈالی تاکہ ہم کو لوگوں کے درمیان بدنام کریں اور ان کی دشمنی کی آگ ہمارے خلاف بھڑکائیں اور یہ ماجرا امام حسنـ کی رحلت کے بعد معاویہ کے زمانے میں شدید ہوگیا۔''(۷۶) اس روایت کو نقل کرنے کے بعد مدائنی کی معتبر کتاب الاحداث سے ایک دوسری بات نقل کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ فوائد پر مشتمل ہے لہٰذا ہم اس کا ایک اہم حصہ بیان کریں گے:حضرت علیـ کی شہادت کے بعد جب معاویہ کی خلافت مستقر ہوگئی، اُس(معاویہ) نے اپنے والیوں کو اس طرح لکھا: ''میں نے اپنے ذمہ کو اس فر دسے جو ابوتراب اور ان کے خاندان کے فضائل بیان کرتا ہے بری کر لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ دور و نزدیک تمام علاقوں میں ہر منبر سے ہر خطیب نے مولائے کائنات حضرت علی ـ پر لعنت کرنا شروع کردیا اور ان سے اظہار بیزاری کرنے لگے خود ان کے اور ان کے اہل بیت کے خلاف زبان کھولنے لگے اور ان پر لعن وطعن کرنے لگے۔ اسی درمیان کوفہ تمام علاقوں سے زیادہ مصیبت میں گرفتار ہوگیا چونکہ زیادہ تر شیعہ اسی شہر میں ساکن تھے۔ معاویہ نے زیاد ابن سمیہ کو اس کا والی بنایا اور بصرہ کو بھی اسی سے متصل کردیا اس نے بھی شیعوں کو ڈھوڈنا شروع کیا اور چونکہ حضرت علیـ کے دور میں وہ خود بھی آپ کے شیعوں میں سے تھا لہٰذا ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا ان کو جہاں بھی پاتا قتل کردیتا تھا ایک عظیم دہشت پھیل گئی تھی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا اور آنکھوں میں سلاخیں ڈال دیتا اور درخت خرمہ کے تنے پر ان کو سولی دے دیتااور عراق سے ان کو نکال کر ان لوگوں کو ادھر ادھر منتشر اورتتر بتر کردیا اس حدتک کہ اب کوئی معروف شخصیت وہاں باقی نہ رہ جائے۔
معاویہ نے دوسری نوبت میں اپنے کارندوں کو لکھا کہ کسی ایک بھی شیعۂ علی اور ان سے وابستہ لوگوں کی شہادت (گواہی) کو قبول نہ کرو۔ اپنی توجہ کو عثمان اور اس کے شیعوں کی طرف موڑ دو اور جو لوگ اس کے فضائل اور مناقب کو بیان کر تے ہیں انہیں اپنے سے نزدیک کرو ان کو اکرام و انعام سے نوازو۔ ان سے مروی روایات اور خود ان کے ناموں، ان کے باپ اور خاندان کے ناموں کو لکھ کر میرے پاس ان کی فہرست بھیجو۔
اس کے کارندوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ عثمان سے متعلق فضائل بہت زیادہ ہوگئے اور ہر جگہ پھیل گئے اور یہ معاویہ کے مختلف ہدیوں کی بدولت تھا عبا اور زمین سے لیکر دوسرے بہت سارے قیمتی تحفے، تحائف تک کہ جو عربوں اور دوستوں کو بخشا تھا ۔وہ دنیا کو پانے کے واسطہ ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی میں مشغول تھے۔ کوئی بیکار اور فضول شخص بھی ایسا نہ تھا جو معاویہ کے گورنر کے پاس گیا ہو اور کوئی روایت عثمان کی فضیلت میں نقل نہ کی ہو مگر یہ کہ اس کا نام لکھا جا ئے اور اس کی قدردانی کی جاتی تھی اور وہ شخص مقام و منزلت پا جاتا تھا اور ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔
کچھ دنوں کے بعد معاویہ نے اپنے والیوں کو لکھا کہ عثمان کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہوگئی ہیں اور تمام علاقوں میں پھیل گئی ہیں۔ جس وقت میرا خط تم تک پہنچے لوگوں کو دوسرے صحابہ اور پہلے دونوں خلفا کے فضائل بیان کرنے کی دعوت دو۔ جیسی فضیلتیں مسلمانوں نے ابوتراب کے بارے میں نقل کی ہیں ویسی ہی فضیلتیں صحابہ کی شان میں جعل کر کے میرے پاس بھیج دو۔ کیونکہ اس امر کو میں بے حد پسند کرتا ہوں اور میری آنکھیں اس سے روشن ہوجاتی ہیں اور وہ خلفائے راشدین کی فضیلتیں ابوتراب اور ان کے شیعوں کی دلیلوں کو بہتر طورپر باطل کرتی ہیں اور ان لوگوں پر عثمان کے فضائل بیان کرناسخت اور دشوار کام ہے۔
اس(معاویہ) کے خطوط لوگوں کے سامنے پڑھے گئے۔ بلا فاصلہ اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اخبار و احا دیث صحابہ کی فضیلت میں بیان ہونے لگیں کہ تمام کہ تمام جھوٹی اور جعلی تھیں ،لوگ اس راہ پر چلنے لگے یہاں تک کہ یہ روایتیں منبروں سے پڑھی جانے لگیں اور مدرسہ کے منتظمین اور اس میں پڑھانے والے اساتذہ کو دیدی گئیں انھوں نے ان روایات کو بچوں کو تعلیم دینا شروع دیا اور یہ احادیث اس قدر پھیل گئیں اور اہمیت کی حامل ہوگئیں کہ ان(احادیث) کو قرآن کی طرح سیکھ لیا اپنی لڑکیوں، غلاموں، کنیزوں اور عورتوں کو تعلیم دے دی گئیں۔
اس کے بعد ایک دوسرا خط لکھا اور اپنے کارندوں سے چاہا کہ جس شخص پر علی ـ کی دوستی کا الزام ہو اس کو زیرنظر اور اس پر دباؤ بنائے رہیںاس کے گھر کو خراب کرد یں۔''.. اس طرح بہت سی احادیث جعل کر کے منتشرکر دی گئیں۔ فقیہوں، قاضیوں اور امیروں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ اسی درمیان ریاکار جھوٹے راوی اور زہد فروش حقیر اور مقدس نما، افراد اس مسابقہ میں بازی جیت لے گئے اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس سے آلودہ کرلیا تاکہ اس راہ سے مال و متاع اور مقام ان کے ہاتھ لگے اور وہ حکام سے نزدیک ہوجائیں ۔یہاں تک کہ یہ احادیث متدین افراد اور سچ بولنے والوں کے پاس پہو نچ گئیں جو لوگ نہ تو جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہی فطری طورپر اس بات کا یقین کر نے پر قادر تھے کہ دوسرے لوگ بعنوان محدث و راوی جھوٹ بولیں گے۔ لہٰذا ان سب کو قبول کرکے اورسچ سمجھ کر روایت کرنے لگے ۔اگر وہ جانتے کہ یہ احادیث جھوٹ اور باطل ہیں تو نہ ان کو قبول کرتے اور نہ ہی ان کو نقل کرتے...''(۷۷)
اس کے بعد ابن ابی الحدید نے ابن نفطویہ جو کہ برزگ محدثین میں سے ہیں، ان سے ایک جملہ نقل کرتے ہیں مناسب ہے کہ ہم بھی اس کو نقل کردیں:''اکثر جعلی حدیثیں جو صحابہ کے فضائل میں گڑھی گئیں وہ بنی امیہ کے زمانہ میں گڑھی گئیں ہیں، تاکہ اس کے ذریعہ ان کا تقرب حاصل کریں یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس طرح بنی ہاشم کی ناک زمین پر رگڑ دیں گے۔(۷۸)
حقیقت یہ ہے کہ معاویہ اور اس کے بعد بنی امیہ نے، مختلف وجوہات اور دلائل کے تحت ایسے اقدام کئے۔ وہ اپنی موقعیت اور مشروعیت کو ثابت کرنے اور اپنے سب سے بڑے رقیب و مخالف، بنی ہاشم اور ان میں بھی سرفہرست ائمہ معصومین(ع) کو میدان سے ہٹانے کے لئے مجبور تھے کہ خود کو عثمان کے شرعی اور قانونی وارثوں کی حیثیت سے پہچنوائیں اور حضرت علیـ کے ہاتھ کو اس کے خون سے آلودہ بتائیں اگر ان کاموں میں وہ کامیاب ہوجاتے تو وہ اپنے مقاصد تک پہنچ جاتے ،اسی وجہ سے خاص طورپر شعرا اور ان کی مدح و سرائی کرنے والوں نے عثمان کے فضائل بیان کرنے اور ان کو بے گناہ قتل ہونے اور یہ کہ بنی امیہ اس کے خون کے حقیقی وارث ہیں اور اس کی طرف سے یہ خلافت ان تک پہنچی ہے، اس کے لئے ان لوگوں نے داد سخن دی ہیں۔(۷۹)
گولڈزیہر ( Goldziher ) اس بارے میں اس طرح کہتا ہے:''تاریخ کے نقطۂ نظر سے یہ چیز تقریباً مسلم ہے کہ بنی امیہ نے خود کو عثمان کا قانونی اور شرعی جانشین کہلوایا اور اس کے خون کا انتقام لینے کے عنوان سے حضرت علیـ اور ان کے شیعوں کے خلاف بنی امیہ دشمنی پر تل گئے ۔ اسی سبب سے عثمانی ایک ایسا عنوان ہوگیا تھا جو اموی خاندان کے سر سخت طرفداروں پر اطلاق ہوتا تھا۔(۸۰)
یہ سب اس بات کا مرہون منت ہے کہ عثمان جس قدر، منزلت پاسکتے ہوں پالیں۔ ایسی منزلتیں جو ان کو ہر اس تنقید سے بچاسکتی تھیں جو تنقید یں ان پر کی جاسکتی تھیں اور اس میں چند اہم نتیجہ پائے جاتے تھے۔ پہلا یہ کہ اس کے ذریعہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتاکہ وہ کیوں اور کن لوگوں کے ذریعہ اور کن تہمتوں کی وجہ سے قتل کئے گئے ؟ وہ فضائل جو ان(عثمان) کے لئے نقل ہوتے تھے ان کی حقیقی شخصیت اور ان کے اعمال و کردار کے اوپر ایک ضخیم پردہ کی حیثیت رکھتا تھا اورہالہ کی روشنی کے سبب ان کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال دیتا تھا۔ دوسرے: یہ ثابت کرتا تھا کہ ایک ایسا شخص جواپنی زندگی کے آخری لمحہ تک حق و حقیقت کے سوا کسی اور راہ پر نہ تھا لہٰذا وہ مظلومانہ طور پر شہیدکیاگیا ہے اور اس کے قاتل، بے دینوں اور بددینوں کا ایک گروہ تھاالبتہ پروپیگنڈے سے لوگوں کو یہ یقین دلا سکتے تھے کہ علیـ کا اس حادثہ میں ہاتھ تھا بلکہ ان کا اہم کردار تھا۔ تیسرے : اس خون ناحق کا انتقام لیا جائے اور اس کا بدلہ لینے کے لئے معاویہ اور بنی امیہ کے علاوہ کون سب سے زیادہ حق دار ہوسکتا ہے! معاویہ عثمان کے خون کا ولی اور وارث ہے اور صرف اسی کو اس کے خون کا بدلہ لینے کے لئے اُٹھنا چاہئے اور صرف اسی کو اس کا جانشین ہونا چاہئے لہٰذا معاویہ کی خلافت اور جانشینی بھی مشروعیت پارہی تھی اور علیـ سے اس کی مخالفت اور آپ سے جنگ بھی شرعی اور قانونی قرار پارہی تھی ۔اتفاقاً اس طرح کے استدلال اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے قابل درک تھے کیونکہ وہ لوگ ابھی تک دوران جاہلیت کے میراث کے قانون سے متائثر تھے اور بنی امیہ بھی اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ انھیں زندہ کرنے کے لیئے کمر بستہ تھے اور وہ لوگ اس کو درک کرتے تھے۔ کیونکہ جاہل معاشرہ میں ثار کے قانون کی بنیاد پر مقتول کے وارثوں پر لازم ہے کہ اس کا انتقام قاتلوں سے لے لیں۔ اصل (اس قانوں میں) فقط انتقام لینا ہے دوسری کسی اصل کی رعایت نہیں ہے نہ کہ کسی اور دوسری اصل (قاعدہ) اور حدود کی رعایت کرنا۔(۸۱)
اب تک جو کچھ بھی بیان ہوا اس کا بہترین ثبوت جنگ صفین میں عمرو ابن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے ذریعہ حکمیت کے بارے میں موافقت نامہ کا تحریر کرنا ہے۔ ایک ایسا نمونہ جس کی بعد میں معاویہ اور سارے خلفائے بنی امیہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ ان دونوں کی بہت سی بحث و گفتگو کے بعد عمرو عاص نے اپنے ساتھی سے چاہا جس چیز پر ہم توافق کرتے جائیں وہ کاتب کے ذریعہ لکھوایا جائے۔ کاتب اسی عمرو کا بیٹا تھا، خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور پہلے دو خلفا(ابو بکر وعمر) کی حقانیت کی گواہی لکھنے کے بعد عمرو ابن عاص نے اپنے بیٹے سے کہا لکھو: کہ عثمان، عمر کے بعد تمام مسلمانوں کے اجماع اور صحابہ کی مشورت اور ان کی مرضی سے خلافت کے عہدہ پر فائز ہوئے اور وہ مومن تھے۔'' ابوموسیٰ اشعری نے اعتراض کیا اور کہا: یہاں اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے نہیں بیٹھے ہیں، عمرو نے کہا:'' خدا کی قسم یا وہ مومن تھے یا کافر تھے۔
ابوموسیٰ نے کہا :''مومن تھے۔''
عمرو نے کہا ''ظالم قتل ہوئے یا مظلوم؟''
ابوموسیٰ نے کہا ''مظلوم قتل ہوئے ہیں۔''
عمرو نے کہا :''آیا خداوندعالم نے مظلوم کے ولی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ اس کے خون کا بدلہ لے؟ ''
ابوموسیٰ نے کہا: ''کیوں نہیں''
عمرو نے کہا: ''آیا عثمان کے واسطے معاویہ سے بہتر کوئی ولی جانتے ہو؟'' ابوموسیٰ نے کہا ''نہیں''
عمرو نے کہا:''آیا معاویہ کو اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عثمان کے قاتل کو جہاں بھی ہوں اپنے پاس طلب کرے تاکہ یا تو اس کو قتل کردے یا اس کے مقابلہ سے وہ عاجز ہوجائے؟ ''
ابوموسیٰ نے کہا :''کیوں نہیں، ایسا ہی ہے''
عمرو نے کہا:'' ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ علی نے عثمان کو قتل کیا ہے۔(۸۲)
اور ان تمام باتوں کو اس عہد نامہ کا جز قرار دیا
مقام صحابہ کا اتنا اہم ہوجانا
یہ ان حالات کا ایک گوشہ ہے جس میں عثمان اور گذشتہ خلفا اور صحابۂ پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے نفع میں حدیث کا گڑھے جانے کا کام انجام پایا۔ معاویہ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لئے مجبور تھا کہ عثمان کی حیثیت اور شخصیت کو بڑھائے لہٰذا مدائنی کے نقل کے مطابق کہ (معاویہ نے) بلا فاصلہ خلافت پر پہنچنے کے بعد حدیثیں گڑھنے کا حکم صادر کردیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ اقدام فقط شخص عثمان تک محدود نہیں رہ سکتا تھا۔ کیونکہ اس زمانہ کے لوگوں کے لئے، جن میں سے بعض نے عثمان اور ان کے پہلے والے خلفا کو دیکھا تھا یہ ان لوگوں کے لئے قابل درک وہضم نہیں تھا کہ اس (عثمان) کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہو اور اس کے پہلے والے خلفا اور دوسرے صحابۂ نامدار کی یہ منزلت نہ ہو۔ یہ مسئلہ عثمان کے فضائل کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات اور شک وشبہہ ایجاد کرسکتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ (معاویہ) مجبور ہوگیا کہ عثمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی شان و شوکت اور مقام و منزلت بلند کریں اور ایسا ہی کیا۔
اس ضرورت کے علاوہ اس عمل کے دوسرے نتائج بھی تھے۔ ان میںسے اہم ترین نتیجہ یہ تھا کہ ایک ایک صحابہ کی قدر و منزلت کو آشکار کرنے کے ذریعہ بلند ترین قدر ومنزلت رکھنے والے صحابی کی معروف ترین شخصیت اور حیثیت کو دبانے اور کم کرنے میں مدد کررہے تھے۔(۸۳) یہ کہ جو معاویہ نے کہا:'' ابوتراب کی کسی بھی فضیلت کو جو کسی مسلمان نے نقل کی ہو اسے ہرگز نہ چھوڑنا مگر یہ کہ اس کے خلاف صحابہ کی شان میں حدیث میرے پاس لاؤ۔'' درحقیقت اس کا مقصد حضرت علیـ کی حیثیت اور شخصیت کو کم کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے صراحت کے ساتھ کہا:'' اس بات کو میں دوست رکھتا ہوں اور وہ میری آنکھوں کو روشن کرتا ہے جو ابوتراب اور ان کے چاہنے والوں (شیعوں)اور ان کی دلیلوں کو بہتر طورپر باطل کرتا ہے۔'' البتہ ان دلیلوں کے تحت جن کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔
بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ دوسروں کی سطح بھی اوپر آگئی اس حد تک کہ بسا اوقات پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی سطح کے نزدیک قرار پاگئی اور صدر اول کی تاریخ ایک شان او ر قدر منزلت اور تقدس کی حامل ہوگئی اور اس کی قدر و منزلت خود اسلام کے ہم پلہ ہوگئی اور اس طرح اسلام کی ہمزاد ہوگئی کہ بغیر اس کی طرف توجہ دیئے اسلام کا سمجھنا ممکن نہ تھا۔
دین فہمی میں بدلاؤ
اس طرح سے دین فہمی میں سیاسی رقابتیں ایک بہت بڑی تبدیلی کا سرچشمہ بن گئیں۔ یعنی صدر اسلام کی روشنی میں دین کا سمجھنا، یعنی خلفائے راشدین، صحابہ اور تابعین خصوصاً خلفا ئے راشدین اور صحابہ کے دور میں دین کا سمجھنا۔ اگرچہ دوسرے بہت سے اسباب اور عوامل بھی مؤثر تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے اہم ترین اور مؤثر ترین اسباب علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لئے معاویہ کے اقدامات تھے۔ حضرت علیـ کی مذمت میں اس کی جعلیات اور من گڑھت روایات باقی نہ رہ پائیں اور نہ ہی باقی رہ سکتی تھیں اگرچہ حضرت پر وہ جھوٹی تہمتیں بالکل بے اثر بھی نہیں تھیں۔ خاص طورپر ابتدائی صدیوں میں،( لیکن اس کی جعلیات اور من گڑھت فضیلتیں) دوسروں کو امام کے برابر کرنے کے لئے باقی رہ گئیں اور مورد اعتقاد اور اتفاق قرار پائیں۔ جیساکہ ہم نے اس سے قبل بھی اشارہ کیا کہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان دین اسلام کو سمجھنے میں یہ ایک بنیادی فرق تھا اور واقعاً ایسا ہی ہے۔ اہل سنت نے شیعوں کے بالکل برعکس معاویہ کے اقدامات کو چاہے جان بوجھ کر یاانجانے میں صحیح سمجھ بیٹھے اور آخرکار اُسے قبول کرلیا۔ لہٰذا اسلام کو صدر اسلام کی تاریخ کی عینک سے دیکھنے لگے اور شیعہ صدر اسلام کی تاریخ کو اسلامی اصول و معیار پر پرکھتے ہیں۔(۸۵)
اگرچہ بعد میں تجزیہ و تحقیق اور تاریخی تنقید کے ترقی پر پہونچنے کی وجہ سے جس کا زیادہ تر حصہ معتزلہ کے اقدامات کا مرہون منت تھا صدر اسلام کی غیر متنازعہ ہیبت ایک طرح سے ٹوٹ گئی، لیکن یہ امر وقتی اور جلد ی ہی گذر جانے والا تھا اور اس میں دوام و بقا نہیں تھی۔ اس کی چند وجوہات ہیں سب سے اہم یہ ہے کہ انھوں نے ایسے زمانہ میں میدان میں قدم رکھا تھا کہ عام لوگوں کے دین و عقائد و افکار مستحکم ہوچکے تھے۔ وہ ایسے عقاید کی اصلاح کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کی رگ وپے میں سرایت کرچکے تھے اور ان کی شخصیت نے بھی اسی بنیاد پر قوام حاصل کیا تھا اور ان کا ناکام ہونا بھی ایک فطری امر تھا۔ اور احتمال قوی کی بناپر جس زمانے میں وہ میدان میں آئے تھے اگر اس زمانہ سے پہلے وہ میدان میں آگئے ہوتے تو وہ زیادہ کامیاب ہوتے۔(۸۶)
جیساکہ ہم نے کہا کہ اہل سنت کے دینی عقائد کا مرکزی نقطہ، اس زمانہ اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی صدر اول کے تقدس کی فکر حاکم تھی۔(۸۷) اگر ان کی اس فکر کا شیرازہ بکھرجاتا تو ان کا اعتقادی ڈھانچہ درہم برہم ہوجاتا، اس بناپر نہ تو معتزلہ اور نہ ہی کوئی دوسرا گروہ اس سے مقابلہ کے لئے نہیں اُٹھ سکتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ کونسی نظر صحیح ہے اور کونسی غلط ہے؟ عام لوگوں اور بعض فقہا اور محدثین کا قابل اعتنا گروہ جو عوامی ذہنیت کے حامل تھے، اس طرح سے صورت اختیار کرلی تھی جو ایسے زاویۂ نگاہ کی محتاج تھی اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ ان کا ایمان خطرہ میں تھا بلکہ داخلی اعتبار سے ان کی شخصیت بھی درہم برہم ہوجاتی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مقابلہ میں دوسرے عقائد نہیں تھے تاکہ اس فکر کا قائم مقام ہوجائے۔ معتزلہ کے نظریات کے قبول کرنے کے یہ معنی تھے کہ اہل سنت کے اعتقادات کی عمارت بالکل سے مسمار ہوجائے اور معتزلہ بھی اس قدر مورد و ثوق اور اعتماد نہ تھے اور نہ ہی ان کے بیانات اس قدر صریح قابل فہم تھے کہ وہ لوگ اس کو آنکھیں بند کرکے قبول کر لیں۔ خاص طورپر یہ کہ معتزلہ کا کوئی ثابت اور مدون مکتب فکر بھی نہیں تھا اور ان میں ہر ایک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نظریات کے حامل تھے۔(۸۸)
اور آخر کا ایک دوسری اہم بات کا بھی اضافہ کرنا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ ہر مومن اور صاحب عقیدہ انسان، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو عقیدہ کی روسے وہ اپنے عقائد کی طرف دفاعی میلان رکھتا ہے۔ یہ اس کی دین داری کا لازمہ اور اس کا نتیجہ ہے۔ وہ دین کو قبول کیا اور اس کی تمام مشکلات اور رکاوٹوں کو تحمل کیا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی کو حاصل کرلے۔ درحقیقت نجات اور فلاح ہی مطلوب ہے اور چونکہ ایسا ہے لہٰذا وہ ایمان و عقل کے انتخاب میں، ایمان کو اختیار کرے گا۔ پھر بھی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ دو نوں باہم ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں یا ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں، یہاں پر مسئلہ ایک مومن انسان کے ذہن کی خصوصیات کو کشف کرنا، اس کی افکار، اس کی کیفیت اور اس کے موقف کو معلوم کرنا ہے۔ وہ ان دونوں عقیدوں کے انتخاب کے وقت ایک کو مختلف اسباب کے تحت شرعی میزان کے مطابق جانتا ہے اور دوسرے کو عقل کے معیار کے مطابق جانتا ہے۔ آخرکار وہ پہلے والے کا انتخاب کرلیتا ہے۔ ایسے موارد اور مواقع پر کبھی بھی احتیاط شرعی ،عقلی غور و خوض کے مد مقابل مغلوب نہیں ہوگی۔(۸۹)
معتزلہ بالکل انھیں مشکلات سے روبرو تھے (اور یہ وہ مشکل ہے جس سے آج بھی بہت سے اصلاح طلب لوگ روبرو ہیں اور اس کا اہم ترین سبب دینی اصلاح طلب تحریکوں کی ترقی کے لئے اس کی حفاظت کا رجحان اور اس کی لگاؤ ہے) اگرچہ عقلی اور منطقی طورپر ان کے عقائد ان کے مخالفین پر برتری رکھتے تھے اور ظاہری او ر شرعی اصولوں اور موازین سے ان کے نظریات بہت مطابقت رکھتے تھے، لیکن ان سے بدگمانی، ان کے بعض لوگوں کی بے پروائی اور لاابالی پن کی بناپر وجود میں آئی تھی، جو چیزیں پرانے زمانہ سے چلی آرہی میراث اور ان کے نظریات کے خلاف تھیں اورجن چیزوں کو عوام الناس نے ان لوگوں سے لیا تھا جن کو وہ لوگ اپنا سلف صالح سمجھتے تھے آخرکار ان کو ان کے مدار اور گردش سے باہر نکال کر ان کے مخالفین کو قوت بخشی۔ یہاں پر مناسب یہ ہے کہ ان کے کچھ نظریات جو صحابہ کے بارے میں ہیں ابن ابی الحدید کی زبانی نقل کریں:
''معتزلہ لوگ صحابۂ کرام اور تابعین کو دوسرے تمام لوگوں کی طرح دیکھتے تھے۔ وہ لوگ جو کبھی خطا کرتے اور کبھی صراط مستقیم پر چلتے اور ایسے اعمال میں لگ گئے کہ ان میں سے کچھ قابل تعریف اور کچھ قابل مذمت قرار پاتے ہیں۔ وہ لوگ اس طرح موقف اختیار کرنے سے یکسر خوف ناک نہیں تھے۔ لیکن دوسرے لوگ (مخالفین) ایسے نہیں تھے اس لئے کہ انہوں نے صحابہ اور تابعین میں سے بزرگوں کو ایسی شخصیت دے دی تھی کہ ان پر تنقید کرنا ممکن تھا۔''
''معتزلہ کہتے تھے: ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں اور ہیں تک کہ بعض صحابہ بعض دوسرے صحابہ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر صحابہ کی منزلت ایسی ہوتی کہ ان پر تنقید کرنا اور لعنت بھیجنا صحیح نہ تھا تو اس کا لازمہ یہ تھا کہ ان کے رفتار و کردار سے معلوم ہوجاتا کہ وہ ایک دوسرے کو ہمارے زمانہ کے لوگوں سے اچھا سمجھتے تھے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں طلحہ و زبیر وعائشہ اور ان کا اتباع کرنے والوں نے علی ـ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا یہاں تک کہ ان سے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے معاویہ وعمرو ابن عاص بھی حضرت علیـ سے جنگ اور مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر نے ابوہریرہ کی نقل کی ہوئی روایت پر طعنہ دیا اور خالد بن ولید کو برا بھلا کہا اور اس کو فاسق گردانا، عمرو ابن عاص اور معاویہ پر بیت المال میں خیانت اور چوری کا الزام لگایا۔ قا عد تاً صحابہ میں سے بہت کم ایسے لوگ تھے جو ان کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہ گئے ہوں اس طرح کے بہت سے نمونوں کو دریافت کیا جاسکتا ہے۔
اسی طرح تابعین بھی صحابہ ہی کی طرح ایک دوسرے سے آپس میں مخالف رویہ اختیار کئے ہوئے تھے اور وہ اپنے مخالفین کے مقابلہ میں اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں عوام الناس نے ان کو ایک بلند مقام و منزلت پر لاکر کھڑا کردیا۔ کے ہم سے لوگ کرتے ان میں سے اچھے ہیں ان کی تعریف کر تے ہیں۔ صحابہ لوگ بھی عوام الناس کی طرح ہیں ان میں کے خطا کار لائق مذمت ہیں اور اچھے لوگ قابل تعریف ہیں دوسروں کے مقابلہ میں ان کی برتری اور ان کا امتیاز صرف رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کو (درک کرنے) دیکھنے کی بناپر ہے نہ یہ کہ کسی اور چیز کی بناپر، یہاں تک کہ شاید ان لوگوں کے گناہ دوسروں کے گناہوں سے زیادہ سنگین ہوں کیونکہ انھوں نے دین کے معجزات اور سچی نشانیوں کو نزدیک سے دیکھا ہے، لہٰذا ہمارے گناہ ان کے گناہ کے مقابلہ میں زیادہ ہلکے ہیں اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہ میں زیادہ معذور ہیں۔(۹۰)
احمد امین مذکورہ بالا مطلب کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں معتزلہ صحابہ اور تابعین کی رفتار و گفتار پر پوری آزادی کے ساتھ تنقید کرتے تھے اور ان میں پائے جانے والے باہمی تضاد کو بھی آشکار کرتے تھے یہاں تک کہ شیخین کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکے اور اس وقت ابوبکر و عمر پر جو انھوں نے تنقیدیں کی ہیں ان کے چند نمونوں کو بیان کیا ہے۔(۹۱)
صحابہ اور تابعین کے متعلق ان کا ایسے نظریہ کا انتخاب غالباً بلکہ بطور کامل ا عقلی رجحانات کا نتیجہ ہے وہ کسی بھی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے یا کسی اصل اور قاعدہ کو عقل پر مقدم کریں۔ ٹھیک یہی سبب تھا کہ انکے اور انکے مخالفین کے بارے میں اس طرح کہتے تھے: ا شعری'' نرد''( ایک قسم کا کھیل) ہے اور معتزلی شطرنج چونکہ نرد کا کھیلنے والا قضا و قدر پر بھروسہ کرتا ہے اور شطرنج کا کھیلنے والااپنی ذاتی کوشش اور فکر پر اعتماد کرتا ہے۔(۹۲)
دوسرے تنقید کرنے والے
معتزلہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جو فکری آزادی کی طرف مائل تھے انھوں نے صدر اسلام اور صحابہ و تابعین کے زمانہ کو تنقیدی زاویہ سے دیکھا ہے۔ ان (تنقید کرنے والے لوگوں) میں سے ایک ابن خلدون ہیں۔ وہ جب علم فقہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں:''. اس سے قطع نظر صحابہ اہل نظر اور اہل فتویٰ نہیں تھے اور ان تمام لوگوں کے لئے دینی فرائض کا جاننا ممکن بھی نہیں تھا۔ بلکہ یہ امر صرف حافظان قرآن اور ان لوگوں سے مختص تھا جو لوگ ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ اور قرآن کی دوسری ہدایات سے واقف تھے۔ چاہے انہوں نے یہ معلومات براہ راست خود پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم سے حاصل کی ہوں اور یا پھر ایسے بزرگوں سے حاصل کی ہوں جنہوں نے خود رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم سے ان کی تعلیمات کو سنا تھا،اور اسی سبب ایسے لوگوں کو قرّا کہا جاتا تھا۔ یعنی وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے تھے۔ کیونکہ عرب عموماً امی قوم تھیاور اسی بناپر جو لوگ قاریان قرآن تھے اسی نام سے مشہور ہوگئے۔ کیونکہ یہ امر اس زمانہ میں ان کی نظر میں حیرت انگیز سمجھا جاتا تھا۔ صدر اسلام کی یہی صورتحال تھی پس کچھ دنوں بعد اسلامی شہروں میں وسعت پیدا ہوگئی اور عروج اور ترقی حاصل کرلیا اور جہالت نے قرآن اور کتاب کے باربار دہرانے کے نتیجہ میں عربوں سے اپنا بوریا بسترا لپیٹ لیا اور خود ان عربوں میں اجتہاد اور استنباط کی قوت پیدا ہوگئی اور فقہ منزل کمال پر پہونچ گئی اور یہی عرب صاحبان علوم و فنون کے زمرے میں شمار ہونے لگے۔ اور اس وقت حافظان قرآن کے نام میں تبدیلی ہوئی اور ان کو قاری کی جگہ فقیہ یا عالم کے نام سے پکارا جانے لگا...''(۹۳)
ابن حزم بھی اسی گروہ کی ایک فرد ہیں۔ البتہ انھوں نے ایک دوسری جگہ سے معتزلہ اور ابن خلدون سے ملتا جلتا موقف اختیار کرلیا۔ وہ مکتب ظاہری کے علما اور فقہا میں سے ایک ہیں جوکہ شرع اور شریعت کے مصادر اور مآخذ کو نصوص قرآن و سنت اور اجماع میں منحصر جانتے تھے اور قیاس کو قابل قبول نہیں جانتے تھے وہ صحابہ کے قول و فعل کے قطعی طور پر صحیح ہونے کے نظریہ کو جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے قابل قبول نہیں جانتے ہیں اسی بناپر ایسے نقطۂ نظر کے حامل ہوگئے ہیں۔
محمد ابوزہرہ اس سلسلہ میںکہتا ہے: ''ابن حزم کا عقیدہ یہ تھا کہ چاہے صحابہ ہوں یا غیر صحابہ، زندہ ہوں یا مردہ، کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے اور وہ اس بات کے معتقد تھے کہ قول صحابی کو جب تک اس کی نسبت پیغمبر کی طرف معلوم نہ ہو اخذ کرنا ایسی تقلید ہے جو دین خدا میں جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس (حکم خدا) کو صرف کتاب و سنت اور ایسے اجماع سے لینا چاہئے جو ان دونوں کی حکایت کرتا ہو یا کسی ایسی دلیل سے جو ان تینوں سے مشتق ہو۔ لہٰذا صرف صحابی کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور اس کے ذریعہ دلیل قائم نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ وہ بھی ایک عام انسان کی طرح ہے۔ اسی نظریہ کی طرح شافعی کا بھی قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ اس بارے میں کہا کرتے تھے: میں اس شخص کے قول کو کیسے اختیار کروں کہ اگر میں اس کا ہم عصر ہوتا تو اس کے خلاف دلیلیں قائم کرتا۔لیکن صحیح یہ ہے کہ شافعی اقوال صحابہ کو اگر وہ لوگ سب کے سب کسی مسئلہ پرمتحد ہوتے تھے اختیار کرتے تھے اور اگر کسی مسئلہ پر ان میں اختلاف ہو تا تھا تو ان اقوال میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کرلیتے تھے... بلا شک و شبہہ فقط صحابی کا قول ہونا اتباع کے واسطے کافی نہیں ہے، اس لئے کہ رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم کے قول کے سامنے کسی کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طرح کہ مالک ابن انس نے کہا: ہر انسان کی کچھ باتیں قبول کرلی جاتی ہیں اور بعض رد کردی جاتی ہیں مگر اس روضہ کے صاحب (یعنی اس کتاب کے مؤلف) کے اقوال بالعموم اوربلا استثناء قبول کئے جاتے ہیں۔(۹۴)
فکری اوراعتقادی نتائج
لیکن حائز اہمیت مسئلہ فقط یہی نہیں تھا کہ اسلام کو تنہا صدر اسلام کی تاریخ کی روشنی میں دیکھ کر اس کی صحیح پہچان کی جائے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات یہ تھی کہ خود یہ زمانہ اپنے اندر بہت سے تناقضات کو سموئے ہوئے تھا۔ یہ زمانہ باہمی رقابت، کشمکش اور اختلافات سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس زمانہ کے بزرگ لوگ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے اور ایک دوسرے کے خون سے ہاتھ کو رنگین کر رہے تھے۔ اگر یہ زمانہ بہترین اور مقدس ترین زمانہ تھا اور بجز حقیقی اسلام کے تحقق کے اور کچھ نہ تھا اور اس زمانہ کے مسلمان بہترین اور شریف ترین مسلمان تھے تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوکر تلوار کھینچ لیں؟ آپس میں دو حق کس طرح ٹکرا سکتے ہیں؟ ایسے مسائل کا اہل سنت کے کلامی و فقہی و نیز دینی ثقافت کی تشکیل میں بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے، اس اصل کو قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کی تفہیم و تفسیر صدر اول کی تاریخ کے ماورا ہو۔(۹۵)
اس مشکل کو حل کرنے کے واسطے مجبور ہوئے کہ وہ مختلف راستوں کو اختیار کریں۔ وہ اس بات پر مجبور ہوئے کہ کہیں دونوں برحق ہیں، اختلافات اور نزاع کے باوجود دونوں نے اپنے اپنے فریضہ اور اجتہاد کے مطابق عمل کیا ہے لہٰذا و ہ لوگ ماجور اور بہشتی ہیں۔ البتہ ممکن ہے انسان ایک، دو یا چند مواقع پر اس فرضیہ کے تحت اس کو مان لیاور یہ کہے کہ مصداق میں اشتباہ اور غلطی پیش آگئی ہے۔ لیکن موضوع بحث یہ ہے کہ صدر اسلام کی تاریخ ایسے حوادث، واقعات اور ایسے برتاؤ سے بھری پڑی ہے اور ایک اعتبار سے رقابتوں اور ٹکراؤ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی ان لوگوں کے درمیان جن کے بارے میں مصداق میں شک و شبہہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے اور یہ ایک ایسی مشکل ہے کہ نہ فقط اہل سنت کی اس زمانہ کی تاریخ کو وجود میں آنے میں زیادہ مؤثر ہوئی ہے، (یعنی ان پر یہ تاریخ زیادہ اثر انداز ہوئی ہے) بلکہ وہ تمام چیزیں جو کسی نہ کسی طرح اسلام سے متعلق ہیں ،وہ اس سے سخت متأثر ہوئی ہیں۔(۹۶)
اس زاویۂ نظر سے اس زمانے کی تاریخ اور اس کی پیروی میں تمام تاریخ اسلام نہ بالکل سیاہ اور تاریک ہے اور نہ ہی بالکل بے داغ (سفید) بلکہ ملی جلی( خاکستری )ہے۔ گویاحق و باطل کی شناخت کا کوئی مشخص ضابطہ اور معیار نہیں پایا جاتا ہے۔ یا تمام کے تمام مطلق حق ہیں اوریا نسبی اعتبار سے کم وپیش حقانیت کے حامل اور حق و باطل کے درمیان غوطہ زن ہیں آپس میں بغیر کسی طرح کی ترجیح ر کھتے ہوئے۔ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ افراد کے درمیان امتیاز دینے کی ہر طرح کی کوشش اور ان کے اعمال و رفتار اور واقعات و حوادث کے بارے میں بھی یک سرتنقید ممنوع قرار پاگئی۔ بنا اس پر تھی کہ سبھی لوگ اچھے ہیں اور ان میں جو اختلاف پایاجاتا ہے وہ صرف ان کے ا جتھاد کی وجہ سے ہے نہ کہ ایمان تمام ذاتی خصوصیات اور صفاتجو ان کے ایمان کی وجہ سے ان میں پیدا ہوئی ہیں اور چونکہ ایسا ہے تو ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کے اعمال کے بارے میں تحقیق کرکے چوں چرا کرنے کے لئے اُٹھ کھڑے ہوں اور ان کے اعمال کو ان کی حقانیت کی پرکھ کا معیار قرار دیں۔ اس طرح سے ذہنیت اور فکری اور نفسانی اعتبار سے متضاد مسائل کے سمجھنے کے بارے میں ان لوگوں کے حق و با طل ہونے کے اعتبار سے چھان بین کرنے کے حالات ختم ہوگئے۔ سیاسی مباحث کے فقہی اور کلامی معیار اور ان کی بنیادکو، چاہے وہ امامت اور خلافت کے بارے میں ہواور چاہے (دوسرے دینی مسائل) سیاسی مسائل کے بارے میں ہو، بہت ہی شدت سے متأثر کردیا۔(۹۷)
اہل سنت کا فقہی اور کلامی ڈھا نچہ اور اس کے اتباع میں ان کی دینی اور نفسیاتی بناوٹ اس فکر پر بھروسہ کئے ہوئے ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان رقابت میں ایک مطلق حق اور دوسرے کو باطل محض، قرار نہیں دیا جاسکتااور یہ پہلے درجہ میں اس دور کو جو آشفتہ اور پُر کشمکش رہا ہے اور اس کے افراد اور شخصیتوں کو مقدس مان لینے کی وجہ سے متأثر ہے۔ یہ نفسیاتی ڈھانچہ فی الحال اہل سنت کے لئے مشکلات پیدا کررہا ہے۔، یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک نئی اور ایسی مشکل ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس لئے کہ گذشتہ دور میں یا اصولی طورپر ایسی مشکل سے روبرو نہیں ہوئے تھے یا کم از کم یہ مشکل آج کل کی طرح شدید اور سخت پریشان کن نہ تھی۔ دور حاضر کی زندگی، نیا معاشرہ اور نئی تاریخ نے ایسی سخت اور شدید مشکل کھڑی کردی ہے۔(۹۸)
زمانۂ ماضی میں جوانوں کی انقلابی ضروریات کی فی الفور جوابدہی ضروری، بلکہ اتنی زیادہ سخت اور قطعی اور سنجیدہ نہیں تھی۔ یا بالکل سے اس طرح کی ضرورت ہی نہیں تھی ، یا اگر موجود بھی تھی تو آج کل کی طرح مختلف گوشوں میں پھیلی اور قدرت کی حامل نہیں تھی۔ آج یہ ضرورت پوری تیسری دنیا اور اسلامی ممالک میں موجود ہے اور اسلام اس سے بے اعتنابھی نہیں رہ سکتا۔ خصوصاً یہ کہ عمومی طورپر مسلمان جوان لوگ کم سے کم ان آخری ایک د ودہائیوں میں اس بات کے جواب کو اسلام سے چاہتے ہیں۔ وہ اپنی نئی ضرورتوں کے اسلامی جواب کی تلاش میں ہیں۔ چونکہ پہلے تو وہ اس جواب کو اپنی ضرورت کے ساتھ بہت ہی ہماہنگ اور مناسب پاتے ہیں اور دوسری دینی ضرورت جو ان کو ہر غیر اسلامی چیز سے روک دیتا ہے۔
آج کے وہ سنی جوان جو انقلاب سے لگاؤ اور مسلحانہ رحجان رکھتے ہیں دوسروں سے زیادہ اس مشکل سے جوجھ رہے ہیں۔ وہ اپنی معاشرتی اور ثقافتی اور سیاسی سرنوشت کے اعتبار سے ایک عظیم تبدیلی (انقلاب) کے خواہاں ہیں۔ ان کے ایسے ارمان اور دبی تمنائیں ان کو انقلابی اقدامات کے لئے آگے بڑھا تے ہیں۔ لیکن وہ لوگ عین اسی عالم میں ایک اسلامی راہ حل کی تلاش میں ہیں۔ ایک ایسا راہ حل جو اسلامی بھی ہو اور انقلابی بھی۔ بہت بڑی مشکل اس سوال کے جواب کا حاصل کرنا ہے، اس لئے کہ اس سوال کا جواب حاصل نہیں ہوگا مگر یہ کہ کلی طورپر فقہی، کلامی دینی اور تاریخی فہم میں بنیادی طور سے تجدید نظر کی جائے اور عام لوگ کے نفسیات کی شناخت اس عظیم تحول اور انقلاب کے ساتھ ہماہنگ ہوکر پورے طورپر بدل جائیں۔(۹۹)
قطعی طورپر یہی سبب ہے کہ بہت سے اسلامی دانشوروں، انقلابی سنی لوگوں نے، اپنے ضروری اور سخت ضرورتوں کا جواب پانے کے لئے اپنی تاریخی افکار میں ایک قسم کی تجدید نظر کی ہے۔ یہ اس کے سبب تھا کہ انہوں نے اپنی تجزیہ و تحلیل اور ارزیابی کے واسطے بہت صریح و قاطع اور کشادہ راہ پالی ہے کہ باطل کو باطل دیکھیں اگرچہ باطل نے اسلام کی نقاب اپنے چہرہ پر ڈال رکھی ہو، حق کو حق کہنا چاہئے اگرچہ دوسرے لوگوں یا تاریخ نے اس کے ظاہری چہرہ کو مشتبہ کردیا ہو بغیر کسی خوف و ہراس کے باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور حق کی مدد کے لئے ہمہ تن اٹھ کھڑے ہوں۔ اس قاعدہ اور ضابطہ کی قبولیت کہ اسلام کی نقاب صریح فیصلہ اور پختہ تصمیم کے لئے مانع ہو یہ ہر اس اقدام کے غلط ہونے کے مساوی ہے جو کسی ایسے حاکم کے خلاف اُٹھ کھڑا ہو جو ظواہر اسلام سے تمسک کرکے ہر طرح کے جرم و جنایت اور خیانت کو انجام دینے میں کامیاب ہوجائے ۔تاکہ یہ اصل جو صدر اول کی تاریخ کو غیر قابل تنقید ہونے اور قانونی (شرعی) ماننے کا نتیجہ ہے، یہ ممار نہ ہو جائے جب تک یہ مسلم قضیہ ختم نہ ہوگا (یعنی صدر اول کی تاریخ پر نقد و تبصرہ غیر قانونی اور غیر شرعی جانا جاتا رہے گا) یہ مشکل ویسے ہی استوار و برقرار رہے گی، یہ ٹھیک اسی سبب کی بناپر ہے کہ اہل سنت کی فقہی و کلامی کتابوں کے مختلف موضوعات جیسے: بیعت، اجماع، اجتہاد، تخطئہ و تصویب، اجماع حل و عقد، مقام خلافت اور خلفا کی حیثیت منزلت، اولی الامر اور اس کی اطاعت کا ضروری ہونا اور ایسے ہی دوسرے موضوعات کی اس طرح سے دوسرے مختلف انداز میں تعریف اور اس کی چوحدی بیان کی ہے۔(۱۰۰)
وہ انقلابی اور مفکرین لوگ جنھوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس اصل کو محفوظ رکھتے ہوئے مقابلہ کے لائحہ کی تدوین کریں ان لوگوں کو عملی طورپر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنی ذاتی فداکاری ، استقامت اور اپنے ایمان پر تکیہ کرتے ہوئے جو ان کے نظریاتی اعتقادات میں کمزوری اور کمی واقع ہوئی ہے اس کی بھرپائی کریں۔ اور کم از کم یہ ہمارے زمانہ میں میسر نہیں ہے۔ اگر معاشرتی اور سیاسی مقاصد تک پہنچنے کے لئے انقلابی لوگوں کے لئے ضروری شرط ان کی پائے مردی اور استقامت پر موقوف ہے، بیشک اعتقادی نظریہ اور اس کی حساسیت کے لئے یہ شرط کافی ہے جو اس کے مقاصد اور اس زمانہ کی روح سے سازگار ہو عین اس عالم میں کہ قدرت میں استمرار و بقا، پائے مردی و استقامت اور اس کی جواب دہی پر قادر ہو۔(۱۰۱)
البتہ وہ مسئلہ جس کے متعلق اوپر اشارہ کیا گیا ہے صرف اسی میں محدود نہیں ہو گا۔ صدر اسلام کے حوادث پر نقد و تبصرہ کو غیر قابل قبول ہونے کو قانونی حیثیت دینا فکری، علمی اور دینی اعتبار سے مطلوب اور ضروری تبدیلی لانے سے مانع ہے کہ دور حاضر میں مسلمان لوگ جس کے نیازمند ہیں۔ فقط اس ضرورت کا ایک حصہ انقلابی پہلو اور مبارزہ جوئی کا پہلو ہے جیساکہ ہم نے بیان کیا حتیٰ اس ضرورت کا جواب دینے اور اس کو صحیح راستہ پر لگانے کے لئے ان کے عقائدمیں بھی تبدیلی پیدا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جن مختلف موضوعات کی تنقیدا نہ جانچ پڑتال ہونی چاہئے انھیں میں سے دین اور اس کی تاریخ بھی ہے جو اس جدید زمانہ کی اہم ترین ضروریات میں سے ہے، اس کے بارے میں کوئی مناسب راہ حل نکالنا چاہئے۔ عصر نو کی تنقیدوں کے مقابل میں لوگوں کے ایمان کا کچھ خاص یقینیات کی بنا پر اصرار نہیں کیا جا سکتا جو نہ تو دین کے بنیادی اصول میں سے ہیں بلکہ زمانہ کے ایک خاص حصہ کے مسلمانوں کے اجماع کا نتیجہ ہے اس کا دفاع کیا جا ئے ۔
ہر دین میں کچھ ایسے مقدسات اور یقینیات پائے جاتے ہیں جو قابل تنقید و تبصرہ بھی نہیں ہیںاور ان میں کوئی اندیشہ اور خدشہ بھی نہیں ہے۔ یہ دین کی حقیقت کی طرف پلٹتی ہے اور زمانہ کے تحولات اور تبدیلیوں کو اس میں بالکل دخالت نہیں رہا اور نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ عقیدہ کے اس جز سے متعلق ہے جس کی بنیاد اصل دین میں نہیں ہے بلکہ مومنین کے اجماع میں پا ئی جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے علمی اور تاریخی تنقیدوں اور تبصروں کا ہمیشہ کے لئے دفاع نہیں کیا جاسکتا۔ کسی چیز کے بارے میں اس تنقیدی رجحان کے مقابلہ میں اُٹھ کھڑے ہونا دین سے فرار یا دین کے پاسداروں پر ہی معصیت اور اعتقادی ہرج و مرج کے علاوہ کچھ اور عاید ہونے والا نہیں ہے(۱۰۲)
اس سے قطع نظرچونکہ دین کی اصل اس پر تھی کہ اس مدت میں جو بھی اتفاقات پیش آئے ہیں وہ حقیقی اسلام کے وجود میں آنے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ لہٰذا مجبوراً ہر اس میدان جس میں اسلام کے مصادیق اور نظریات کو معلوم کرنا جس کے اس زمانہ میںکوئی نمونہ پایا جاتا ہو اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں کبھی ایک ہی مسئلہ کے مختلف جواب دیئے گئے ہیںبغیر اس کے حالاتم میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ اب ایسی صورت میں کون سے جواب کو اختیار کیا جائے؟
مثلاً انتخاب خلیفہ کی کیفیت کے باب میں مختلف نمونے موجود تھے۔ ابوبکر نے عمر کو وصیت کی لیکن عمر نے چھ آدمیوں کو وصیت کی اور انتخاب خلیفہ کے کیفیت کی تعیین کیفیت کو ان لوگوں میں سے ہی معین کردیا۔ اس کے باوجود کہ شروع میں خود ابوبکر کی خلافت کو چند لوگوں نے جن کو انگلیوں پر گنا جاسکتا تھا ان کے ذریعہ اس کی بیعت منعقد ہو گئی ۔یہ نمونہ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے نمو نے، خصوصاً فقہی اور کلامی مسائل میں کہ کبھی ایک ہی مسئلہ کے بارے میں مختلف جوابات اور کبھی ایک دوسرے کے متضاد جواب دیئے گئے تھے، بعد میں اہل سنت کے متکلمین و فقہا کو صحیح معیار کو معین کرنے کے لئے متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو تمام کے تمام صدر اسلام کی تاریخ کو قانونی حیثیت دینے کی بناپر تھا۔(۱۰۳)
دوسری فصل کے حوالے
(۱)واقعیت اور حقیقت یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی ذات گرامی خاص طور سے قریش (عرب کا مشہور و معروف خاندان) کے نزدیک بہت زیادہ محترم و مقدس نہ تھی آپ کے ساتھ جو ان کا برتاؤ اور رویہ تھا اس کے مجموعہ سے یہ بات حاصل ہوتی ہے، حتیٰ وہ لوگ عام مسلمانوں کے برابر بھی پیغمبر اکرم کی بہ نسبت عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی شان و منزلت کو تصور سے بھی کم جانتے تھے جس پر اس زمانہ کے تمام مسلمانوں کا اتفاق تھا۔ مندرجہ ذیل داستان اس کا بہترین نمونہ ہے۔
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں: ''جو کچھ میں رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم سے سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اس کے ذریعہ میں اسے محفوظ کرلوں، خاندان قریش نے مجھے اس چیز سے روکا اور کہا:'' ہر وہ چیز جو پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے سنتے ہو اسے کیوں لکھتے ہو؟ حالانکہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو کبھی غصہ میں آکر اور کبھی رضا و رغبت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پھر میں نے اس کے بعد کچھ نہیں لکھا اور اس بات کو پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خدمت میں عرض کردیا۔ حضرت نے انگلی سے اپنے دہن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: لکھو! خدا کی قسم جو بھی چیز اس سے خارج ہوتی ہے وہ حق کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتی ہے۔'' مسند احمد، ج۳، ص۱۶۲ دوسرا نمونہ وہی شخص ہے( ذو الخویصرہ) جس نے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم پر اعتراض کیا کہ عدالت کی رعایت کیوں نہیں کی۔ ملل و نحل، ج۱، ص۱۱۶ یہ دو نمونے اور دوسرے بہت سے نمونے اس حقیقت کی حکایت کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں مسلمانوں کے عقاید کی کیفیت، خاص طورپر خاندان قریش نے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کو اتنا بلند مرتبہ دے دیا کہ خود اس بات کی توقع رکھنے لگے یعنی کہنے لگے کہ یہ لوگ صحابہ ہونے کے اعتبار سے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے زیادہ نزدیک ہیں حق تو یہ تھا کہ ان کو پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی بہ نسبت بھی ایسا ہی عقیدہ رکھنا چاہئے۔ ان کے واسطے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عملی طورپر کون کون سے عقائد موجود تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ خود قریش نے بعد والے زمانوں میں مسلمانوں کی نظر میں بالا ترین قدرو منزلت کو حاصل کرلیا۔ اس لئے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے زعم ناقص میں دوسرے لوگوں کی بہ نسبت پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے بہت زیادہ نزدیک اور ان کے بہت ہی وفادار اصحاب میں سے تھے، اقتضاء الصراط المستقیم کے ص۱۵۰۔ ۱۵۵اور اسی طرح کنز العمال، کی ج۳، ص۲۴۔ ۲۶، پر بھی رجوع کریں۔
(۲)تقریباً تاریخ اسلام کی تمام کتابیں جو زمانۂ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے واقعات و حوادث کو شامل ہیں اور آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد کے واقعات، ابوبکر کے انتخاب کی کیفیت کی داستان اور وہ بحثیں جو اس کے ضمن میں آئی ہیں، کم و بیش بغیر کسی اختلاف اور فرق کے نقل کرتی ہیں اور یہ بات اس کی نشان دہی کرتی ہے کہ یہ داستان صحیح ہے نمونہ کے طورپر الامامة و السیاسة کی ج۱، ص۲۔ ۱۷، پر رجوع کریں۔
(۳)اسلام اس نئے معاشرہ کا بانی تھا جس کے دینی اور دنیاوی مقدسات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اس امر کو کہ یہ دین جاہلیت کی رسم و رواج اور اس کی میراث کی طرف توجہ دیتے ہوئے کس طرح وجود میں آیا اور اس میں تبدیلی پیدا کرکے برقرار رہا احمد امین نے فجر الاسلام، کے ص۹۶۔ ۹۷، میں اس کی بخوبی وضاحت کردی ہے اور اسی طرح العقیدة والشریعة فی الاسلام، کے ص۹۔ ۴۲، پر بھی رجوع کریں۔
Shorter Encyclopaedia of Islam, PP.۳۵۰-۵۱۰
(۴)الاسلام و اصول الحکم ص۱۷۵۔ ۱۷۶، مزید وضاحت کے لئے آپ اسی کتاب کے ص۱۷۱۔ ۱۸۲پررجوع کریں۔
(۵) چھوٹے سے ایک گروہ نے ابوبکر کی خلافت کو پیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی وصیت کی اوسے جاناہے ۔حسن بصری، محب الدین الطبری اور اہل حدیث کی ایک جماعت اس گروہ سے متعلق ہیں۔ معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامیص۱۳۳، ابن حزم ایک مفصل اور طاقت فرسا بحث کے ضمن میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ ابوبکر کی خلافت حضرت کے واضح بیان کے سبب اور آپ سے منصوص تھی، الفصل ج۴، ص۱۰۷۔ ۱۱۱، اس نظریہ پر تنقید و تبصرہ الاسلام و اصول الحکم کے ص۱۷۲۔ ۱۷۳، پر موجود ہے اور اس پر اس سے بھی زیادہ علمی تنقید النظم الاسلامیة کے ص ۸۴۔۸۵، پر رجوع کریں۔
اس مقام پر قابل توجہ یہ ہے کہ ابن جُزّی جو غرناطہ کے آٹھویں صدی کے معروف علما میں سے ہیں، ابوبکراور عمر کی بھی خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی وصیت کے قائل ہیں۔ اس کی کتاب القوانین الفقہیة کے ص۱۷، پر رجوع کریں۔
(۶)ابوبکر کے خلیفہ منتخب ہونے میں انصار کی مخالفت کے بارے میں الامامة والسیاسة کے ص۵۔ ۱۰اور اسی طرح ابوبکر اور عمر کی طرف سے انصار کو دیئے گئے جوابات کو ص۶اور ۷ رجوع کریں۔
(۷)ابوبکر کو خلیفہ کے امیدوار کے طورپر نام پیش کرتے وقت ابوسفیان نے اس طرح کہا: ''اے عبدمناف کے بیٹو! کیاتم اس بات پر راضی ہوجاؤ گے کہ قبیلۂ بنی تمیم کا ایک شخص تم پر حکومت کرے؟ خدا کی قسم مدینہ کو گھوڑوں اور جنگجو افراد سے بھر دوں گا۔'' مواقف کے ص۴۰۱ رجوع کریں۔
(۸)بنی ہاشم کی مخالفت کے بارے میں الامامة و السیاسة''کے ص۴۔ ۱۰اور اسی طرح ص۱۳۔ ۱۶، پر بھی رجوع کریں۔
حضرت علیـ کے اقوال جسے آپ نے بعد میں مقابلہ نہ کرنے کی علت اور سبب کے طور پربیان کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت کے موافق بہت زیادہ اور ابوبکر کے مخالفین کی بھی تعداد بہت زیادہ تھی۔ نمونہ کے طورپر آنحضرت کے خطبہ کو الغارات کے ج۱، ص۳۰۲پراور اسی طرح کشف المحجةمیں سید ابن طاؤس نے ان کے کلام کو نقل کیا ہے اس کی طرف رجوع کریں۔
(۹)بہت سے لوگ جن پر مرتد ہونے کا الزام تھا اور ''اہل ردہ'' سے مشہور تھے حقیقت میں وہ لوگ مرتد نہیں تھے۔ وہ لوگ ابوبکر کے سیاسی مخالف اور حریف تھے نہ یہ کہ انھوں نے اسلام کا انکار کیا ہو۔ اس بارے میں خاص طورپر آپ رجوع کریں الاسلام و اصول الحکم کے ص۱۷۷۔ ۱۸۰پر اور اسی طرح النص و الاجتہاد کے ص۱۳۶۔ ۱۵۰ پر رجوع کریں۔ فجر الاسلام ص۸۰۔ ۸۱، پر رجوع کریں۔ جو لوگ تمام ارتداد کے ملزموں کو مرتد واقعی جانتے ہیں ان کے نظریات اور تحلیل و تجزیہ کی کیفیت کو معلوم کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ وہ لوگ ابوبکر کے سرسخت مدافع ہیں، اس کے لئے رجوع کریں، البدعة: تحدیدہا و موقف الاسلام منہاص۳۲ اور ۳۳، مولف عزت علی عطیہ، اس داستان کے مصادر کو تفصیل سے نقل کرتے ہیں۔
(۱۰)نمونہ کے واسطے، ابوبکر کے منتخب ہونے کے مخالفین و موافقین کی دلیلوں کو الامامة و السیاسة کے ص۴۔ ۱۶، پر ملا حظہ کریں۔
(۱۱)اس بات پر دلیلیں قائم کرنا کہ خلافت اور امامت کی اپنی ایک حیثیت ہے جو صرف علی ابن ابی طالب کے لئے زیب دے سکتی ہے، نہ فقط آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ذریعہ، بلکہ بعد میں دوسرے ائمہ ہُدیٰ (ع) کے ذریعہ ایک دوسرے طریقہ سے بھی بیان کی گئی ہے۔ نمونہ کے واسطے امام حسنـ کا معاویہ کے نام خط کو نظریة الامامة عند الشیعة الامامیة کے ص۳۱۸۔ ۳۱۹ پر آپ رجوع کریں ان شرائط کے بارے میں جو امام کے اندر ہونے چاہئے، اس کے لئے شرح نہج البلاغة ابن ابی الحدیدکی ج۸، ص۲۶۳پر رجوع کریں۔
(۱۲)آنحضرت کے کامل بیان کو الامامة و السیاسة''کی ج۱، ص۱۲، پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر قابل توجہ یہ ہے کہ حضرت کے بیان کے تمام ہوجانے کے بعد بشیر ابن سعد نے جوسعد ابن عباد کے بڑے حریف تھے انھوں نے کہا: ''اگر ابوبکر کی بیعت سے پہلے آپ کا کلام انصار نے سُن لیا ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی آپ کی بیعت کی مخالفت نہ کرتا اور نہ ہی کوئی توقف اور اختلاف کرتا۔''بشیر قبیلۂ اوس کا سردار تھا اور بیعت کے بارے میں اس کی مدد اس بات کا سبب بنی کی کہ عمر اپنی خلافت کے آخری زمانہ تک بنی خزرج سے زیادہ بنی اوس کو حصہ دے ۔اس کے لئے محمد مہدی شمس الدین کی کتاب ثورة الحسین کے ص۱۶، پر رجوع کریں۔
(۱۳)بنی ہاشم نے علیـ کا دامن پکڑ لیا تھا اور زبیر بھی انھیں لوگوں کے ساتھ تھا اور بنی امیہ عثمان کے طرفدار تھے اور بنی زہرہ بھی سعد اور عبدالرحمن کے طرفدار تھے...'' آپ الامامة و السیاسة کے ص۱۰۔ ۱۱، پر رجوع کریں۔
(۱۴)طبری ج۳، ص۱۹۷ پر رجوع کریں ۔
(۱۵)ابن قتیبہ نے حضرت علیـ سے بیعت لینے کی داستان کو اس طرح نقل کیا ہے:'' حضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے پاس دوبارہ سے بیعت لینے کے لئے لوگوں کو بھیجنے کے بعد عمر ایک جماعت کے ہمراہ حضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو ابوبکر کے نزدیک لے گئے، آپ سے کہا گیا: بیعت کرو۔ آپ نے فرمایا: اگر میں بیعت نہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں نے کہا: خدا کی قسم تمہاری گردن مار دیں گے تو آپ نے فرمایا: ایسی صورت میں تم نے خدا کے ایک بندہ اور رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بھائی کو قتل کردیا۔ عمر نے کہا: ہاں بندہ خدا ضرور لیکن پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بھائی کو نہیں۔ ابوبکر کے سرپر طائر بیٹھے ہوئے تھے یعنی وہ خاموش تھے۔ عمر نے چاہا کہ وہ حضرت سے بیعت لے لے تو اس (ابوبکر) نے جواب میں اس طرح کہا: ''جب تک فاطمہ اس کے ساتھ ہیں ، اس کو کسی چیز کے لئے مجبور نہیں کروں گا۔ الامامة و السیاسة کی ج۱، ص۱۳ پر رجوع کریں۔ ابن قتیبہ اس کو تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں:'' علی، کرم اللہ وجہہ نے، رحلت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وقت تک ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔'' نفس حوالۂ سابق، ص۱۴اور اسی طرح ریاحین الشریعةکی ج۲، ص۳۔ ۴۱، پر بھی رجوع فرمائیں۔
(۱۶)سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بلکہ فقط ایک دلیل جو اس زمانہ میں قائم کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ خاندان قریش کے علاوہ دوسرے عربوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے اس کے لئے آپ الامامة و السیاسة کے ص۶۔ ۸ پر رجوع کریں۔
بعد میں عمر نے اپنے آخری حج کے سفر کی واپسی کے وقت مدینہ میں ایک خطبہ میں بیان کیا، ابوبکر کو مسند خلافت پر بٹھانے کی داستان اور ان دنوں کے حوادث اور واقعات کو تفصیل سے بیان کیا۔ مسند احمد ابن حنبلکی ج۱، ص۵۵۔ ۵۶، پر رجوع کریں۔
(۱۷)یمامہ میں بارہ سو(۱۲۰۰) مسلمانوں کو شہید کردیا گیا ان میں سے ۲۳ افراد خاندان قریش سے اور ۷۰ افراد انصار میں سے تھے التنبیہ و الاشراف کے ص۲۴۸ پر رجوع کریں۔
(۱۸)جنگ یمامہ کے بعد عمر کا بھائی زید بھی اس جنگ میں قتل ہوگیا، عمر نے ابوبکر سے اس طرح کہا: ''بہت سے قاریان قرآن جنگ یمامہ میں قتل ہوگئے ڈرتا ہوں کہ دوسری جنگوں میں تمام قاری حضرات قتل کردیئے جائیں اور قرآن کا بہت ساحصہ ضائع ہوجائے۔ اس طرح سوچتا ہوں کہ قرآن کو جمع کرلیا جائے...'' اس کے لئے العواصم من القواصم کے ص۶۷ پر رجوع کریں۔
حاشیہ میں مختلف مآخذاور مختلف نقل موجود ہیں ان کو ملاحظہ کریں۔
(۱۹) ان مرتدوں کے بارے میں جنھوں نے اسلام سے منھ موڑ لیا تھا اور مدینہ کو قطعی دھمکیوں کی چپیٹ میں لاکر کھڑا کردیا تھا۔ بحث کو منقح اور تفصیلی طور پر مطالعہ کرنے کے لئے مویر کی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ اور اسی طرح التنبیہ' الاشرافکے ص۲۴۷ ۔ ۲۵۰پر بھی رجوع کریں۔ MuirTheCalighate PP.۱۱-۴۱۰
(۲۰) جس چیز نیمسلمانوں کو مشغول کر رکھا تھا وہ دائمی جنگیں تھیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ اس زمانہ میں روم اور ایران کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے۔ الملل و النحل کی ج۱، ص۱۸ پر رجوع کریں۔
(۲۱)کنزالعمال ج۵، ص۶۵۸، نیز العواصم من القواصم کے ص۴۵، اسی صفحہ کے حاشیہ میں اس واقعہ کے بہت سے مآخذ اور مختلف نقلوں کی طرف ملاحظہ کریں۔
(۲۲)حقیقت یہ ہے کہ عمر کی جانشینی میںبہت زیادہ کشمکش اور کھینچا تانی تھی۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں:'' جب ابوبکر مریض تھے ، اسی مرض میںوہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے، کچھ صحابہ اس کی عیادت کے لئے آئے۔ عبدالرحمن ابن عوف نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا: اے خلیفۂ پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کیسے امید وار ہوں کہ تم شفا و سلامتی پالو، ابوبکر نے کہا: کیا تم ایسا سوچتے ہو؟ کہا: ہاں ابو بکر نے کہا: خدا کی قسم میری حالت بہت خراب ہے اور شدید درد ہے۔ لیکن جو کچھ تم مہاجرین کی طرف سے دیکھتا ہوں میرے لئے اس سے بھی کہیںزیادہ دردناک ہے۔ تمہارے امور کو جو میرے نزدیک بہترین شخص ہے میں نے اس کے ذمہ کردیا ہے لیکن تم غرور و تکبر اور بغاوت پر اتر آؤگے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہو گے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا نے تمہاری طرف رخ کرلیا ہے...'' الامامة و السیاسة ج۱، ص۱۸؛ شرح ابن ابی الحدید ج۲۰، ص۲۳؛ ملل و نحل ج۱، ص۲۵۔
ابن ابی الحدید طلحہ کی صریح مخالفت کو بھی نقل کرتا ہے: ''جس وقت ابوبکر نے عمر کو انتخاب کیا، طلحہ نے کہا: خدا وند عالم کو کیا جواب دوگے اگر وہ بندوں سے پوچھے کہ کیوں سخت اور سنگدل شخص کو لوگوں کا حاکم بنادیا ہے۔ ابوبکر نے کہا: مجھے اٹھا کے بیٹھا دو! مجھ کو خدا سے ڈراتے ہو۔ اگر وہ مجھ سے پوچھے گا تو جواب میں کہہ دوں گا: تیرے بندوں میں سے بہترین مرد کو لوگوں کا امیر بنایا ہے اس کے بعد اس (طلحہ) کو برا بھلا کہنا شروع کردیا۔'' (نفس حوالئہ سابق کے ص۲۴، پر رجوع کریں)
ان روایات کی بناپر جن کا تذکرہ کنزالعمال نے اس باب میں کیا ہے۔ طلحہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس انتخاب پر معترض تھے۔ ایک روایت کے مطابق جس کو اصحاب پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم میں سے ایک صحابی نقل کرتا ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف اور عثمان، ابوبکر کی مجلس میں وارد ہوئے اور تنہائی میں اس سے کچھ خاص باتیں کر تے ہیں۔ اسی وقت کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اورعمر کے انتخاب پر اس کی خشونت کی بناپر اعتراض کرتے ہیں۔ کنزالعمال ج۵، ص۶۷۵ ایک دوسری روایت نقل کے مطابق جس وقت ابوبکر کی وصیت، عمر کی خلافت کے لئے لکھی گئی اس وقت طلحہ ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ میں ان لوگوں کی طرف سے گفتگو کرنے آیا ہوں جو تیرے انتخاب پر معترض ہیں۔ عمر کو جو ایک بداخلاق، تندخو اور سخت گیر انسان ہے ایسے شخص کو خلافت کے لئے کیوں انتخاب کیا ہے؟ نفس ماخذ سابق ص۶۷۸۔
خود عمر اپنے انتخاب کے بعد منبر پر گئے اور اس طرح کہنا شروع کردیا: ''خدا یا! میں ایک سنگدل انسان ہوں مجھ کو نرم بنادے، میں ایک ضعیف انسان ہوں مجھے قدرت عنایت کر، میں بخیل ہوں مجھے سخاوت عطاکر۔''نفس ماخذ سابق ص،۶۸۵، پر ان کا خطبہ اس کی تائید کرتا ہے کہ واقعاً ایسے اعتراضات کا بازار گرم تھا اور حتیٰ ان پر یہ اعتراض کی فضا عمومی تھی۔
البتہ اس کے علاوہ اور دوسرے اسباب بھی دخیل ہیں ۔ابن ابی الحدید کہتے ہیں:'' ابوبکر نے اپنے مرض الموت میں صحابہ کو خطاب کرکے اس طرح کہا: ''جس وقت میں نے اپنے نزدیک تم میں سے بہترین کو چُنا، تم سب نے اپنی سانس کو سینے کے اندر حبس کرلیا چاہا کہ یہ امر اسی کے پاس رہنے دوں یہ سب اس لئے ہے کہ تم نے دیکھا کہ دنیا نے تمہاری طرف رخ کرلیا ہے۔ خدا کی قسم حریر و دیبا کے پردوں اور ریشمی مسندوں کو اپنے لئے حاصل کرلو گے۔ شرح ابن ابی الحدید ج۲، ص۲۴
(۲۳)عمر ابوبکر کے بالکل برخلاف اپنے آپ کوایک طرح کی قانون سازی کی صلاحیت کے مالک سمجھتے تھے۔ لیکن جیساکہ ان کی رفتار و گفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو مسلمانوں کے حاکم ہونے اور اپنی ذاتی حیثیت کے اعتبار سے جانتے تھے نہ کہ اپنی ذاتی اور دینی مقام و منزلت کے سبب۔ خود ان کے فرزند عبداللہ روایت کرتے ہیں ایک روز' جابیہ' ایک مقام جو بیت المقدس نے نزدیک واقع ہے اس مقام پر مسلمانوں کو خطاب کرکے اس طرح کہا: ''اے لوگو! میں تمہارے درمیان وہی حیثیت رکھتا ہوں جیسی پیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم ہمارے درمیان مقام و منزلت کے حامل تھے۔'' سنن ترمذی ج۴، ص۴۶۵۔
انہوں نے بعد میں اس بات کو ثابت کردیا کہ وہ واقعا اپنے لئے اس شان کی حکومت کے قائل ہیں۔ اس سلسلہ میں اس کے بہت سارے اقدامات جن کے ذریعہ ایسی شان و شوکت اُبھر کر سامنے آئی اس کے لئے آپ رجوع کریں النص و الاجتہاد کے ص۱۴۸۔ ۳۸۳، پر اس کے بعد کے دور کے فقہا اور متکلمین میں اسی حیثیت اور مقام و منزلت کی بنیاد پر جس کے عمر اور دوسرے خلفا اپنے واسطے قائل تھے ، نیز دوسری دلیلوں کے تحت بھی، جنھوں نے حکومتی احکام کی تفسیر و تدوین کی ہے۔ اس بارے میں آپ الاحکام فی تمیز الفتاویٰ عن الاحکام مؤلفٔ ابن ادیس قرافی کے ص۳۹۰۔ ۳۹۶، پر رجوع کریں۔ خصائص التشریع الاسلامی فی السیاسة و الحکمص۳۱۰۔ ۳۱۹؛ الاعتصام مؤلفۂ شاطبی کی، ج۲، ص۱۲۱۔ ۱۲۲ پر رجوع کریں۔
(۲۴)نمونہ کے واسطے جس وقت عمر نے حضرت علیـ سے ابوبکر کی بیعت لینے کے لئے آنحضرت کے اوپر دباؤ ڈالا، حضرت نے فرمایا:'' اس کودوہ لے کہ کچھ حصہ تجھے بھی نصیب ہوجائے گا۔ تو اس کی امارت اور حکومت کو آج مستحکم کرد ے تا کہ کل تیرے ہی پاس پلٹ کر آنے والی ہے۔ الامامة و السیاسة ج۱، ص۱۱۔ عمر نے اپنا جانشین بناتے وقت کہا: اگر ابوعبیدہ جراح زندہ ہوتے تویہ عہدہ ان کو دیتا۔ نفس حوالئہ سابق ص۲۳، یہاں پر دلچسپ چیز یہ ہے کہ تمام دنیا سے اُٹھ جانے والے لوگوں میں صرف ابوعبید جراح پہلے انسان تھے کہ عمر نے ان کو یاد کرکے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ کیوں زندہ نہیں ہیں۔
(۲۵)من اصول الفکر السیاسی الاسلامی کے ص۳۴۷ پر رجوع کریں۔
(۲۶)یہ بات خلیفہ دوم کی ذاتی اور اخلاقی خصوصیات کا ملاحظہ کرتے ہوئے اور اسی طرح پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے زمانہ اور تھوڑا سا قبل و بعد کے زمانہ کے اعراب ا ور ان کی تربیتی اور نفسیاتی خصوصیات پر توجہ کر نے سے یہ بات بخوبی معلوم ہوجاتی ہے بطور نمونہ آپ، کنزالعمال کی ج۵، ص۶۸۷۔ ۶۷۴پر رجوع کریں اسی طرح کتاب عمر ابن خطاب مولف عبدا لکریم الخطیب کے، ص۵۲۔ ۴۲۔ ۳۷۱۔ ۴۴۰اور اسی طرح ان کی وصیت، اپنے بعد والے خلیفہ کے لئے ان کے روحانی اور نفسیاتی افکار اور قلبی جھکاؤ اور روحی اور نفسیاتی حساسیت کی حکایت کرتی ہے۔ آپ اس کے لئے البیان و التبیین کی ج۲، ص۴۷۔ ۴۸ پر رجوع کریں۔
(۲۷)عبداللہ ابن عمر اس زمانہ کے سخت اور خوف ناک حالات کی اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں:'' پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کیں، مدینہ نفاق سے بھر گیا اور اعراب مرتد ہوگئے۔ عجمی بھی وجد میں آکر خیالی پلاؤ پکانے لگے اور طرح طرح کے نقشے بناکر کہنے لگے وہ انسان جس کے سایہ میں اعراب نے قدرت حاصل کی تھی وہ اس دنیا سے اُٹھ چکا ہے ۔اس کے بعد ابوبکر نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور کہا: اعراب نے اونٹ ، بھیڑ اور بکری دینے سے انکار کردیا ہے اور دین سے پلٹ گئے اور عجمی لوگ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے سبب تمہارے اوپر حملہ کرنے کا سودا سر میں پالے ہوئے ہیں۔ پس اپنی رائے کو اس بارے میں بیان کرو میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں البتہ اس موقع پر میری ذمہ داری زیادہ سنگین ہے۔'' کنزالعمال ج۵، ص۶۶۰۔
(۲۸)وہ روایات جو مسلمانوں کے خوف کو ظاہر کرتی ہیں، یہاں تک کہ عمر کی خلافت کے زمانہ میں ایران سے جنگ ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایسا مشہور ہے کہ عمر اس اقدام سے وحشت زدہ تھے اور یہی سبب تھا کہ اس نے چند بار ارادہ کیا تاکہ وہ خود محاذ جنگ پر جائیں ۔یہاں تک کہ حضرت علیـ اپنے ایک مختصر اور پُرمعنی بیان کے ضمن میں ان کے ڈر کو ان کے دل سے نکال دیا اور فی الحال ان کو محاذ جنگ پر جانے سے روکا۔ آپ کے کلام کا ایک حصہ اس طرح سے ہے: ''...اس دین کی کامیابی اور شکست شروع ہی سے کمی اور زیادتی پر نہیں رہی ہے۔ یہ ایک ایسا دین ہے کہ خداوندعالم نے اس کو فاتح بنایا اور اس کے سپاہیوں کو قدرت بخشی اور اس کی مدد فرمائی۔ اور نوبت آہستہ آہستہ یہاں تک آپہنچی... نہج البلاغة خطبہ۱۶۴۔
(۲۹)ایران و روم سے جنگوں میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کی مقدار کو معلوم کرنے کے واسطے اخبار طوال میں رجوع کریں، اسی طرح الکامل فی التاریخکی ج۲، ص۳۸۔ ۶۸، پر رجوع کریں۔
امین اس کتاب سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: ''مسلمانوں نے جنگ جولاء میں بہت زیادہ مال غنیمت اپنے اختیار میں لے لیا جو تمام دوسری جنگوں سے بہت زیادہ تھا اورکثیر تعداد میں عورتیں قیدی ہو کر آئیں نقل کیا جاتا ہے کہ عمر ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے ''خدایا! جنگ جولاء کے اسیر وں کے بچوں کے بارے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔'' فجر الاسلام ص۹۵؛ ملل و نحل ج۱، ص۲۵۔ ۲۶۔ دوسرے مقام پر نافع عمر سے اس طرح روایت کرتے ہیں: ''جس وقت قادسیہ کی فتح کی خبر لائی گئی تو عمر نے کہا :کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں زندہ رہوں اور ان سے تمہاری اولادوں کو دیکھوں۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ؟اس نے کہا: اس صورت میں تمہاری رائے کیا ہے کہ ایک شخص میں حیلہ عربی اور عجمی تیز ہوشی جمع ہوجائے؟ ''کنزالعمالکی ج۵، ص۷۰۲ پر رجوع کریں۔
(۳۰)گولڈزیہر ( Goldziher )نے اس نئے تجربہ کو جو کثیر مال کے جمع کرنے سے حاصل ہوا، جنگوں کی وجہ سے حاصل ہوا تھا پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے روایت نقل کی جاتی ہے کہ مال و دولت کے اکٹھا کرنے کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ (کتاب الجہاد، صحیح بخاری،حدیث۳۶،) بخوبی اس کی توضیح دیتی ہے العقیدة و الشریعة فی الا اسلام ص۳۴۰۔ طٰہ حسین نے خلافت کی عمر کے ختم ہوجانے کا سبب دوسری طرح بیان کرتے ہیں جس طرح شیخین کے زمانہ میں موجود تھاویسے بیان کرتے ہیں الاسلامیات ص۶۶۲۔
(۳۱)من اصول الفکر السیاسی الاسلامی ص۳۵۰۔
(۳۲)سیرۂ ابن ہشام ج۴، ص۳۳۷۔ ۳۳۸۔ اور اسی طرحمسند احمد ابن حنبل ج۱، ص ۵۵۔ ۵۶۔
(۳۳)عمر کی وصیت ، اس کی کیفیت اور شرائط کے لئے الاسلامیة و السیاسیة ج۱، ص۲۳۔ ۲۵ پر رجوع کریں۔ عمر اپنی جانشینی کے معین کرنے کے سلسلہ میں متعدد مشکلات اور موانع سے روبرو تھے، اس مقام پر مناسب ہے کہ اس بارے میں علی الوردی کی نظر کو نقل کریں۔ البتہ اس لحاظ سے کہ وہ شیعہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر عمر نے علیـ کو خلافت کے لئے معین نہیں کیا تو صرف خاندان قریش کی مخالفت سے ڈرتا تھا یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا نظریہ درست ہے یا نہیں اہم اس زمانہ کے خصوصیات اور حالات کی نشاند ہی ہے: ''بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عمر اپنے بعد خلیفہ معین کرسکتا تھا اور لوگ بھی اس کوعمر سے مان لیتے اور اس کے امیدوار کے آگے سرتسلیم خم کردیتے۔ یہ ایک سرسری اور سطحی نظر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس زمانہ میں پس پردہ کیا گذر رہی تھی۔ اگر عمر حضرت علی ـ کو اپنا جانشین انتخاب کرلیتے تو قطعی طورپر قریش یہ افواہیں اڑاتے جو خود آنحضرت کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوتے۔ کیونکہ ان کو آپ سے سخت دشمنی تھی۔'' اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اضافہ کرتا ہے: ''بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمر حیران تھے اور اس بات کی طرف مائل تھے کہ خلافت کو علیـ کے سپرد کردیں لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ قریش ان کے خلاف کھڑے ہوجائیں گے...'' وعاظ السلاطین ص۱۹۹۔ ۲۰۱۔
(۳۴)خلیفہ دوم کی ممتاز اور منحصر بہ فرد موقعیت کے باوجود یہ کہ بعد والے زمانوں میں لگاتار کوشش کی جارہی تھی تاکہ سبھی لوگ ا ن کے طریقۂ کار کا اتباع کریں، لیکن کسی نے بھی ان کے جانشین کی تعیین میں ان کی روش کا اتباع نہیں کیا اور اہل سنت کے متکلمین نے بھی باوجود اس کے کہ بعد میں بننے والے خلیفہ کی تمام انواع و اقسام کا ذکر پہلے سے ہی کردیا ہے جس کو خلیفہ سابق معین کرتا تھا اس کو بیان کردیا ہے لیکن اس روش کا نام بھی نہیںلیا ہے۔ الاحکام السلطانیہ ص۶۔ ۱۱۔
(۳۵)کنزالعمال ج۵، ص۷۴۴۔ ۷۴۵۔
(۳۶)الفکر السیاسی الشیعی ص۲۴۸، ماخوذ از الفلسفة السیاسیة الاسلام مصنفہ ابوالعطائ، ص۳۱۔ ۳۲۔
(۳۷)کتاب الزہد احمد ابن حنبل، ج۲، ص۳۹۔ ۴۳؛ اور تاریخ الخلفاء کے ص۱۴۷۔ ۱۵۳ پر بھیرجوع کریں اور خصوصاً محب الدین خطیب کے العواصم من القواصم کے ص۵۳۔ ۵۵۔ ان احادیث کے بارے میں جو عثمان کے فضائل کے بارے بیان کی گئی ہیںان پر جامع اور منصفانہ تنقید کی ہے۔ اس مطلب کو آپ کتاب الغدیر کی ج۹، ص۲۶۵۔ ۲۶۱، پر ملا حظہ کریں۔
(۳۸)مقدمہ ابن خلدونترجمہ محمد پروین گنابادی، ج۱، ص۳۹۰۔ ۳۹۳۔ اس تفصیل کو جس چیز کو ابن خلدون نے مسعودی سے نقل کرتے ہیں اس کو مروج الذہب نامی کتاب کی ج۲، ص۳۴۱۔ ۳۴۲،پر ملاحظہ فرمائیں۔
(۳۹)ملل و نحل ج۱، ص۲۶، عثمان کے گورنروں کی لاپرواہی اور فسق و فجور کے سلسلہ میں آپ رجوع کریں فجر الاسلام کے ص۷۹۔ ۸۱ پر، شہرستانی کے کلام کا وہ حصہ جو عثمان پر ہونے والی اہم تنقیدوں کو شامل ہے خواہ وہ تنقیدیں عثمان کی حیات میں ہوں یا مرنے کے بعد، اپنے اعتراضات کو ثابت کیا ہے؛ ابن عربی کے جوابات مع تفسیر و توجیہ جس کو انہوں نے العوصم من القواصمنامی کتاب کے ص۱۲۲۔ ۶۳پر بیان کیا ہے آپ اس سے مقایسہ کریں۔ خاص طور سے اسی مقام پر محب الدین خطیب کے شدید اللحن حاشیوں کو ملاحظہ کریں۔
(۴۰)ان میں سے ایک نمونہ ولید ابن عتبہ کا ہے جو حاکم کوفہ تھا وہ اپنے ندیموں اور گانے والیوں کے ساتھ رات سے صبح تک شراب پی پی کر اپنی محفل جمائے رہتا تھا ۔ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مستی کی حالت میں صبح کی نماز چہار رکعت پڑھادی سجدہ کے عالم میں شراب کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے اعتراضات کے جواب میں کہا: تم لوگ اگر چاہو تو اور زیادہ پڑھادوں۔ کوفیوں کا عثمان پر اعتراض کرنے کی داستان اور اس پر اس کے ردعمل اور حضرت علی ـ کا اس (ولید) پر حد جاری کرنا ان باتوں کو مروج الذہبنامی کتاب کی ج۲، ص۳۴۴۔ ۳۴۵، پر تلاش کیجئے۔ ابن تیمیہ کے کلام سے مقایسہ کیجئے جہاں عثمان پر اعتراض کرنے والوں کی متعصبانہ اور تکلیف دہ انداز میں اعتراض کی رد کی ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے فاسق اور لاابالی نزدیک لوگ کو امارت بخشی تھی اس کو بیان کرتا ہے۔ منہاج السنة النبویة کی ج۳، ص۱۷۳۔ ۱۷۶، پر ملاحظہ کیجئے۔
(۴۱)عثمان پر مسلمانوں کے اعتراضات، ان کو محاصر ہ کرنے، اس کے بعد ان کے قتل کئے جانے، ان پر نماز میت پڑھنے اور دفن کرنے کی کیفیت کو تفصیل کے ساتھ تاریخ الخلفاء کے ص۱۵۷۔ ۱۶۴ پر ملاحظہ کریں؛ الامامة و السیاسةکی ج۱، ص۳۲۔ ۴۵ پراور ایسے ہی مروج الذہب کی ج۲، ص۳۴۵۔ ۳۵۷، پر تلاش کرسکتے ہیں۔اس مقام پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے عائشہ کا عثمان پر اعتراض اس قدر شدیداور کفن پھاڑ تھا کہ آج کل کوئی اس بات کی جرأت بھی نہیں کرسکتا کہ اس کو کوئی اس طرح کہے جس طرح عائشہ نے عثمان کے بارے میں کہا ہے اور ان کو اتنی ساری نسبتوں سے منسوب کیا ہے۔ شرح ابن ابی الحدید کی ج۲، ص۱۱ پر رجوع کریں۔
(۴۲)عثمان کی فضیلت کے بارے میں معاویہ نے وسیع پیمانے پر جعل حدیث کے اقدامت کئے ہیں اس کے بارے میں آپ، شرح ابن ابی الحدید کی ج۱۱، ص۱۵۔ ۱۶پر رجوع کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی جس کے ذریعہ اموی خاندان کے لوگ اس سے متمسک ہو کر اس بات کی کوشش کررہے تھے کہ اپنی حقانیت اور مشروعیت کو ثابت کرلیں یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ عثمان کے شرعی و قانونی وارث بن بیٹھے۔ اس بارے میں اموی دربارکے مداحوں اور شعرا نے دادسخن دی ہے۔ لیکن یہ سکہ کا ایک رخ تھا۔ اس کا دوسرا رخ عثمان کی تقدیس اور اس کی حقانیت اور مظلومیت کی تبلیغ تھی۔ جس قدر اس (عثمان) کی شان و منزلت اور حیثیت بڑھتی جا رہی تھی اس کے جانشینوں اور وارثوں کا بھی مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیساکہ اس کے برعکس بھی صحیح تھا۔ یعنی اگر عثمان کی منزلت میں شک و تردید کی جاتی تو یہ تردید بنی امیہ کی حیثیت پر بھی اثرانداز ہوتی۔ یہ اہم ترین سبب تھا کہ ایک ایسے انسان کے چہرہ کو تقدس بخشا جارہاتھا جو اپنے زمانۂ خلافت میں لوگوں کی نظر میں تمام کمالات و فضائل اور شخصیت و محبوبیت سے عاری تھے۔ مزید توضیح کے لئے آپ الامویون والخلافة کے ص۱۲۔ ۱۷،پر رجوع کریں۔
ایسی بحثیں جو بعد میں عثمان کی شان اور ان کا خلفائے راشدین سے مقایسہ چاہے متکلمین کے درمیان اور چاہے اہل حدیث کے درمیان ہوں زور پکڑگئیں: اس کے بارے میں آپ شرح ابن ابی الحدیدکی ج۱، ص۶۔ ۱۰،پر رجوع کریں؛ نیز المواقف کے ص۴۰۷۔ ۴۱۳، پر بھی رجوع کریں؛ مذہبی روشن فکروں کی تنقید کے بارے میں اور اسی طرح وہ لوگ جو انقلابی رجحان رکھتے ہیں ان کی تنقیدوں کے بارے میں ''اندیشۂ سیاسی در اسلام معاصر کے ص۱۵۰، پر رجوع کریں۔
(۴۳)محب الدین خطیب کے حاشیوں پر جس کو انھوں نے کتاب العواصم من القواصم کے ص۶۳۔ ۶۵، پر درج کیا ہے اس کی طرف رجوع کریں۔
(۴۴)تاریخ الخلفاء ص۱۶۵۔
(۴۵)الاسلام و اصول الحکم ص۱۸۱۔
(۴۶)یہ معروف جملہ ہے جس کو مختلف مناسب مواقع پر عمر سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے لئے آپ تحریر الاعتقاد کے ص۲۴۵، پر رجوع کریں؛ اور شرح ابن ابی الحدید کی ج۲، ص۲۶پر رجوع کریں۔
(۴۷)''... جن لوگوں نے علیـ کی بیعت کی تو ان کی بیعت کرنے کا اصلی سبب یہ تھا کہ آپ کو مسلمانوں کے درمیان مقام خلافت کے لئے سب سے بہتر پاتے تھے جیساکہ گذشتہ زمانہ کے مسلمان ابوبکر کو مقام خلافت کے لئے سب سے بہتر سمجھتے تھے، اسی لئے اس کا انتخاب بھی کرلیا اور یکے بعد دیگرے عمر اور عثمان کو منتخب کرتے رہے (۲۲۰) اسلام بلا مذاہب ص۱۱۰۔
(۴۸)ان توقعات کے نمونوں میں سے ایک نمونہ ابوموسیٰ اشعری کی تجویز ہے جس کو آپ مروج الذہبکی ج۲، ص۴۰۹، پر ملاحظہ کریں۔
(۴۹)طلحہ و زبیر کا جنگ جمل سے پہلے امام جماعت اور لشکر کی قیادت کے سلسلہ میں اختلاف اس کے لئے آپ ''نقش عائشہ در تاریخ اسلام'' کی ج۲، ص۴۸۔ ۶۵پر رجوع کریں۔
(۵۰)طلحہ کا جنگ جمل کے دوران مروان کے ہاتھوں قتل کئے جانے اور اس کے مدارک میں تنقیدی چھان بین کے بارے میں آپ اسی کتاب کے ص۱۷۳۔ ۷۵ ۱پر رجوع کریں، نیز العواصم من القواصم فی الذب عن سنةابی القاسم کے ص۲۴۰۔ ۲۴۱،پر اور خاص طورپر اسی طرح آپ محب الدین خطیب کے شدید تکلیف دہ جواب کے لئے ان کے حاشیوں میں رجوع کریں۔
(۵۱)اس کے باوجود کہ سعد ابن ابی وقاص کے ایسا انسان علیـ کے ساتھ نہ تھا لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ سے مقابلہ کرے، وہ اس جملہ کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے کہ'' میں جنگ نہیں کروں گا کہ مجھے تلوار دو اور وہ میرے بارے میں یہ سوچیں اور دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ راہ راست اور دوسرا خطا پر ہے۔'' حضرت علیـ کی مددسے انکار کردیا الفتنة الکبریکےٰ ص۵پر، لیکن اس کے باوجود امامـ کی تعریف میں یہ کہا: ''پس پیغمبر خداصلىاللهعليهوآلهوسلم سے جو باتیں علی ـ کے بارے میں میں نے سنی ہیں اگر میرے سر پر آرہ رکھ کر ان کو برا بھلا کہنے کے لئے کہیں کہ ان کو برا بھلا کہوں تب بھی میں ان کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔'' کنز العمال اس روایت کو مختلف نقلوں اور سندوں کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ ج۱۳، ص۱۶۲۔ ۱۶۳۔
(۵۲) الخلافة و الامامة عبد الکریم الخطیب' ص۱۲۱۔
(۵۳) مقدمہ ابن خلدون' ج۱، ص۲۹۸۔
(۵۴)شرح ابن ابی الحدید' ج۲۰، ص۸۔
(۵۵) اس خود پسندانہ تفسیر اور اس من چاہی اور ناجائز توقعات کے بہترین نمونہ کو علیـ سے طلحہ و زبیر کے مجادلات میں دیکھا جاسکتا ہے اس کے لئے آپ''نقش عائشہ در تاریخ اسلام'' کے ص۳۵۔ ۴۱، پر رجوع کریں۔
(۵۶)بیشک حضرت علیـ اپنی خلافت کے وقت جن مخالفتوں سے روبرو ہوئے اس کے چند اصلی اسباب تھے ان میں سے ایک سبب خاندان قریش کا آپ سے قدیمی کینہ تھا۔ امام نے بارہا مختلف مواقع پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور قریش والوں کی شکایت کی۔ ایک بار آپ نے فرمایا: ''تمام وہ کینہ جو قریش نبی اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے لئے اپنے دل میں رکھتے تھے مجھ پر ظاہر کردیا اور بعد میں میری اولاد سے بھی اس کینہ کا اظہار کریں گے۔ مجھ کو قریش سے کیا سروکار! خدا اور اس کے رسول کا حکم تھا جس کے باعث میں ان (قریش) سے لڑا۔ کیا خدا و رسول کی اطاعت کرنے والے کی جزا یہی ہے، اگر یہ لوگ مسلمان ہیں۔'' الشیعة و الحاکمون ص۱۷۔
قابل توجہ بات تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس نکتہ کی تہہ تک پہونچ گئے تھے۔ ایک دن عمر نے عباس سے اس طرح کہا:'' اگر ابوبکر کی رائے اپنے مرنے کے بعد کے خلیفہ کے بارے میں نہ ہوتی تو بیشک و شبہہ یہ قدرت تمہارے پاس پہونچ جاتی اوراگر ایسا ہوجاتا تو اپنی قوم سے تمہیں چین کا سانس لینا نصیب نہ ہوتا۔ وہ تم کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ذبح ہونے والی گائے قصاب کو دیکھتی ہے۔'' ایک دوسرے مقام پر ایک جلیل القدر صحابی ابن التیہان نے حضرت علیـ سے کہا: ''قریش کا حسد آپ کی بہ نسبت دو طرح کا ہے۔ ان میں کے اچھے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی طرح ہوجائیں اور آپ ہی کی طرح معنوی اور روحانی حیثیت بڑھانے میں آپ سے رقابت کریں لیکن ان میں کے جو برے لوگ ہیں وہ آپ سے اس قدر حسد کرتے ہیں جو دل کو سخت بنادیتا ہے اور عمل کو نابود کرنے والا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کن نعمتوں سے مالا مال ہیں جو آپ کی خوشنودی اور ان کی محرومی کا باعث ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے برابر ہوجائیں اور آپ سے آگے نکل جائیںکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کرپاتے ہیں اور ان کی کوشش بے نتیجہ ہوجاتی ہے چونکہ وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں لہٰذا وہ آپ سے مقابلہ کے لئے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ تمام قریش سے زیادہ ان کے نزدیک قدردانی کے مستحق ہیں۔ کیونکہ آپ نے پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی مدد کی اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد ان کے حق کو ادا فرمایا۔ خدا کی قسم ان کی سرکشی میں صرف انھیں کا نقصان ہے۔ انھوں نے اس کے ذریعہ خدا کے عہد کو توڑ دیا اور اس (خدا وند عالم) کا ہاتھ تمام ہاتھوں سے برتر ہے۔ لیکن ہم انصار کے ہاتھ اور زبانیں آپ کے ساتھ ہیں...'' الفکر السیاسی الشیعی کے ص۲۰۴۔ ۲۰۶،پر رجوع کریں ؛خاص طورپر آپ زیاد ابن الغم شعبانی کے نظریات میں رجوع کریں (متوفی۱۵۶) اور اسی طرح شعبی نے بھی اسی باب میں محب الدین خطیب العواصم من القواصم نامی کتاب کے حاشیہ کے ص۱۶۸۔ ۱۶۹، سے نقل کیا ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ قریش کی مخالفت صرف حضرت علیـ تک محدود نہ تھی یہ خود پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کو بھی شامل تھی کہ اس کے نمونے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی عمر کے آخری حصہ میں باربار دیکھے جاسکتے ہیں۔ شیخ مفید، امام صادقـ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اس میں کا کچھ حصہ اس طرح ہے: ''پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کو خبر ملی کہ قریش کے بعض لوگوں نے اس طرح کہا ہے: کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے کس طرح قدرت کو اپنے اہل بیت کے لئے مستحکم اور استوار بنادیا ہے ان کی وفات کے بعد اس قدرت کو ہم ان (اہل بیت) سے دوبارہ لے لیں گے اور اسے دوسری جگہ پرمقرر کردیں گے...'' امالی، ص۱۲۳۔ قریش کے طعنہ دینے کے باب میں اور ان میں سے سرفہرست ابوسفیان تھاجو بنی ہاشم کو حتیٰ زمان پیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم میں بھی طعنہ دیا کرتا تھا اس کے لئے عبداللہ بن عمر کی روایت کو اقتضاء الصراط المستقیم، نامی کتاب مصنفہ ابن تیمیہ کے ص۱۵۵ سے ماخوذ ہے اس پر ملاحظہ فرمائیں اور ایسے ہی ابوسفیان کے کلام کی طرف بھی جو پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے چچا حضرت حمزہ کی قبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قاموس الرجال، نامی کتاب کی ج۱۰، ص۸۹، پر رجوع فرمائیں۔
(۵۷)اس زمانہ کے رائج دین کی تبعیت میں ڈاکٹر طہ حسین صاحب کے اقتصادی بدلائو کے بارے میں تحلیل و تجزیہ کو الفتنة الکبریٰ، نامی کتاب میں رجوع کریں۔
(۵۸)نمونہ کے واسطے ابوحمزہ کے خطبہ البیان والتبیین، کی ج۲، ص۱۰۰۔ ۱۰۳، پر رجوع کریںاور یہ کہ پہلے والے دو خلیفہ اور حضرت علی تعارف کس طرح سے کرایا گیا۔
(۵۹)نظریة الامامة لدی الشیعة الاثنا عشر، نامی کتاب کے، ص۲۸۰ پر، ان تنقیدوں کے خلاصہ کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔
(۶۰)معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں اور اس کی اتباع میں پہلے زمانہ کی دینی، سیاسی اور فکری تبدیلیاں اس قدر گہری اور تیز تھیں کہ معاویہ کے جیسے بلا کے سیاسی انسان کو بھی عاجز وناتواں بنادیا۔ اس نے اپنے مرض الموت کے خطبہ میں اپنی ناتوانی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا: ''اے لوگو! ہم بہت ہی سخت اور گیرودار اور فتنہ سے بھرے ہوئے زمانے میں واقع ہوئے ہیں۔ ایسا زمانہ جس میں ایک صالح انسان گنہگار شمار کیا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں اور اضافہ کردیتا ہے...'' عیون الاخبار، ج۲، ص۲۵۹۔
(۶۱)حقیقت تو یہ ہے کہ عائشہ بہت زیادہ مصمم نہیں تھیں اور حتیٰ کہ حضرت علیـ سے جنگ کرنے کے لئے مائل نہیں تھیں چند بار ارادہ کیا میدان جنگ میں نہ جائیں زیادہ تر عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجہ تھے، حضرت عائشہ کو ان کے قطعی ارادہ سے روک دیا۔ اس کے لئے آپ نقش عائشہ در تاریخ اسلام، نامی کتاب کی ج۲، ص۵۱۔ ۵۲ کی طرف رجوع کریں۔
(۶۲)عائشہ جنگ جمل کے بعد اپنے کئے پر سخت پشیمان ہوئیں اور انھوں نے اسے مختلف طرح سے اظہار اور بیان کیا۔ ان میں سے ایک معاویہ کے ذریعہ حجر بن عدی کی شہادت کے بعداس طرح کہا: ''میں یہ چاہتی ہوں حجر کے خون کے بدلہ لینے کے لئے قیام کروں (اس کا بدلہ لوں) لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں جنگ جمل کی تکرار نہ ہوجائے: الفکر السیا سی الشیعی، ص۲۹۱۔
(۶۳)زبیر کا محاذ جنگ چھوڑ کر چلے جانے کا بڑی ہی باریکی سے جائزہ لینے کے لئے عائشہ در تاریخ اسلام، نامی کتاب کی ج۲، ص۱۶۰۔ ۱۷۰ پر ملاحظہ کیجئے۔
(۶۴)بطور نمونہ الامامة والسیاسة، نامی کتاب کے ص۱۷۷، ۱۸۹،۱۹۱ پر رجوع کریں۔
(۶۵)حقیقت یہ ہے کہ انصار کی حضرت علی بن ابی طالب کی حمایت اور معاویہ اور امویوں کی مخالفت کے بہت سے دلائل اور وجوہات موجود ہیں۔ سب سے زیادہ مخالفت یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنی موافقت کے لئے کھینچ لیا اور یہ سبب مستقل برقرار رہا۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے مختلف مواقع پر ان لوگوں کو اس بات کا طعنہ دیا اور یزید اور تمام امویوں نے بھی ایسا ہی کیا یہاں تک کہ ان کے قتل عام کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمود صبحی، مسعودی کے قول سے اس طرح حکایت کرتا ہے: ''جس وقت امام حسنـ نے معاویہ سے صلح، قیس بن سعد نے معاویہ سے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور اپنے افراد کو اختیار دیا کہ یا تو امام حسنـ کی طرح صلح پر قائم رہیں یا پھر بغیر امام کی اجازت کے جنگ کو جاری رکھیں۔'' اس کے بعد وہ خود اضافہ کرتا ہے: ہاں اس نے اچھے طریقے سے امویوں کو انصار پر امویوں کی حکومت کے مفہوم کو جان لیا تھا۔ نظریة الامامة لدیٰ الشیعة الاثنا عشریة، ص۴۴۔ایک دوسری جگہ قیس بن سعد ایک خط (نامہ) کے ضمن میں جو نعمان بن بشیر کو لکھا تھا کہ وہ خود انصار میں سے تھے لیکن خاندان اور قبیلہ کے درمیان اختلاف کی بنا پر انصار سے جدا ہوکر معاویہ سے مل گیا تھا، اس طرح لکھا: ''اگر تمام عرب معاویہ کی حمایت میں جمع ہوجائیں، تب بھی انصار اس سے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہونگے انصار اور امویوں کی گہری جڑیں رکھنے والی مخالفت کے بارے میں آپ، الامامة و السیاسة،کی ج۱، ص۱۷۷۔ ۲۲۰۔ پر رجوع کریں اور اسی طرح معاویہ اور انصار کے درمیان رقابت کے بارے میں بھی البیان و التبیین، کی جلد۱، ص۱۲۹ پر رجوع کریں۔
(۶۶)اس داستان کو عموماً کتب تاریخ واحادیث نقل کرتی ہیں۔ اس کے لئے آپ ، حاشیہ ملل ونحل، ج۱، ص۱۱۶ پر رجوع کریں۔ یہاں پر مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کو ابن تیمیہ جیسا شخص بھی السیاسة الشرعیہ، کے ص۴۶ پر نقل کرتا ہے: اس باب میں وہ احادیث جو خوارج کے بارے میں وارد ہوئیں ہیں ان کے بارے میں کنزالعمال، کی،ج ۱۱، ص۲۸۶۔ ۳۲۳ پر رجوع کریں۔
(۶۷)خوارج کے وجود میں آنے اور ان کی پیدائش اور بقا کی کیفیت کے بارے میں بہترین کتاب مصنفہ نایف الخوارج فی العصر الاموی کی معروف نیز قدیمی ترین کتاب الخوارج والشیعة، مولفہ ولہازن، ترجمہ عبدالرحمن بدوی میں کسی طرف بھی رجوع کریں۔
ان کے بارے میں بہترین اور جامع ترین تعریف توصیف کو خود امامـ نے بیان کیا ہے۔ نہروان کی جنگ کے تمام ہونے کے بعد امام سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ اور کیا یہ لوگ کافر تھے؟ آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے کفر سے فرار کیا۔ ان لوگوں نے پھر پوچھا کیا یہ لوگ منافق تھے؟ آپ نے فرمایا: منافق لوگ خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ خدا کی یاد کثرت سے کرتے ہیں۔ پھر آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر وہ کون لوگ تھے؟ تو آپ نے فرمایا: ایک ایسا گروہ تھا جو فتنہ میں مبتلا ہو گیا۔ لہٰذا وہ لوگ اندھے اور گونگے ہوگئے۔ المصنف شمارہ۱۸۶۵۶ ونیز قرائة جدیدة فی مواقف الخوارج وفکر وادبہم کے ص۷۵۔ ۸۲ پر بھی رجوع کریں۔
(۶۸)بطور نمونہ ابوحمزہ کے اس خطبہ کو جس مقام پر وہ معاویہ، یزیداور بنی مروان کا تعارف کراتا ہے اس کے لئے آپ البیان التبیین، کی ج۲، ص۱۰۰۔ ۱۰۳، پر رجوع کریں۔
بعد میں خوارج کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور ان کے درمیانہ اقدام کو آپ ملاحظہ کریں اباضیہ کے فقہ و کلام میں خاص طور پر ازالة الاعتراض عن مخفی آل اباض، و الاصول التاریخیة للفرقة الاباضیة، نامی کتابوں میں رجوع کریں۔
(۶۹)حقیقت یہ ہے کہ متعدد مواقع پر بنی امیہ کی سیاست ایک ایسی سیاست تھی جو قہر وغلبہ، دبائو، دھمکی آمیز انداز، خوف کا ماحول بنانے اور بلا وجہ ایک شخص کو دوسرے پر ترجیح دینے اور جبری دین کا لبادہ پہنے ہوئے تھی، نمونہ کے طور الامامة و السیاسة، کی ج۱، ص۱۹۱۔ ۱۸۳ یزید کے لئے بیعت لینے کے موقع پر معاویہ کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ اور زیاد بن سمیہ کا اہل بصرہ سے وحشت ناک خطاب جس کو البیان والتبیین، کی ج۲، ص۵۸۔ ۶۰ پر، اپنے باپ مروان کے مرنے کے بعد عبدالملک کا خطبہ جس کو انساب الاشراف، نامی کتاب کی ج۱، ص۱۶۴ پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ مصعب بن زبیر کے قتل کرنے کے بعد خود اسی کا خطبہ جس کو الامویون والخلافة، کے ص۱۲۰ پر بھی رجوع کریں۔ اور اسی طرح سے طبری، ج۷، ص۲۱۹ میں بھی ملاحظہ کریں۔ یزید بن عبدالملک کا اپنے دو بیٹوں کی ولایت عہدی کے بارے میں ان کے نام خط اور اسی طرح حجاج کے متعدد خطبے جس کو جاحظ نے البیان والتبیین، نامی کتاب کی جلد دوم میں بیان کیا ہے۔ خاص طورپر عراق کے لوگوں سے اس کا خطاب اسی کتاب کے ص۱۱۴ و ۱۱۵ پر رجوع کریں، خاص طورپر آپ، الامویون والخلافة، نامی کتاب کی طرف مصنفہ، حسین عطوان کی طرف رجوع کر یں۔ سب سے بہتر اور سبق آموز مطلب کے لئے آپ، عبداللہ بن مروان کی داستان کی طرف رجوع کریں جو بنی امیہ کے آخری خلیفہ کا بیٹا تھا، اپنے خاندان کی حکومت کے ختم ہوجانے کو نئے بادشاہ کے عنوان سے اپنی زبانی منصور سے نقل کرتا ہے بادشاہ نے امویوں کی داستان کو سن کر عبداللہ سے یہ کہا: ''یہی وجہ ہے کہ خدا وند عالم نے تمہارے گناہوں کے سبب تم سے عزت اور بزرگی کو چھین لیا اور لباس ذلت پہنا دیا ہے اور انتقام خدا ابھی تمہارے اوپر ختم نہیں ہوا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسی وقت میرے ہی ملک میں خدا کا عذاب تم پر نازل ہوجائے اور تمہاری وجہ سے وہ عذاب مجھ پر بھی آجائے...'' مقدمة ابن خلدون، ج۱، ص۳۹۷ اور ۳۹۸۔
(۷۰) W. M. Watt, the Majesty That was Islam,p.۱۸
شامیوں اور عراقیوں کے فرق کے باب میں جعفری بھی واٹ کے نظریات کی تاکید کرتا ہے۔
(۷۱)لوگوں (عوام الناس) نے میری بیعت کی۔ وہی افراد جنھوں نے ابوبکر وعمر وعثمان کی بیعت توجہ کی ضرورت ہے کی اسی چیز پر ان لوگوں کی بیعت کی تھی... الیٰ آخرہ'' شرح نہج البلاغہ، ج۳، ص۸۔
(۷۲)علامہ امینی مختلف روایتوں کو ان انگشت شمار اصحاب کے بارے میں نقل کرتے ہیں جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ جنگ صفین میں تھے۔ ایک روایت کی بناپر حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے، وہ ۲۵۰افراد جنہوں نے بیعت رضوان میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جنگ صفین میں حضرت علیـ کے ہم رکاب تھے اور ایک دوسری روایت کی بنا پر ۸۰۰آدمی تھے، ان میں سے ۳۶۰آدمی شہید ہوگئے۔ جیسا کہ جنگ بدر میں حضرت کے ہمراہ شرکت کرنے والے صحابہ ۷۰ و۸۰ یہاں تک کہ ۱۰۰افراد کو بھی نقل کیا گیا ہے۔ خود حضرت علیـ نے ۱۴۵صحابہ کے نام ذکر کئے ہیں عموماً یہی امام کے باوفا ساتھیوں میں سے تھے جو حضرت کے لئے اسی شان اور حیثیت کے قائل تھے جو پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے حضرت کے بارے میں فضیلت بیان کی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس جنگ میں شہید ہوگئے اور امام اپنے آخری ایام میں بارہا ان سے بچھڑنے کو یاد کرکے گریہ فرماتے تھے اور یہ آرزو فرماتے کہ جتنی جلدی ہوسکے ان سے ملحق ہوجائیں۔ الغدیر، ج۹، ص۳۶۲۔ ۳۶۸ ۔
تسمیة من شہد مع علی حروبہ ان لوگوں کے اسامی جو امیر المومنینـ کے ہمرکاب جنگ میں شہید ہوگئے تراثنا، مجلہ کے تسمیات نامی مقالہ کے شمارہ، ۱۵، کے ص۳۱ پر ملاحظہ ہو۔
(۷۳)اس طرح کے بیانات پہلے دو خلفا نے بہت زیادہ دئیے ہیں اور تاریخی اور مختلف روائی مآخذ میں کثرت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ اس کے لئے تجرید الاعتقاد، نامی کتاب مؤلفہ محمد جواد جلالی کے حاشیہ کے ص۲۴۱۔ ۲۵۴ پر رجوع کریں۔
(۷۴)معاویہ کے اقدامات ایسے موثر اور دیرپا تھے کہ بہت سے اہل سنت کے نزدیک اس نے اموی خاندان کو ایک بہت بلند مرتبہ عطا کردیا۔ ''کیونکہ امویوں کا مسئلہ اور ان کا دفاع ہمیشہ سنیوں کی سیاسی فکر کے عنوان سے باقی رہا۔'' ضحی الاسلام کی ج۳، ص۳۲۹ پر رجوع کریں۔
(۷۵)اضواء علی السنة المحمدیة، کے ص۲۱۶ کا ملاحظہ کریں۔ اور یہ کہ ابوہریرہ نے معاویہ کی خوشامد کے واسطے امام علیـ کے خلاف کس طرح بہت سی روایات جعل کیں اور معاویہ کا قدرت پر پہنچنے کے بعد کوفہ میں لوگوں کے سامنے ان کو پڑھا اور اس نے اس کے بابت ایک بہت بڑا انعام حاصل کیا۔
(۷۶)بہت سی ان باتوں (نکات) کو حاصل کرنے کے لئے جو روایت میں موجود ہیں اور شیعوں کے ایک صدی کے حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے لئے شرح نہج البلاغہ کی ج۱۱، ص۴۳ پر رجوع کریں۔
(۷۷)حوالہ سابق (شرح نہج البلاغہ) ج۱۱، ص۴۴۔۴۶۔
(۷۸)حوالہ سابق (شرح نہج البلاغہ) ج۱۱، ص۴۶۔
(۷۹)بطور نمونہ اموی شعر کے اشعار کو ملاحظہ کیجئے الامویون والخلافة، کے ص۱۵۔ ۲۱ پر اور عباسی شعرا کے رد کے ساتھ، مروج الذہب، کی ج۳، ص۴۳پر موازنہ کریں۔
(۸۰) Goltziher, Muslim Studies Vol.۲nd P.۱۱۵
(۸۱)اموی لوگ کہتے تھے خلافت ہمارے جملہ حقوق میں سے ایک حق ہے اور انہوں نے اس کو عثمان سے ورثہ میں حاصل کیا ہے۔ عثمان نے شوریٰ کے ذریعہ اس کو حاصل کرلیا لیکن مظلوم قتل ہوگیئے اور ان کا حق پائمال ہوگیا۔ خلافت ان کے خاندان سے باہر چلی گئی اور دوسروں کی طرف منتقل ہوگئی۔ یہ ان کا فریضہ ہے کہ اس کو واپس پلٹانے کے لئے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔ امویوں کی طرفداری میں رطب اللسان شعرا اس بات کو مختلف مواقع پر کہا کرتے تھے: الامویون والخلافة، ص۱۳اور تبلیغ کرتے تھے کہ امویوں نے خلافت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم سے وراثت میں حاصل کی ہے۔ حوالہ سابق ص۱۷۔
یہ تبلیغات اس حد تک موثر ہوگئیں کہ امویوں کی حکومت کے زوال تک ایسا اعتقاد، کم سے کم ان کی اپنی سرحد میں یعنی شام میں کامل شائع تھا۔ مسعودی اس موقع پر روایت کرتے ہیں: ''اس کے بعد کہ مروان، آخری اموی خلیفہ، قتل ہوگیا عبداللہ بن علی شام آئے اور وہاں کے ثروت مند لوگوں کے ایک گروہ کا انتخاب کرکے سفاح کے پاس بھیجا۔ انھوں نے سفاح کے نزدیک قسم کھائی کہ وہ لوگ امویوں کے علاوہ کسی کو پیغمبراکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اہل بیت نہیں جانتے تھے تاکہ آنحضرت سے میراث حاصل کریں۔ اس مجلس میں ابراہیم بن مہاجر نے ایک شعر پڑھا جس کی بعد میں عباسیوں کے چاہنے والے شعراء نے متابعت کی اور امویوں کے طعنہ دینے کے ضمن میں، بنی عباس کو پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ورثہ داروں کے نام سے یاد کیا۔'' اس کے لئے آپمروج الذہب، کی ج۳، ص۴۳ پر رجوع کریں۔
(۸۲)اس داستان کی تفصیل کوکتاب مروج الذہب کی ج۲، ص۴۰۶۔ ۴۰۹ پر ملاحظہ کیجئے۔
قابل توجہ بات یہ ہے کہ استاد سبحانی اس داستان کا اصلی سبب خلفا کی حقانیت کا عقیدہ جانتے ہیں۔ ''جبکہ یہ عقیدہ تینوں خلفا کے زمانے میں دکھائی نہیں دیتا ہے مہاجرین وانصار کسی فرد کے ذہن میں خطور نہیں کرتا تھا کہ اس کی یا اس کی خلافت کا عقیدہ رکھنا واجب ہے اور جو ان کی خلافت کا معتقد نہیں ہے وہ مومنین کی جماعت سے خارج اور بدعت گزاروں کی جماعت میں داخل ہوگیا ہے۔ اس قاعدہ کو سیاست نے وجود دیا تاکہ علیـ کو طعنہ دیں اور خون عثمان کے انتقام کے سلسلہ میں معاویہ کے خروج کو مشروعیت بخشے۔ شاید عمرو ابن عاص پہلا شخص تھا جس نے اس طرزتفکر کا بیج بویا۔'' اس کے بعد داستان کو مفصل طور پر نقل کرکے اس قسم کا نتیجہ نکالتا ہے: ''یہ داستان اور اسی کی طرح دوسری داستانیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ خلفا کی خلافت کا اعتقاد دشمنی اور رقابت کی مسموم فضا میں پیدا ہوا یہاں تک کہ وہ مکار اور ہوشیار مرد شیخین کی خلافت کے اعتقاد کو وسیلہ بنا کر عثمان کی حقانیت کا اقرار لینا قرار دے...'' الملل والنحل،کی۱، ص۲۶۵۔ ۲۶۶ پر رجوع کریں۔
(۸۳)اس طرح کے واقعہ کے نمونہ کو رجال حول الرسول نامی کتاب میں ملاحظہ کریں۔ اس واقعہ نے حتی ایک آزاد خیال اور خالد محمد خالد کے جیسا تجدد پسند انسان، جو اس کتاب کے مؤلف بھی ہیں ان کو بھی متأثر کردیا ہے۔
(۸۴)بربہاری جو ابن حنبل کی کتاب السنة، کی شرح ہے اس میں کہتے ہیں: ''اس بات کو دل وجان سے ماننا ضروری ہے کہ عمر اور ابوبکر عائشہ کے حجرہ میں مدفون ہیں۔ پس جب پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی قبر کے نزدیک آئو تو پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کو سلام کرنے کے بعد ان دونوں پر سلام کرنا واجب ہے۔'' طبقات الحنابلة، نامی کتاب کی ج۲، ص۳۵ سے ماخوذ ہے۔
صحابہ نامی مقالہ سے موازنہ کریں شارٹر انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں
Shorter Encyclopaedia of Islam.p.۸۸
اور اسی طرح العواصم والقواصم فی الذب عن سنة ابی القاسم، کی ج۳، ص۲۳۔ ۲۳۰ پر بھی ملاحظہ کریں۔
(۸۵)یہ نکتہ ایسے حساس نکات میں سے ایک ہے، جو بہت ہی قاطع اور ظریف ہے کہ اہل سنت وشیعہ اس طرف زیادہ متوجہ نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اصول اور اپنے عقائد کے مطابق ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں۔ ان نمونوں میں سے ایک بہترین نمونہ کتاب دلائل الصدق، ہے، جو مرحوم شیخ محمد حسین مظفر کی مؤلفہ ہے جو کتاب ابطال الباطل فضل بن روز بہان کی رد میں لکھی گئی ہے کہ خود یہ کتاب ابطال الباطل بھی علامہ حلی کی کتاب نہج الحق کی رد میں لکھی گئی ہے۔ اس کے متن میں کچھ غور و فکر کے بعد اور ابن روز بہان کی اس پر رد اور اس کے بعد مرحوم مظفر کی تنقید سے پتہ لگا لیتا ہے کہ بعض مباحث کاملاً دو مختلف بنیاد وںپر مبنی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے عقائد کے اعتبار سے مسائل پر غور و خوض کرتا ہے اور اسی معیار پر وہ اپنے مدمقابل پر تنقید کرتا ہے۔
(۸۶)بطور نمونہ مقدمہ مفصل ابوریدہ، رسائل الکندی، نامی کتاب پر رجوع کریں۔
(۸۷)صدر اول کے مقدس اور اس کے باعظمت ہوجانے کے سبب کو عبدالہادی حائری مشہور مستشرق انگریز، واٹ سے اس طرح نقل کرتے ہیں: ''تیسری صدی کی نویں اور آخری دہائیوں میں اکثر مسلمانوں پر واضح ہوگیا تھا کہ اپنی اسلامی ماہیت اور حقیقت کو محفوظ رکھنے کے لئے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو گذشتہ اسلام کی تاریخ کو یا کم از کم اپنے آپ کو صدر اسلام سے وابستہ کرلیں اسی صدی کے آخر میں زیادہ تر وہ لوگ جو طرح طرح کی مذہبی تحریکوں میں مشغول تھے سنی فرقہ کے رواج کو تمام اختلافات کے باوجود قبول کرلیااور یہ اسی معنی میں تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی ساتھی اور اصحاب احترام کے قابل ہیں ان میں سے ایک عثمان بھی ہیں جو صدر اول کے مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے نزدیک خلافت کی شائستگی کے بارے میں شک وشبہہ کررہے تھے وہ لوگ مورد احترام قرار پائیں... ادبیات کالج اور انسانی علوم مشہد کے جریدہ، شمارۂ سلسلہ ۵۶، ص۷۳۳۔
(۸۸)معتزلہ کی بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ ٹھیک جس زمانے میں ان کی سیاسی، معاشرتی، فکری اور مختلف دینی نظریات روبزوال تھے۔ اپنے آخری اعتقادی اصول و قواعد کو جمع کرنے کے لئے کمربستہ ہوگئے۔ اس پختگی کی معراج کو قاضی عبدالجبار کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے المغنی، نامی کتاب کے علاوہ کہ اس کی عظمت اور اہمیت کے باوجود علما اہل سنت کے ذریعہ غفلت برتی گئی ہے کہ فقط اس صدی کے پچاس کی دہائی میں یمن میں، معتزلی زیدیوں کا مرکز سامنے آیا، اس کے لئے الاصول الخمسہ، جو معتزلی فکر کی کتابوں میں سے بہترین کتاب ہے اور اپنی پہلی والی کتابوں سے زیادہ شرعی و قرآنی بنیادوں پر استوار ہے اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر یہ کتابیں اور دوسری اس طرح کی مشابہ کتابیں جلدی یا کم از کم ابوالحسن اشعری کی کتابوں کے ہمراہ آجاتیں تو اشاعرہ اس طرح کا کامل غلبہ حاصل نہیں کرپاتے۔ اس بارے میں کہ اشاعرہ کن حالات میں میدان میں آئے اور کن اسباب کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اس کے لئے بغداد کے بزرگ حنبلیوں کے ساتھ اس کی گفتگو کے ذریعہ آپ طبقات الحنابلة، مئولفہ بر بہاری کی ج۲، ص۱۸۔ ۱۹ پر رجوع کریں۔
(۸۹)ابن حنبل اور معتصم کی گفتگو کی طرف الفکر والدعوة فی الاسلام، نامی رجال کی کتاب، مولفۂ ابوالحسن ندوی، کے صفحات۱۱۸۔ ۱۲۰پر رجوع کریںاور خاص طورپر آپ، مناقب الامام احمد بن حنبل، نامی کتاب میں جو ابن جوزی کی مولفات میں سے ہے کے ص۳۹۷۔ ۴۳۷ پر رجوع کریں، جو معتصم اور واثق سے اپنی بحثوں کی داستان کو تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔
(۹۰)ضحی الاسلام، کی ج۳، ص۷۶۔ ۷۵، شرح ابن ابی الحدید، کی ج۴، ص۴۵۴ سے نقل کی گئی ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔
(۹۱)ضحی الاسلام، ج۳، ص۸۶۔ ۸۸۔
(۹۲)حوالہ سابق، ص۸۹۔
(۹۳)مقدمة ابن خلدون، ج۲، ص۹۰۷اور ۹۰۸۔
(۹۴)ابن حَزم: حیاتہ وعصرہ وآرائہ وفقہہ، ص۴۸۳ پر رجوع کریں؛ مزید وضاحت کے لئیاسی کتاب کے ص۴۸۳۔ ۴۸۵ پر رجوع کریںاور اسی طرح اس میں بھی رجوع کریں:
Goltziher, The Zahiris Their Doctorine and their History, PP.۱۹۰-۲۰۷
(۹۵)جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ شیعوں کے علاوہ صرف معتزلہ ہی تھے جو صدر اسلام کی تاریخ کو تنقیدی زاویہ نگاہ سے دیکھتے تھے: فجر الاسلام، ص۲۶۶۔ ۲۷۸، ان کے با مقابل اہل حدیث اور حنبلی فرقہ کے لوگ تھے جو اس تاریخی دورہ کو مقدس اور اس دور کے لوگوں کو مقدس ہونے کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہے تھے: ''چونکہ بنی امیہ کی تاریخ ان کے دشمنوں یعنی بنی عباس کے دور میں تحریر کی گئی لہٰذا ان کی خوبیاں نہیںلکھی گئی ہیں۔ لیکن احمد بن حنبل بعض امویوں کے صفات کو نقل کرتا تھا جس کی بناپر مستشرقین کو ان کی ان صفات کی تعریف کرنے پر مجبورکرتا تھا مثلاً ان کی امانت داری اور شجاعت کے بیان کرنے پر آمادہ کیا ہے۔'' ضحی الاسلام، ج۲، ص۱۲۲۔ ابن حنبل کی یہ روش زمانہ کے تقاضہ کے مطابق تھی فقط اس کے قطعی اعتقاد سے اس تاریخی دور کی حقانیت اور اس زمانہ کے افراد سے وجود میں آئی تھی۔ اس سلسلہ میں خاص طورپر الائمة الاربعة، کی ج۴، ص۱۱۷، پر رجوع کریں ان دو گروہ کے علاوہ عموماً اہل سنت متوسط موقف کے حامل تھے۔ الاقتصاد فی الاعتقاد، کے ص۲۰۳۔ ۲۰۵۔ گب کے نظریات سے اس کا مقایسہ کیجئے۔
(۹۶)یہ کہ اجتہاد و تأَوّل، (تاویل) کس طرح ان لوگوں کی برائت کا سبب بنا جو لوگ برے کاموں میں ملوث اور مفسد تھے اس کے لئے آپ مقدمہ متمتع سید محمد تقی الحکیم النص والاجتہاد، نامی کتاب کی طرف رجوع کریں و نیز یہ کہ خود اپنی کتاب میں اجتہاد کے کیا معنی ہیں، کہاں اور کن مواقع پر اجتہاد کرسکتے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ الغدیر، کی ج۱، ص۳۴۱۔ ۳۴۹ کی طرف رجوع کریں۔
اس مقام پرمناسب ہے کہ ایک نمونہ ذکر کریں۔ اس وقت جب خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی بیوی کے ہتھیانے کی لالچ میں پڑگیا اور اس کو قتل کردیا اور وہ مدینہ واپس آگیا، عمر نے ابوبکر سے چاہا کہ اس سے قصاص کرے۔ ابوبکر نے جواب میں کہا: ''اس کو قتل نہیں کرونگا۔ کیونکہ اس نے اجتہاد کیا اور اس میں اس سے خطا سرزد ہوگئی ہے۔'' الاسلام واصول الحکم، کے ص۱۷۹ پر رجوع کریں اس مفہوم سے بعد میں وسیع پیمانہ پر استفادہ کیا گیا۔ مجرمین کو بھی بری کرنے کے واسطے اور ان کی تاریخی وراثتوں سے بھی بری کرنے کے لئے اور اسی طرح سے اہل سنت کی تاریخی، کلامی اور فقہی افکار کو بنانے سنوارنے کے لئے بطور نمونہ آپ کنزالعمال میں، خالد بن ولید کے فضائل کے باب میں، ج۱۳، ص۳۶۶۔ ۳۸۰ پر رجوع کریں۔
بے شک اس کو منظم کرنے کی ضروریات میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے درجہ پر دائرہ اجتہاد کو وسعت دی جائے اور دوسرے درجہ میں ان اختلافات کی تفسیر وتوجیہہ تھی جو دو قابل اعتماد افراد کے درمیان پیدا ہوگئی تھی۔ مثلاً عمر اور خالد بن ولیدشعبی کے درمیان اختلاف کے اسباب کے بارے میں جو پہلی صدی کے آخری سالوں کے بزرگ فقہا میں سے ایک ہیں اور اہل سنت کے فقہی و کلامی افکار کو منظم کرنے اور بنانے و سنوارنے میں ایک مؤثر اور اساسی کردار ادا کرتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں: ''خالد عمر کا ممیرا بھائی (ماموں زاد بھائی) تھا بچپنے میں دونوں نے لڑائی کرلی۔ خالد نے عمر کا پائوں توڑدیا جو ایک عرصئہ دراز کے بعد اچھا ہوا۔ یہی واقعہ دونوں کے درمیان عداوت کا سبب بنا۔'' کنزالعمال، کی ج۱۳، ص۳۶۹اور اسی طرح آپ عمر ابن الخطاب،نامی کتاب کی طرف جو عبدالکریم الخطیب کی تصنیف ہے، اس کے ص۴۲۴۔ ۴۴۰ پر رجوع کریں۔
جنگ جمل وصفین کی توجیہہ اور تفسیر کے بارے میں کہ اس میں اس زمانہ کے برجستہ افراد ایک دوسرے کے مقابلہ میں بغیر اس بات کے کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی شخصیت اور موقعیت داغدار ہو اور پوچھ تاچھ کی جائے، اس کے لئے آپ مناقب الخلفاء الاربعةفی مؤلفات الشیعة، عبدالستار التونسوی کی تحریر کے، ص۶۴۔ ۷۰۔ پر رجوع کریں اور اسی طرح آپ البدعة تحدیدہا وموقف الاسلام منہا، کے ص۲۵۔ ۶۱، پر رجوع کریں۔ اثر عزت علی عطیہ، اس باب کے سلسلہ میں خاص طورپر آپ ، العواصم من القواصم، محب الدین الخطیب کے حواشی پر ملاحظہ کیجئے۔ وہ کتاب جو تاریخی اور دینی توجیہہ کی شاہ کار ہے اور یہاں تک کہ اس میں تاریخی اور دینی مسلمات کو اس کی حقیقی اور واقعی شکل کے خلاف مختلف شکل میں تفسیر اور توجیہہ پائی جاتی ہے مثلاً اس کے واسطے آپ معاویہ کا حجر بن عدی کے قتل کردینے کے دستور کو اس کے ص۲۱۱۔ ۲۱۳ پر رجوع کریں اور خطیب کے حاشیہ کے ص۲۱۲ پر ملاحظہ کیجئے ونیز آپ ، خطیب کی جانب سے یزید کے دفاع کے لئے، ص۲۱۴ پر رجوع کریں اور اسی طرح آپ ، ص۲۴۴۔ ۲۵۱ پر رجوع کریں کہ اس دوران ابن عربی، طبری کے علاوہ تمام مورخین کو محکوم کرتے ہیں اور یہ کہ خلفا کے فسق وفجور کی داستان کو کیوں نقل کیا ہے۔
اور اسی طرح آپ رجوع کریں۔ I.Goldziher, The Zahiris, PP.۳-۱۳
اور اسی طرح آپ ابن حزم کے نظریات رائے وقیاس اور تعلیل کے بارے میں رجوع کریں۔
(۹۷)نمونہ کے واسطے، آپ صدر اسلام کے مسلمانوں کی بہ نسبت ابن حنبل کے مختلف نظریات اور زاویہ نگاہ کے لئے آپ۔ الائمة الاربعة، کی ج۴، ص۱۱۷ پر رجوع کریںاور اس کو اس کے سیاسی افکار کے ساتھ مقایسہ کیجئے حوالہ سابق ص۱۹۔ ۱۲۔ ومخصوصاً آپ شرح کتاب السنة، مئولفۂ بربہاری کی طرف رجوع کریں، چوتھی صدی ہجری کے حنبلیوں کے بزرگ عالم، طبقات الحنابلة، کے ص۱۸۔ ۴۵ پر رجوع کریں۔
اور اسی طرح آپ الابانة عن اصول الدیانة، ابوالحسن اشعری کی کتاب کے ص۱۸۔ ۴۵ پر رجوع کریں۔
(۹۸)پچھلے زمانہ کے لوگوں کے بارے میں قضاوت کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں ان میں سے ہر ایک کا نظریہ اور موقف کیا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صداقت وحقانیت دونوں طرف کی صداقت اور حقانیت یقینی (محرز) ہے اور اسی لئے اقدامات کی توجیہہ کرنے کے واسطے بیٹھنا چاہئے۔ نمونہ کے واسطے فارسی ترجمہ ایہا الولد، غزالی، کے ص۳۰۔ ۳۱ پر رجوع کریں۔
(۹۹)آج کے جوان مسلمانوں کے درمیان انقلاب کی طرف مسلحانہ رجحانات اور میلان کی میزان کو کتاب الفریضة الغائیة، مصنفۂ عبدالسلام جوجہاد اسلامی نامی فرقہ کے ایک نظریہ پرداز تھے انہیں ان آخری سالوں میں پھانسی دے دی گئی ہے، اس کتاب میں پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ وہ اپنی اس کتاب کے ایک حصہ میں تحریر کرتے ہیں اس کے بعد کہ معاشرہ کو اسلامی کرنے کے واسطے تمام طریقوں کے بارے میں سفارش اور تجربہ کو بتایا گیا ہے اس بات سے عام ہے کہ احزاب اسلامی کی تاسیس کرنے، پڑھے لکھے مسلمانوں کی ایک نسل کی تربیت کرنا ان کے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے تک اور لوگوں کو راہ راست کی ہدایت اور وعظ ونصیحت کرنے اور دوسرے علاقہ میں ہجرت کرکے فاتحانہ طورپر واپسی کے لئے حالات کو ہموار کرنے اور انھیں کی طرح دوسری چیزوں کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اسلامی ممالک میں دشمن گھریلو یعنی داخلی ہے۔ (یعنی اپنے اندر ہی دشمن ہے) حقیقت میں وہی ہے جس نے سرداری کی کمان کو اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ اس کی نمائندگی کو دوسری حکومتوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، جس نے قدرت کو مسلمانوں کے ہاتھ سے اچک لیا ہے اور اسی وجہ سے تمام مسلمانوں پر جہاد واجب ہے۔'' کچھ توضیحات کے بعد اضافہ کرتے ہیں: ''خداوند عالم کے فرمان کو جاری کرنے کے لئے اسلامیحکومت کے لئے اقدام کرناضروری ہے۔ ہم اس پار یا اس پار کے نتیجہ پر اصرار نہیں کرتے۔ کافر حکومت کے نابود کرنے کے لئے ہر چیز مسلمانوں کے اختیار میں موجود ہے۔'' پیامبر وفرعون، کے ص۲۴۲۔ ۲۴۷ پر رجوع کریں۔
(۱۰۰)سعدالدین ابراہیم مصر میں اسلامی مجاہدین کی اہم خصوصیات کو، ۷۰ اور ۸۰ کی دہائی میں اس طرح بیان کرتے ہیں: ''کسی گروہ کی عملی شدت پسند ی ہرگز کسی حکومت اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو اسلام کے نام پر عمل کرتے ہیں، ان کے خلاف وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔'' Asaf Hussain, Islamic Movements, P.۲۹
(۱۰۱)نسل جدید کے اسلامی اور روشن فکر صاحبان قلم میں سے احتمالاً پہلا شخص جس نے کوشش کی تاکہ اپنی تعبیر کے مطابق ظاہری مسلمان حکام کی فریب دینے والی نقاب کو جس کو انہوں نے اپنے چہرے پر ڈال رکھی تھی اور حقیقت میں اس کے مخالف تھے کہ اس (نقاب) کو نوچ کر پھینک دے، وہ سید قطب تھے۔ خاص طور پر انہوں نے اپنی اہم ترین اور آخری کتاب معالم فی الطریق، اگرچہ یہ کتاب بعد میں بہت زیادہ تنقیدوں کا نشانہ بنی اور بجز ان جوانوں کے جو انقلابی رجحان رکھتے تھے کسی ایک نے بھی اس کی کلیت کو قبول نہ کیا۔ حتیٰ کہ حسن الھضیبی، اخوان المسلمین مصر کے رہبر، سید قطب کی پھانسی کے تختہ پر چڑھ جانے کے بعد صراحت کے ساتھ ان کی کتاب دعاة لاقضاة، میں انتقاد کیا اور یوسف العظم، اخوان المسلمینکا مشہور ترین دانشور اپنی کتاب رائد الفکر الاسلامی المعاصر، کے نام سے ان کے بعض افکار پر تنقید کی۔
لیکن ۷۰ اور ۸۰ کی دہائیوں کے سیاسی حالات نے ان کے افکار کی وسعت کے لئے مناسب حالات فراہم کردیا۔ عملی طور پر سنی دنیا کی موجودہ اسلامی تحریکیں خاص طورپر دنیائے عرب میں سید قطب کے افکار سے متاثر ہیں۔ چاہے اس کی افکار کو مجموعی طور پر قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ انہوں نے مبارزہ طلب اسلامی عقائد ( Idealogy ) کو حاصل کرلیا ہے۔ انہوں نے ایک بند جگہ سے اپنی فعالیت کا آغاز کیا اسی وجہ سے ایسا نہ کرسکے اور یہ ان کے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں کرسکتے اور نہ ہی ان کو اپنے اعتقادی اصول کو نظر انداز کرنا چاہئے اور اپنی اعتقادی بنیادوں کو اس کے علاوہ کسی اور چیز پر رکھیں۔ ہاںا یسا کرسکتے ہیں کہ ان اصول وضوابط کی دوسری تفسیر کرنے لگیں لیکن یکسر ان کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ جس وقت تک یہ ایسا کرتے رہیں گے تب تک ان پر اعتراض ہوتے رہیں گے اور کوئی اطمینان بخش جواب بھی نہیں دے سکیں گے اور ان کے اعتقادات بھی ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہوسکتے اور نہ ہی اس کو پائداری نصیب ہوگی۔
ان کی دوسری غلطی یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ انقلابی لوگوں کی فداکاری اور ایمان واستقامت اور پائداری کے سبب اپنے مقاصد تک پہنچنے کو قطعی بنالیں۔ یہ خیال بنیادی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے جز کو علت تامہ سمجھ لیا ہے اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر تکیہ اور تاکید کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے نجات دے لیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی اس غلطی میں دوسرے انقلابی اور غیر اسلامی گروہوں کے جیسے ہیں۔ نمونہ کے طور پر 'فدائیان خلق' انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی سے پہلے، پہلی دہائی میں انہیں توہمات اور غلطیوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے مصدق کے زمانہ کی مختلف پارٹیوں کو ان کی استقامت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر تنقید وتبصرہ کیا ہے اور فقط فداکاری اور استقامت میں ہی کامیابی کا راز سمجھتے تھے۔ اس کے لئے آپ، جزنی، احمد زادہ اور صفائی فراہانی کی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور خاص طورپر شخص اول یعنی جزنی کی کتابوں میں رجوع کریں۔ اسی طرح آپ، ایدئولوژی وانقلاب، نامی کتاب کے ص۲۱۴۔ ۲۲۰ پر۔ معالم فی الطریق نامی کتاب کی اہمیت کے باب اور اسی کے ذیل میں مختلف نظریات جو بیان کئے گئے ہیں، ان کی طرف رجوع کریں اور اسی طرح سید قطب کی کتاب مصنفۂ عبداللہ عوض اس، ص۳۲۵۔ ۳۲۹ پر رجوع کریں۔
(۱۰۲)دینی پابندیوں سے رہائی پانے کے لئے نسل جدید کی کوششوں کے بارے میں تامل آور السنة النبویة بین اہل الفقہ واہل الحدیث، نامی کتاب خاص طورسے، اس کے ص۷۔ ۱۲، مصنفۂ محمد الغزالی جو موجودہ زمانے کے معتبر ترین دینی عالم ہیں اس میں ملاحظہ کریں مفصل من العقیدة الیٰ الثورة، نامی کتاب جو پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اور دور حاضر کے روشن فکر اور اطلاع رکھنے والے شخص حسن حنفی کی تحریر ہے، خاص طور پر آپ ان کی جلد اول کے ص۷۔ ۴۷ پر رجوع کریں۔
(۱۰۳)نمونہ کے طور پر ماوردی کی تصنیف الاحکام السلطانیة، کے ص۵۔ ۲۱ پر رجوع کریں اور اسی طرح ابویعلی کی تصنیف الاحکام السلطانیة، کے ص۱۹۔ ۲۸ پر بھی رجوع کریں۔
تیسری فصل
حکومت اور حاکم
گذشتہ فصل میں مختصر طور سے بیان ہو چکا ہے کہ صدر اسلام کی تاریخ کس طرح وجود میں آئی اور بعد میں کن زاویہ نگاہ سے غور و خوض کیا گیا، اس نظریے نے اہل سنت کے فقہ و کلام اور ان کے سیاسی عمارت اور نظریات پر کیا اثر چھوڑا۔ لیکن ہم جدید بحث و گفتگو کے آغاز سے پہلے، ایک مختصر مقدمہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔
ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان اگرچہ بنیادی طور سے کافی حدتک اشتراک پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کے فقہی اور کلامی مسائل بھی الگ الگ ہیں اور دو مذاہب کے پیروکاروں کے مذہبی رجحانات اور معاشرتی مسائل بھی جدا جدا ہیں۔ اس بات کو واضح کرنے کے لئے کہ ان دونوں مذاہب کے دینی نظریات کس طرح وجود میں آئے اور کن عوامل و اسباب اور مراکز سے متاثر ہوئے ہیںاور اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ دونوں نظاموں کی حقیقت کیا ہے؟ اور تاریخی لحاظ سے یہ کیسے وجود میں آئے ہیں؟ اس مقام پر جو بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے (جاننا پڑے گا) کہ ان دونوں مکاتب فکر کی سیاسی بنیادیں کن اصولوں پر استوار ہیںاور کن اسباب وعوامل سے متأثر ہیں؟۔ کیونکہ ان دونوں مکتبوں کی سیاسی، معاشرتی تحریک یہاں تک کہ فکری اور ثقافتی تحریکیں خواہ مخواہ انھیں خصوصیات کے زیر اثر ہیں، جب تک ان خصوصیات کو نہیں پہچانا جائے گا، اس کے نتائج اور اثرات کی چھان بین نہیں کی جا سکتی اور اس وقت تک ان دونوں فرقوں کی دینی تحریکوں کو صحیح طریقہ سے نہیں پہچانا جاسکتا۔ چاہے گذشتہ زمانہ کی تحریکیں ہوں، یا دور حاضر کی تحریکیں۔
ہم یہ بیان کرچکے ہیں کہ وہ اہم ترین اصول جس نے ان دونوں فرقوں کے سیاسی نظریات کو جنم دیا، ان کی فہم اور تفسیر و توضیح کا سرچشمہ صدر اسلام کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے متعلق اہل سنت کی فہم اس کی حقیقت سے بالکل جدا ہے۔
دوسری اصل: حاکم کے سلسلہ میں اہل سنت کیاعقائد کی کیفیت اس لحاظ سے کہ وہ حاکم ہے۔ یعنی ان مسائل سے قطع نظر جو صدر اسلام میں پیش آئے اور اہل سنت نے اس سے جو سمجھا ہے، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہئے کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ اور اس نظریہ نے ان کے سیاسی نظریات پر کیا اثر چھوڑا ہے یا کیا اثر ڈال سکتا ہے۔ آخرکار تیسری اصل یہ ہے: جو چیز اہل سنت کے علما، فقہا اور متکلمین کی نظر میں حاکمیت اور اس کی مشروعیت کے متعلق اہمیت کی حامل ہے وہ امنیت ہے نہ کہ عدالت۔ (یعنی حاکم کے لئے عادل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف امن قائم کرنا ضروری ہے) وہ لوگ (اہل سنت) امنیت اور ایسی قدرت کے متعلق جو امنیت کی ضمانت لے سکے حساس تھے نہ کہ عدالت یا مثلاً شرعی قوانین اور قواعد و ضوابط اور سنت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم پر اس طرح سے اجرا کرنا جیسے خود حضور اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے زمانے میں تھی۔ شیعوں کا موقف اور زاویہ نظر آخری ان دو مسائل میں اہل سنت کے نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ اس اختلاف کے نتیجہ اور عکس العمل کو ان دونوں فرقوں کے پیروکاروں کی دینی اور معاشرتی تحریکوں کی تاریخ میں دیکھا جاسکتا ہے۔
یہ لوگوں (عوام الناس) کی عدالت دوستی اور عدالت خواہی ہی تھی جو سیاسی اور معاشرتی تحریکوں کا سرچشمہ ہے، اتفاق سے شیعہ حضرات اپنی ابتدائی تاریخ سے ہی مفہوم عدالت اور دینی قوانین وضوابط کے اجرا کے بارے میں پابند اور حساس اور اس پر زور دیتے چلے آئے ہیں۔ اور قیام عدالت اور دینی قوانین کی پابندی اور ان دونوں مسائل سے دفاع اور اس کے وجود عطا کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتے آئیں ہیں۔ جب کہ اہل سنت کی نظر میں عدالت کا مسئلہ اہمیت کے دوسرے اور یا پھر تیسرے درجہ کی اہمیت کا حامل ہے۔ جو چیز ان کی نظروں میں اہمیت کی حامل رہی ہے اور اب بھی ہے وہ اقتدار اور نظام ہے البتہ اس کے ذریعہ امنیت بھی برقرار کی جاتی رہی ہے۔ اس مقام پر ہم الگ الگ تمام مسائل پر گفتگو کریں گے۔
خلافت کی اہمیت
گذشتہ فصل میں بیان کرچکے ہیں کہ اہل سنت کے اس نظریہ کی پیدائش میں سب سے پہلا اور بنیادی سبب صدر اسلام کی تاریخ میں معاویہ کے اقدامات تھے۔
حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت اور آپ کی قدر و منزلت سے(۱) اس کی رقابت اور دشمنی اور آپ کے چاہنے والوں کو گوشہ نشین کرنے کی کوششوں کو بروئے کار لانا کہ سب کے سب معاویہ کے نظریاتی مخالف تھے، اس (معاویہ) کو اس بات نے اس پر ابھارا کہ وہ اپنے تمام والیوں اور کارندوں کو حکم دے کہ وہ آپ کو کھلم کھلا برا بھلا کہیں، (گالیاں تک دیں) سرعام آپ پر تبرّا کریں اور جیسی حدیثیں حضرت امیرـ کی فضیلت کے متعلق موجود تھیں، وہی کو دوسروں کے لئے بھی گڑھی جائیں اور انہیں کو رواج دیا جائے اور ان لوگوں نے یہ کام انجام بھی دیا۔
بے شمار دلیلوں اور وجوہات کے سبب حضرت امیرـ پر وہ سب و شتم اور لعن و طعن کا سلسلہ دیرپا نہ رہ سکا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ جس کی اہم ترین دلیلوں میں سے وہ فضائل تھے جسے دوسروں کے لئے گڑھا گیا تھا۔ کس طرح ممکن تھا کہ دوسرے افراد ایسے فضائل وکمالات کے حامل ہوتے اور حضرت علیـ جو کم از کم انھیں کے جیسے ایک افراد اور انھیں کی طرح ایک خلیفہ ہوتے ہوئے بھی ان کے یہاں یہ سب فضائل اور کمالات مفقود تھے جس کی وجہ سے ان کی مخالفت کی جائے اور مورد لعن وطعن قرار پائیں اور ان کو گالیاں دی جائیں۔(۲) اگر فرض کرلیا جائے کہ لوگوں میں ایسے عقائد کو قبول کروانے پر قادر تھے، تو ایسی صورت میں عام لوگوں کا عقیدہ خوارج کے مانند ہوجاتا اور اس کے نتیجہ میں خوارج ان سے نزدیک ہوجاتیاور یہ چیز بھی خود نظام حاکم کے نزدیک نفرت اور خوف و ہراس کا باعث ہوتی، چاہے موجودہ نظام بنی امیہ کا ہوتا یا بنی عباس کا ہوتا، کیوں کہ خوارج ان (بنی عباس اور بنی امیہ) کے سرسخت دشمنوں میں سے تھے۔ لیکن دوسرے اقدام نے اپنا گہرا اثر چھوڑا اور صدر اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی شان اور اہمیت کو اعلیٰ درجہ تک پہنچاکر اس کو اسلام کے برابر کردیا۔ البتہ معاویہ کے نقشوں کے علاوہ، اس سلسلہ میں دوسرے اسباب وعوامل بھی دخالت رکھتے تھے جو ایسے عقیدے کے استحکام واستقرار میں مددگار ثابت ہوتے جن کی طرف میں درج ذیل عبارت میں اشارہ کررہا ہوں۔
خلفائے راشدین (ابوبکر، عمر، عثمان وحضرت علیـ) کے بعد والے خلفا چاہے اموی ہوں یا عباسی اور چاہے ان کے علاوہ ،وہ تمام افراد جو تاریخ اسلام میں خلیفہ کے عنوان سے سامنے آئے اور ان کی خلافتوں کو لوگوں کے درمیان قبول کیا گیا ہو، مصر کے خلفائے مملوک کی طرح، عثمانی حکومت کے دورہ کے سلاطین، اپنی منزلت اور مقام کو منوانے کے لئے محتاج تھے کہ وہ اپنے لئے دینی شان وحیثیت کے قائل ہوں اور اسے لوگوں سے منوائیں۔ اور اس بات کے لئے بہترین وسیلہ یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ وہ اس منصب کے لئے ایسی حیثیت اور مقام ومنزلت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جس گدی پر وہ خلیفہ بن کر براجمان تھے۔ تاکہ اس کے ذریعہ اپنے لئے جواز اور قانونیت ثابت کرلیں اور اس کا لازمہ یہ تھا کہ اپنی قدرت بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفا کی قدر و منزلت کو اونچا کیا جائے اور خلافت کو ایک الٰہی اور دینی امر بناکر پیش کیا جائے اور خلفا کے ماننے والوں (طرفداروں)اور خلافت کو مقدس ثابت کریں۔ کلی طورپر اس زمانے کی تاریخ اور اس کے لوگوں کو ایک خاص دینی اہمیت اور تقدس سے نوازیں۔ کیونکہ اس کے ذریعہ اپنے منصب خلافت کو ایک خاص حیثیت بلکہ ضرورت دین بناکر سامنے لائیں اور یہ عظمت خود ان کی شان ومنزلت کو بھی شامل ہو جائے گی، اس لئے کہ اس کے سہارے خلیفہ یا حاکم بنے تھے۔(۳)
در حقیقت اموی خلفا اس بات پر زیادہ مائل تھے کہ وہ خلیفہ کے عنوان سے پہچانے جائیں۔ کیونکہ نہ تو ان کو اس کی کوئی خاص ضرورت تھی اور نہ ہی ان کی ابتدائی اور جاہلیت کے زمانے کی فطرت اور لاپرواہی اور لاابالی گری سے سازگار تھی۔ لیکن خلفا بنی عباس، خلافت اور حکومت کا سہارا لئے بغیر باقی نہیں رہ سکتے تھے۔ مسلسل پانچ صدیوں تک ان حکومت کا باقی رہنا اگرچہ بہت سے حصوں میں ان کی حکومت وخلافت صرف ظاہری تھی، لیکن بہرحال اسی دینی خلافت کے عنوان ہی کی مرہون منت تھی جو چل رہی تھی۔ بنی عباس نے ان مسائل اور بدعتوں جس کی معاویہ نے مختلف دلائل کے تحت بنیاد ڈالی اور وہ اس کا بانی تھا انہیں کو بے حد اچھالا۔ باوجود اس کے کہ بنی عباس کے دور میں معاویہ کی بہت سی کلی سیاستوں اور بنی امیہ کا یکسر انکار کیا گیا، لیکن دراصل یہ ایک استثنائی موارد میں سے تھا جس کی تائید و تصدیق کردی گئی۔ کیونکہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بعد آنے والے خلفا کا ا لٰہی اور مقدس ہونا خلافت کے نظام اور خلیفہ کے تقدس کو ثابت کرنے اور اس کے ذمہ دار کیلئے مددگار تھا۔(۴)
دوسر اسبب جو ایسے موقف کی تقویت اور مدد کررہا تھا، وہ شیعوں اور خوارج سے مقابلہ کی وجہ سے تھا۔ پہلی دو صدیوں بلکہ تین صدیوں تک چاہے اموی خلفا ہوں یا عباسی زیادہ اہمیت کے حامل مخالفین شیعہ تھے۔ اور یہ دونوں گروہ صدر اسلام کی تاریخ کے متعلق تنقیدی نظریہ رکھتے تھے۔ شیعوں کا نظریہ تو معلوم ہی ہے کہ دوسرے دوروں کی طرح صدر اسلام کو بھی جانتے تھے اور ان کے درمیان کسی فرق کے قائل نہیں تھے، لیکن خوارج خلفا راشدین کے پہلے حصہ سے لے کر عثمان کے درمیانی زمانہ تک کی تائید کرتے تھیاور دوسرے حصہ کو اپنے نظریہ کے لحاظ سے شرک اور دین سے خروج کی تاریخ سمجھتے تھے۔ مزید یہ کہ خوارج کا پہلے حصہ سے ان کی اپنی سمجھ سے بالکل دوسرے لوگوں کے فہم کی طرح نہیں تھی اور ان لوگوں کی بہ نسبت کچھ مختلف تھے۔ وہ لوگ (خوارج) خشک ذہنیت کے مالک افراد تھے جو کبھی کسی فرد، شخص یا زمانہ کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنے پر تیار نہیں تھے۔ بلکہ وہ صرف اس زمانہ کو جوان کی رائے کے موافق تھا، یعنی اس دور پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے ،اسے قبول کرتے تھے۔(۵)
بہرحال عام مسلمانوں کی نگاہ میں ان دونوں گروہوں سے مقابلہ کرنے کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں گروہ اس بات کا اقرار کریں کہ صدر اسلام کی تاریخ کی حقانیت ان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ جتنا ممکن ہو اس دور کی تعریف اور تحسین کریں۔ اس دور کی الٰہی اور دینی قدر وقیمت عام لوگوں کے نزدیک جتنی زیادہ ہوتی جائے گی، مخالفین اتنا ہی خلع سلاح (نہتھے) ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دور کے خلفا کا ایک اہم ترین اور دھوکہ دھڑی والے حربوں میں سے ایک یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے مخالفین سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں ناحق سمجھتے ہو اور ہم سے مقابلہ کرنے کے لئے کمربستہ ہو خود تم ہی لوگ مشروعیت نہیں رکھتے ہو۔ یعنی خود تمہاری بھی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ صدر اسلام اور اس دور کی شخصیتیں تمہارے لئے مورد احترام اور اعتقاد نہیں ہیں(۶) خاص طورپر اتفاقاً یہ تہمت شیعوں کے اوپر زیادہ سخت مؤثر تھی اور ایک زمانہ تک بہترین حربہ کے عنوان سے شیعوں کے خلاف استعمال کی جاتی تھی۔ گذشتہ تاریخ میں ایسی بیشمار مثالیں مل سکتی ہیں جواس حربہ کے ذریعہ مخالفین کی تحریک کو نطفہ میں (شروع میں) ہی اس کا گلا گھونٹ کر ان کو نیست و نابود کردیا اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ اگرچہ ابھی تک یہ حربہ کند نہیں ہوا اور خاص طور سے آج بھی سعودی اور ان کے ہم خیالوں کے ذریعہ یہ حربہ وسیع پیمانہ پر استعمال کیا جارہا ہے۔ وہ لوگ (سعودی) اپنی شیطانی چال کے ذریعہ صدر اسلام کی ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جس کے مقابلہ میں ہر طرح کے تنقیدی موقف کو باطل اور محکوم کر دے تے ہیں اور اپنی پوری طاقت وقدرت کے ذریعہ آگ کو شعلہ ور بنانے میں ہوا کا کام کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ شیعہ کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائیں اور ان کو لوگوں کی نظر میں بُرا بناکر گوشہ نشین کردیں اور اسی طرح ہر اصلاح طلب تحریک کو بھی اسی عنوان کے تحت کچل دیں۔ اس لئے کہ عموماً اصلاح طلب اور انقلابی تحریکیں اہل سنت کی نگاہ میں صدر اسلام کی تاریخ کے مقابلہ میں تنقیدی موقف کے حامل ہیں بلکہ اصولی طورپر خود تاریخ اسلام کے ہی خلاف تنقیدی موقف کے حامل ہیں اور جب اصل نظریہ اور طرز فکر ہی مورد سوال واقع ہوجائے گا تو لامحالہ اس (نظریہ) کے قائلین بھی مورد تردید قرار پائیں گے اور ان کے مخالفین کا اصلی ہدف اور مقصد بھی یہی ہے۔(۷)
درحقیقت یہ دو اہم اور سیاسی اسباب تھے جو صدر اسلام کے الٰہی اور دینی پہلو کی زیادہ سے زیادہ تقویت کرنے میں مددگار تھے۔ معاویہ کے بعد کے، خلفا، بھی مختلف انداز میں مختلف عنوان کے تحت ان اسباب کے محتاج تھے اور اس بات پر تاکید کرتے تھے۔ یہ ضرورت بھی اس وقت تک باقی تھی، جب تک ان کی خلافت برقرار تھی۔ یعنی عملی طور پر موجودہ صدی کی ابتدا تک اس کے بعد بھی آنے والی حکومتوں کے حاکم جو خود اپنے آپ کو اپنے زعم ناقص میں سلف صالح کا پیرو سمجھتے تھے وہ لوگ بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔
صدر اسلام کا تقدس پانا
البتہ اس دوران دوسرے اقدامات بھی انجام پائے جس کے نتیجہ میں ان حوادث میں مزید شدت پیدا ہوگئی اور اس میں بھی معاویہ ہی اساسی کردار کا حامل تھا۔ معاویہ نے اپنے حق اور اپنی حکومت کی حقانیت اور مشروعیت کا دفاع کرنے کے لئے دوسری گندی اور دھوکہ دھڑی کی سیاست کا سہارا لیا، جس میں اس کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے نزدیک صدر اسلام کی تاریخ کے چہرے پر تقدس کے نقاب اوڑھانے میں بھرپور مددگار تھی۔ وہ چاہتا تھا خود اپنے اور اپنی حقانیت اور پہلے والے خلفا اور ان کی حقانیت، خاص طور سے ابوبکر اور اپنے درمیان تعلق برقرار کرے۔ لیکن جب تک حضرت علیـ زندہ رہے، نہ تو یہ حربہ کامیاب ہوسکا اور نہ ہی حضرت امیرالمومنین علیـ نے اس سے سوء استفادہ کی ہی اجازت دی، آپ کی بے نظیر شخصیت، آپ کی موقعیت (قدر و منزلت) اور آپ کا منحصر بہ فرد ماضی اور آپ کا مسلمانوں کی اکثریت آرا ان کے اتفاق سے خلافت اور امامت کی مسند پر رونق افروز ہونا، ایسے وسیلہ سے سوء استفادہ کرنے میں ایک بہت بڑا مانع اور رکاوٹ تھی۔ لیکن جب امام علیـ کی شہادت ہوگئی اور امام حسنـ نے حکومت کو سنبھالا تو ان حربوں سے غلط استفادہ ممکن اور آسان ہوگیا۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس حربہ سے سوء استفادہ کی کیفیت کو خود معاویہ ہی کی زبانی سنیں۔
معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے اس خط کے جواب میں جس میں صلح اور جنگ سے خلاحی کے مسئلہ کو بیان کیا گیا تھا، اس نے اس طرح لکھا ''...حضور اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد اس امت نے جس وقت آپ کی فضیلت اور حضورصلىاللهعليهوآلهوسلم سے آپ کی قرابت اور درخشاں ماضی اور اسلام و مسلمانوں کے درمیان آپ کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اس سلسلہ میں اختلاف کیا تو کیا اس وقت وہ لوگ ان سب باتوں سے بے خبر تھے؟ ان لوگوں نے مصلحت اس میں جانی کہ حضور اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے قرابت داری کی بناپر، قریش خاندان کے افراد حکومت و خلافت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ قریش وانصار کے بزرگوں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ خلافت کی ذمہ داری کو قریش کی ایسی شخصیت کے سپرد کریں جو اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے قدیم تر ہو خداکی بہ نسبت اس کا علم اور اس سے اس کی دوستی زیادہ اور گہری ہو اور اس کے امر میں سب سے قوی اور مقتدر ہو، لوگوں نے ابوبکر کو چن لیا اور یہ کام (انتخاب) صاحبان عقل ودین وفضیلت اور اس امت کے آگاہ ترین لوگوں کی رائے سے انجام پایا... اور اگر تمہارے درمیان مسلمان لوگ کسی کو ان صفات کا حامل پاتے تو شروع سے ہی اپنی رائے سے نہ پلٹتے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی نظر میں اسلام اور مسلمانوں کے حق میں جو بہتر سمجھا، اسی پر عمل کیا... اور ہماری تمہاری کہانی بھی حضورکی رحلت کے بعد تمہاری اور ابوبکر کی داستان کی طرح ہے۔ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد اگر میں اس بات کو جانتا کہ تم مجھ سے زیادہ اس امت کے امور کو سنبھالنے کی قدرت رکھتے ہو تو میں ہر اس چیز کو جس کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو قبول کرلیتا۔ لیکن تم خود بھی اس بات کو جانتے ہو کہ میری حکومت کی مدت اور میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے۔ میں تم سے زیادہ سیّاس اور تم سے زیادہ سن رسیدہ ہوں لہٰذا تمہارے لئے بہتر یہ ہوگا کہ جس بات کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس میں تم میری بات مانو اور میری اطاعت اور میرے حکم کی پیروی کرو...''(۸)
معاویہ اس بیان کے ضمن میں اس بات کی کوشش کررہا تھا کہ انہیں گذشتہ دلائل کا سہارا لے کر اپنے آپ کو قانون مند اور اس سے اپنی مشروعیت ثابت کرے جن دلائل کے سہارے ابوبکر نے اپنے آپ کو مشروع اور قانونی ثابت کیا تھا اور اس طرح تظاہر کرتا تھا کہ اس کی داستان بھی ابوبکر کی ہی داستان ہے اور یہ کہے کہ جن معیار کے تحت ابوبکر نے مقبولیت اور مشروعیت حاصل کی ہے اس نے بھی بالکل اسی کی طرح مشروعیت اور قانونیت حاصل کی ہے۔ اور حتی کہ امام حسنـ کو بھی اس کے مقابلہ میں سر تسلیم خم کردینا چاہئے۔
محمود صبحی اس سلسلہ میں یوں بیان تحریر فرماتے ہیں: ''معاویہ کا یہ خط عام طور سے مسئلہ خلافت، خاص طور سے بیعت ابوبکر کے سلسلے میں اہل سنت و جماعت کے عقیدم اور نظریہ کی سب سے پہلی کلامی تفسیر ہے۔ معاویہ نے اقتدار پاتے ہی، کلامی اور عقیدتی کامیابی حاصل کرلی۔ اور اس طریقہ سے تمام سنی مسلمانوں کے عقائد کا بیان کرنے والا بن جائے... اس نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا، تاکہ خلفا اور بزرگان اصحاب کے دفاع کی ذمہ داری کا خود بہ نفس نفیس عہدہ دار ہوجائے اور اس طریقہ سے مسئلہ خلافت میں اپنے دعوی کو شرعی رنگ دے دیا اور بڑی ہی چالاکی کے ساتھ ابوبکر کی بیعت سے دفاع کے قالب میں اپنے دعویٰ کو پیش کردیا۔ اس تفسیر اور تحلیل کی رو سے اس نے خلافت کو غصب نہیں کیا اور خود زبردستی امت کے اوپر نہیں لادا تھا۔ بلکہ اس کی موقعیت اور حیثیت ابوبکر کی موقعیت اور حیثیت کی طرح تھی۔ وہ امور مملکت کو چلانے میں دوسروں سے قوی تر اور دیگر میدانوں میں دوسروں سے زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ کا مالک اور دوسروں سے زیادہ تجربہ کار اور عمر میں بھی سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا۔ اس طرح حضرت امام علی علیہ السلام کے دور میں عثمان کے خون کا انتقام لینے پر مبنی معاویہ کا دعویٰ زیادہ خطرناک، موثر، مقبول تر نظریہ میں تبدیل ہوگیا جو اس کے خلافت تک پہنچنے کی ہوس کے لئے اپنے منشأ کے مطابق جواب دہ تھا اور خلافت کو معاویہ کے حق میں ثابت کرتا تھا۔''(۹)
نتیجہ یہ کہ ان عوامل اور اسباب کے علاوہ جن کو پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ جن اسباب نے معاویہ کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے مخالفوں اور ان میں سر فہرست شیعوں کے حوصلوں کو پست کرنے اور لوگوں کے ذہنوں میں حضرت علی علیہ السلام کی قدر ومنزلت گھٹانے اور گرانے کے لئے صدر اسلام کی تاریخ اور اس کی شخصیتوں کو دینی قدر و منزلت سے نوازے، دوسرے اسباب بھی پائے جاتے تھے جو معاویہ کو اس کام کے لئے رغبت دلاتے تھے۔ اسے امام اور آپ کے شیعوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے، چاہے آپ کی زندگی میں یا اس کے بعد اس تاریخی دور کا سہارا لئے بغیر اپنی مراد کو نہیں پاسکتا تھا۔ اسے کامیابی حاصل نہیں ہوسکتی تھی۔ وہ اس کا محتاج تھا اور مختلف عنوانوں کے تحت اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان اسباب سے اس طرح فائدہ اٹھانا جس کو بعد میں اہل سنت کے فقہی اور کلامی عمارت، خصوصاً امامت اور خلافت کے مسئلہ میں، ایک بلند مقام حاصل کرلیا تھا۔ بے شک اگرامام علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص معاویہ کا اصلی رقیب ہوتا، یا امام علیہ لسلام کے سامنے معاویہ کے علاوہ کوئی اور شخص اپنی ان خصوصیتوں کے ساتھ ہوتا، تو نہ صرف یہ کہ زمانہ کی تاریخ کسی اور شکل میں سامنے آتی، تقریباً یقینی طور سے جس میں اس زمانے کمے اہل سنت کی فقہی اور کلامی عمارت اور اس کی آج کی عمارت میں بہت بڑا فرق پیدا ہوجاتا۔
البتہ مذکورہ اسباب کے علاوہ جو اکثر سیاسی تھے دوسرے دو دینی اسباب بھی پائے جاتے تھے جو ان حوادث کی مدد کرتے تھیاور ذیل عبارت میں ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے۔
جدید مسائل
پہلا سبب دین کے مختلف مسائل چاہے وہ فقہی مسائل ہوں یا کہ کلامی اور خصوصاً فقہی مسائل کے جواب دینے کی ضرورت تھی کہ مسلمان پہلی صدی کے آخر بلکہ پہلی صدی کے وسط سے ہی ان مسائل سے دوچار ہوئے اور پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کی سنت میں اس کو صریح اور واضح جوابات نہیں مل پاتے تھے۔ وہ لوگ مجبور تھے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے چارہ جوئی کی فکر میں پڑیں، اس کا ایک بہترین راہ حل یہ تھا کہ صدر اسلام کی تاریخ کو دین کے مساوی کردیں اور ان مسائل کے جوابات کو صرف سنت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم سے ہی اخذ نہ کریں بلکہ اس دور سے بھی حاصل کریں اور یہ ایک فطری عمل ہوگا۔
حضور اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے زمانہ میں اسلامی معاشرہ، ایک محدود معاشرہ تھا۔ ضروریات بھی کم تھیں اور روز مرہ پیش آنے والے مسائل بھی کم تھے۔ جب بھی کوئی جدید مسئلہ پیش آتا تو اسے بغیر کسی واسطہ کے حضور اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خدمت میں سوال کرلیتے تھے۔ لیکن یہ حالات اسلام کی تیزی سے ترقی کے سبب تبدیل ہوگئے اور خصوصاً ابتدائی اہم فتوحات اور دینی جوش وجذبہ کے تھم جانے اور اسلامی معاشرہ پہلی صدی کے وسط سے پرسکون ہونے کے پھر سے بعد بدل گئے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ معاشرہ کمی اور کیفی (عدد اور کیفیت کے) اعتبار سے ترقی کرچکا تھا۔ بلکہ کیفیتی پیچیدگی جو کمی (افراد کی کثرت والی) ترقی کی وجہ سے وجود میں آئی تھی کئی گنا زیادہ تھی اور روز بہ روز پیچیدہ تر ہوتی جارہی تھی۔ ملتیں، ثقافتیں، فلسفے، مذاہب اور مختلف فرقے اور ادیان نئی قدرت کے ماتحت تھے جس پر دینی رنگ چڑھا ہوا تھا، دینی دعوت بھی تھی اسی اعتبار سے وہ وجود میں آئے ایسے معاشرے نئے نئے بہت زیادہ مسائل بھی اپنے ساتھ لیکر آئے جو جواب کے طالب تھے۔ ایسے جوابات جو واضح وروشن اور عملی ہوں صرف نظری نہ ہوں کیوں کہ ضروری تھا کہ معاشرہ کو انھیں جوابات کی بنیاد پر چلایا جائے۔ درحقیقت یہ جوابات ایسے قوانین تھے جو معاشرہ کو نظم وضبط عطا کرتے تھے۔
یہاں پر پریشانی یہ تھی کہ ان جدید مسائل کے کچھ ہی حصے کا جواب سنت پیغمبر میں صریح اور مستقیم طورپر دیا گیا تھا۔(۱۰) یہ سوالات جدید موضوعات سے متعلق تھے جو اس زمانہ میں نہ تو نظری اعتبار سے ہی وجود رکھتے تھے اور نہ ہی عملی لحاظ سے۔ لیکن اب (جدید زمانہ میں) نظری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی جواب کے خواہاں تھے۔ اسی پس وپیش میں مسلمان مجبور ہوگئے کہ حیات پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے دور سے زیادہ طولانی زمانے کے لئے اور ایک عرصہ دراز کے لئے دینی رسمیت کے قائل ہوجائیں اور یہی وہ خلفاے راشدین کا دور تھا۔
بے طرف اور حقیقت بین نظریہ کی بنیاد پر یہ کہنا چاہیے کہ حق انھیں لوگوں کے ساتھ تھا، اگر یہ طے ہو کہ تاریخ اسلام کے ایک حصہ کو پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم کے دور سے ظاہری شباہت کی بناپر قانونی سمجھا جائے، بیشک یہ وہی دور تھا۔ خاص طور سے جس پر اکثر مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے اور ان کے نزدیک مورد احترام بھی اور ان کے بعد جتنے بھی دور گزرے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تھی۔ جس کے نتیجہ میں اس دور کو استمرار سنت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم سمجھایا گیا اور ان بے شمار پیش آنے والے سوالوں کے جوابات کیلئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خصوصاً اس زمانہ میں جب اجتہاد فقہی، اس کے ارکان اور وہ روش وجود میں نہیں آئی تھی جیسا کہ بعد میں پھولا پھلا، لہٰذا ہر موقع پر مجبور تھے کہ نص پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی طرف رجوع کریں۔(۱۱)
لیکن شیعہ بنیادی طور پر ان مشکلات سے دوچار نہ تھے۔ ان کے عقائد میں ائمہ معصومین (ع) کا قول و فعل اور تقریر (کسی کام کے سامنے معصوم کا خاموش رہنا) وہی سنت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم تھی اس عقیدہ کو نہ تو کسی تاریخی ضرورت نے شیعوں پر تحمیل کیا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے سبب نے۔ بلکہ اصل امامت پر ان کے فطری اور منطقی اعتقاد کا نتیجہ تھا،جس معنی میں وہ سمجھتے اور تفسیر کرتے تھے، ویسے ہی تھا۔ اس طرح سے ان کی نظر میں ۲۶۰ ہجری قمری تک جو امام حسن عسکریـ کی رحلت کا سال تھا، ایک معتبر اور شرعی سنت کے اعتبار سے چلتا رہا۔ یہ غنی اور بہت ہی متنوع میراث جو مختلف مسائل کے جوابات کا ماحصل تھی جو ۲۷۳ سال تک زمانہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے لے کر ائمہ(ع) کی امامت کے زمانے کے علاوہ غیبت صغریٰ کے آغاز تک لوگوں کے درمیان رائے تھی، نیز اصل اجتہاد اور اس کی حدبندی اور اس کے مبانی (معیار و ملاک) کی تعیین پر شیعوں کی تاکید بھی تھی، اصولاً اہل سنت کے نزدیک جن موضوعات کی بہت سخت احتیاج تھی اس ضرورت کے احساس کو بالکل ختم کردیا تھا۔
نفسیاتی جاذبے و قلبی کشش
دوسرا سبب ایک نفسیاتی اور دینی سبب تھا، اصولاً انسان جذباتی اور نفسیاتی لحاظ سے ایک ایسے وجود کا نام ہے جو ان تمام چیزوں کو دوست رکھتا ہے اور اس کی طرف لگاؤ رکھتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ایسی شے یا فرد سے وابستہ ہو جسے وہ چاہتا ہے۔ چاہے وہ وابستگی حقیقی اور و اقعی ہو یا صرف وہمی اور غیر واقعی کی حدتک ہو، (یعنی حقیقت و واقعیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو) لیکن صرف یہی کافی ہے کہ وہ وابستگی کا تصور کرے۔ قدیم زمانہ میں یہ سبب آج کل سے کہیں زیادہ قوی اور موثر تھا۔ آج کا انسان گذشتہ انسانوں سے زیادہ فکری اور نفسیاتی پراگندگی اور پریشانی کا شکار ہے۔ جس کے نتیجہ میں اس کی دوستی اور چاہت کی پائداری اور گہرائی بھی کم ہوگئی ہے۔ لیکن گذشتہ زمانے میں اگر کوئی کسی شے یا شخص کو دوست رکھتا تھا تو وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ اس میں جذب ہو جاتا تھا اور جتنا زیادہ جذب کرنے یا جذب ہونے کی کیفیت قوی تر اور عمیق ہوتی تھی اس شے یا شخص سے وابستہ دوسری اشیا سے تعلق بھی اتنا ہی گہرا اور زیادہ ہوجاتا تھا اور اپنے محبوب کے لئے جن خصوصیات کا قائل ہوتا تھا خود اس سے وابستہ شے اور افراد کے اندر بھی انھیں خصوصیات کا قائل ہوتا تھا۔
حضرت محمد مصطفیصلىاللهعليهوآلهوسلم پوری تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ محبوب اور مقدس ترین شخص تھے۔ خوبصورت ترین اور عارفانہ ترین تو صیف و تعریف آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے سلسلہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اس میدان میں صوفیوں کے خواص سب سے آگے نکل گئے، فطرتاً اور نتیجتاً ایسی جذاب شخصیت کی مقناطیسی کشش آپ کے چاہنے والوں کے ذہن کے لحاظ سے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے حاشیہ نشینوں میں بھی سرایت کرگئی اور یہ کارروائی فطری اور انسانی رد عمل ہے۔ اصلاً یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی شخصیت کے مقناطیسی مدار میں جذب ہوجائے اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم سے وابستہ اور منسلک افراد کو دوست نہ رکھے۔ اس مقام پر مسئلہ یہ نہ تھا کہ حضورصلىاللهعليهوآلهوسلم سے وابستہ اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم سے متعلق رہنے والے کون لوگ تھے اور ان کی زندگی کیسی تھی؟ بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ افراد پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے حاشیہ نشین اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اصحاب ہیں۔
صوفی حضرات بلکہ عام مسلمانوں نے پوری تاریخ اسلام میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اطرافیوں اور صدر اسلام کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں وہ بہترین دور تھا کیونکہ اس دور میں پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم بہ نفس نفیس موجود تھے اور وہ لوگ بہترین افراد میں سے تھے، کیونکہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اردگرد رہ کر اپنی زندگی بسر کررہے تھے اور اسی طرح سے اپنی زندگی گذاررہے تھے۔ البتہ اگر چہ یہ بات حق ہے لیکن اس کے حدود اور مفہوم کو واضح ہونا چاہئے۔ یہ سچ ہے کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے دور نے اس وجہ سے عزت اور شرافت حاصل کرلی تھی، کہ آپ اس دور میں زندگی بسر کر رہے تھیاور سچ ہے کہ آپ کے حاشیہ نشین اس وجہ سے کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، سعادت و بزرگی کی توفیق سے سر فراز ہوئے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے زمانہ سے نزدیک والے ہر زمانہ میں لازمی طور سے زیادہ شرافت پائی جائے گی، تاکہ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ صحابۂ کرام کا زمانہ حضور اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے زمانہ سے نزدیک ہونے کی وجہ سے دوسرے زمانوں سے بہتر ہو گیا ہے اور مثلاً اسلام کو اسی صحابہ کے زمانے کے ذریعہ پہچانا جائے!اور یا صحابہ کا بزم پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم میں حاضری کی تو فیق حاصل کرلینے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنی عملی زندگی میں پابند دین اور متعھد مسلمان کی حیثیت کے حامل تھے۔(۱۲)
بہرحال یہی روحی نظام اور نفسیاتی حالت سبب بنی کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کا تقدس صحابہ اور زمانہ صحابہ تک سرایت کرجائے اور سب کے سب ایک قسم کے الٰہی تقدس کے ہالہ میں چھپ جائیں۔ اس نے خود اپنے طور پر بھی ان مسائل اور حوادث کی مدد کی ہے جس کا مقصد صدر اسلام کو دینی مقام و منزلت عطا کرنا تھا۔ یہ کہ شیعہ حضرات کیوں اس فطری حالت اور روحی نظام سے متاثر نہیں ہوئے اس پر خاص دلیل پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ (شیعہ)دوسرے مسلمانوں کی طرح ہمیشہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے والہانہ عشق و محبت میں سرشار تھے آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کو بہترین اور برترین انسان جانتے تھے، لیکن شیعوں کے نزدیک بہت معتبر احادیث کی بنا پر جو ان کے نزدیک صحیح اور تمام ہیں... نہ کہ تمام اصحاب پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بارے میں جو خاص گروہ سے اظہار محبت و مودت کرتے تھے۔ اگر ایسی حدیثیں موجود نہ ہوتیں تو شیعہ حضرات بھی دوسروں کی طرح پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے معنوی شان و تقدس کو دوسروں تک پہنچا دیتے کیونکہ انسان کی فطرت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔
اس مقام پرمناسب ہے کہ ایک نمونہ ذکر کریں اور یہ کہ بعد کے زمانہ میں آنے والے مسلمانوں کی نظر میں، پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے حضور کو درک کرنے نے کیا قدر و قیمت حاصل کی اور کس طرح افراد کی دینی اور معنوی صلاحیت کے پرکھنے کے لئے سب سے اہم ترین اور اطمینان بخش ترین ضابطہ اور میزان بن گیا۔
ابن حجر، ابن عبد البر کے نظریے پر تنقید کرتے ہوئے جو اس بات کا معتقد تھا کہ ممکن ہے آیندہ آنے والے زمانوں میں لوگوں کے درمیان کچھ ایسے افراد بھی ہوں جو صحابہ سے افضل ہوں، جس کی دلیل یہ حدیث ہے: ''میری امت بارش کی طرح ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی ابتدا بہتر ہے یا انتہا'' اور دوسری حدیثیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں، (ان کی تنقید میں) وہ (احادیث) اس طرح بیان کرتی ہیں: ''یہ ایک بہت ہی شاذ و نادر نظریہ ہے اور یہ حدیثیں اس مطلب پر دلالت نہیں کررہی ہیں۔'' اور پھر اس وقت وہ (ابن حجر) ان مطالب کے ذریعے کہ جنھیں ابن مبارک سے نقل کیا ہے اپنے نظریئے کی یوں تائید کر رہا ہے: ''عبداللہ ابن مبارک نے بھی جو کہ علم و فیض اور معرفت کے اعلی درجہ پر فائز تھا اس نکتہ کی تائید کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ معاویہاور عمر ابن عبد العزیز میں سے کون افضل ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا: خدا کی قسم رسول کے ساتھ میدان جنگ میں معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا غبار عمر ابن عبد العزیز جیسے سو لوگوں سے بہتر ہے۔ اور و ہ اس طریقہ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم کا دیدار اور آپ کی ہمراہی کا شرف اور انسان پر آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی نظر کا پڑجانا اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ نہ تو کوئی عمل اس کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شرافت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔''(۱۳)
بے شک اس کے درمیان سیاست کا بھی کافی عمل دخل رہا ہے۔ لیکن ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں نے اسی طرز تفکر کے ساتھ ترقی کی اور اس کی بنیاد پر ان کی شخصیت اور ذہنیت پھولی پھلی اور پروان چڑھی یہاں تک کہ گویا مسلمان اخلاقی، روحی، فطری اور دینی لحاظ سے ایک ایسے نظریہ کے محتاج تھے۔ اس کے علاوہ اندرونی طور سے تعارض و تضاد سے دوچار تھا، ایسے مجموعہ میں ساز گاری پیدا کرکے ایک مکمل کلامی نظام کو پیش کرنے پر مجبور ہوگئے تھے۔
اصولاً ہر صاحب ایمان اور معتقد انسان، دینی مسائل سے لیکر دوسرے مسائل تک، جس چیز پر اس کا ایمان و عقیدہ ہو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے معتقدات (عقائد) کو ایک ایسے مجموعہ میں پائے جس میں پورے طریقہ سے ارتباط اور ھما ھنگی پائی جاتی ہواور ہر طرح کے تضاد سے خالی ہو۔ اسے حاصل کرے یہ اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اپنے اعتقادات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے یا اپنے عقائد سے دفاع کرنے کے لئے ایسے اقدام پر مجبور ہے، خود اس کی اپنی داخلی ضرورت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایسی کوشش اور عمل کے بغیر لاجواب رہ جائے گا۔ اپنے عقائد کی بہ نسبت انسان کا قلبی سکون ان کے درمیان ہماہنگی اور سازگاری کا مرہون منت ہے۔ انسان کی فطری اور عملی کوششوں کا اچھا خاصا حصہ چاہے دین سے متعلق ہو یا فکر و علم سے، اپنے عقائد کو ہماہنگ اور منسجم کرنے اور اس میں یک سوئی پیدا کرنے میں صرف ہوتا ہے اور یہ عموماً اندرونی ضرورت کے تقاضا کے تحت ہوتا ہے۔
ایسی کوشش کے چند نمونوں کو جو صحابہ اور صدر اسلام کی شخصیتوں کی طرف پلٹتا ہے، اس نظریہ میں تلاش کیا جاسکتا ہے: ''اس امت میں اور اس کے علاوہ دوسری امتوں میں پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں اور ان کے بعد عمر اور ان کے بعد عثمان پھر ان کے بعد حضرت علیـ ہیں۔'' یہ کلام خود پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی زبان مبارک سے سنا گیا ہے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہئے۔ پھر ان حضرات کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل،طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور سعد بن زید اور عبدالرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ جراح وغیرہ سب کے سب منصب خلافت تک پہنچنے کے لئے منا سب اور شائستہ افراد تھے۔ سب میں منصب خلافت کی صلاحیت پائی جاتی تھی۔ پھر ان حضرات کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر اصحاب پیغمبر ہیں، وہ صدی جس میں حضرت ختمی مرتبت مبعوث ہوئے، پہلے والے مہاجرین جنہوں نے حضور اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، انصا اور وہ حضرات جنہوں نے مسجد الاقصی (یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ) کی طرف نماز ادا کی۔ پھر ان لوگوں کے بعد لوگوں میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کی بزم میں حاضر ہوتے تھے۔ چاہے ایک روز یا ایک ماہ یا ایک سال یا اس سے کچھ کم یا زیادہ حضور کے ہمراہ رہے ہوں۔ ہم ان کی مغفرت کے لئے دست بدعا ہیں اور ان کے فضائل کو نقل کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی نیکی کے علاوہ کسی اور چیز سے یاد نہیں کرتے...۔''(۱۴)
نتیجہ یہ کہ مذکورہ اسباب و عوامل اور دوسرے اسباب سب مل کر سبب بنے کہ اہل سنت کے نزدیک صدر اسلام اصحاب پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم اور خلفائے راشدین دینی اور قدسی (پاکیزہ) قدر و منزلت حاصل کرلیں۔ ان لوگوں (اہل سنت) کے درمیان کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ملتی جو ان تمام مقامات میں شک و تردید کا شکار ہو۔ یہ ایک ایسی اصل اور قاعدہ ہے جس پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس کی روشنی میں اسلام کو درک اور اس کی تفسیر کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان مواقع سے قطع نظر اسلام کے متعلق ان لوگوں کی فہم و ادراک کی کیفیت کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کے کلی مسائل فقہ و تفسیر اور تاریخ سے لے کر کلام، فلسفہ، خدا وند عالم کی معرفت اور شناخت (عرفان) تک اور خاص طور سے اس کے سیاسی اور دینی مسائل، اسلام سے متعلق اہل سنت کے فہم و ادراک کی کیفیت اور شیعوں کے فہم و ادراک کی کیفیت کے درمیان فرق اس آخری مسئلہ میں پایا جاتا ہے۔
اگر بغور دقت کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں شیعہ اور اہل سنت ایک دوسرے کو کم سمجھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ چونکہ اس نقطہ کی طرف توجہ نہیں رکھتے کہ ان کیاعقائد و نظریات دو بنیادوں اور دو جدا جدا، فکری وفلسفی کلامی اور تاریخی نظام پر استوار ہیں اس کا اشارہ نہیں کیا ہے، جس کے نتیجہ میں بحث و گفتگو اور افہام و تفہیم کے مرحلہ میں مشکلات سے دوچار ہوجاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک فرقہ، دوسرے کے عقائد کو اپنے دینی نظریہ کے معیار پر دیکھتا ہے، لہٰذا اس کو درک کرنے اور سمجھنے سے قاصر رہتا ہے اور اس سے ان کے اصول اور میزان کے خلاف توقع رکھتا ہے۔یہ ایک نظری مشکل نہیں ہے بلکہ ایک محسوس حقیقت ہے۔ اور جب تک شیعہ اور اہل سنت ایک دوسرے کی فکری اور اعتقادی نظام کی خصوصیات اور یہ کہ کون سی ضروریات اور تصورات سے وجود میں آتی ہیں ان کا پتہ نہ لگالیں تب تک وہ افہام و تفہیم، گفتگو اور ایک دوسرے کی کارساز اور مفید مدد پر قادر نہیں ہوسکتے۔ جیسا کہ عرض کرچکے ہیں کہ یہ سخن دینی و سیاسی مسائل میں بدرجہ ہا زیادہ صحیح ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے اسے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔(۱۵)
اب ہم یہ دیکھیں کہ ایسے اعتقاد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور اس کا انجام کیا ہو گا؟ یعنی اس کے روحی اور اعتقادی، معاشرتی اور سیاسی نتائج کیسے ہیں؟ یہاں پر ہم اس کے دو اہم نتائج کو جو ہماری اس گفتگو میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں بیان کررہے ہیں۔
صریح اور واضح فیصلہ کی قدرت کا نہ ہونا
ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک، صدر اسلام خوددینی مقام و منزلت رکھتا ہے، لیکن موضوع بحث یہ ہے کہ یہ دور اختلافات، کشمکش اور مقابلہ آرائیوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ وہ بھی بزرگان اصحاب کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ عشرۂ مبشرہ کے بہت سے افراد با وجودیکہ بلاشک وشبہہ اپنی دینی منزلت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دور اور یہ افراد باوجودیکہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں اور قتل پر کمر بستہ ہوں، دینی لحاظ سے شائستہ اور اعلیٰ منزلوں پر بھی فائز ہوں؟ پس یہاں پر افراد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ معیار اور ضابطہ کا مسئلہ ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ حق یا باطل پر ہونے کا معیار کیا ہے؟ اور بنیادی طورپر حق اور باطل کیا ہے؟ اور انسان کیسے زندگی بسر کرے اور کون سا موقف اختیار کرے کہ جسے راہ حق پر کہا جاسکے؟ اس کے علاوہ خود باطل کی مخالفت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر باطل کے خلاف آواز اٹھانا چاہئے، تو پھر باطل کو پہچاننا چاہئے اور اس کے تشخیص دینے کا معیار و ملاک کیا ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک وہ لوگ کوئی اطمینان بخش جواب حاصل نہیں کرپائے لہٰذا ایسی توجیہات اور تاویلات کا سہارا لیا جن کا ذکر بہت طولانی ہے۔ لیکن حائز اہمیت یہ تھا کہ اس مشکل نے اہل سنت کی روحی اور اعتقادی عمارت پر اپنا اثر چھوڑ دیا۔ اس معنی میں کہ چونکہ ان کے پاس اس مسئلہ اور مشکل کا کوئی حل موجود نہیں تھا (اور ان کے فرضی اصول بنیادی طور پر قابل حل بھی نہیں تھے) لہٰذا انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اسی سے ملتے جلتے نمونوں کو یوں ہی لاینحل باقی چھوڑ دیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ اس مشکل کا آخری راہ حل یہ ہے کہ اس مسئلہ کا کوئی جواب نہیں ہیاور اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوکشش بھی نہیں کرنی چاہئے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس مسئلہ کے حل کے لئے ہر طرح کی کوشش کو ممنوع اور نا جائز قرار دیا ہے۔ اصل یہ تھا کہ اس مسئلہ کے سامنے سکوت اختیار کریں اور اس سلسلہ میں جو فضائل بیان کئے گئے ہیں، اسی پر اکتفا کریں اور حتی ان روایات اور تاریخی دستا ویز کی صحت و عدم صحت کی تحقیق اور چھان بین بھی نہ کریں۔
لیکن نکتہ یہ تھا کہ اس قضیہ کے سامنے سکوت اختیار کرنا، اسی سے ملتے جلتے دوسرے مسائل کے سامنے خاموش رہنے کا سبب بنا، یہی وہ نقطہ ہے جہاں اس سکوت اور اجمال کی وجہ سے اہل سنت کی روحی اور عقیدتی عمارت پر پڑنے والے اثرات کو دیکھا جاسکتا ہے جو ان کی دینی، سیاسی، معاشرتی اور تاریخی تبدیلی کو شکل دینے میں سخت موثر ثابت ہوا۔
مثال کے طور پر اس کلام کی طرف جو ابن حنبل کے قول سے نقل ہوا ہے، توجہ کریں:
''ابن حنبل سارے صحابہ پیغمبر کی بزرگی کا قائل ا ور ان سب کا احترام کرتا تھا اور ان لوگوں کے بارے میں سوائے خیر کے اپنی زبان تک نہیں کھولتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علیـ کی خلافت، حقانیت اور مشروعیت کے قبول کرنے کے با وجود معاویہ کے خلاف ایک حرف بھی تنقید نہیں کی۔ چنانچہ صفین اور جمل کی جنگوں کے بارے میں جب کہ ان میں بہت سارے اصحاب مار دئیے گئے تھے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور یہ سب اس لئے تھا اور اس واسطہ کچھ نہیں کہا تا کہ صحابہ کی برائی میں ان کی زبان نہ کھلنے پائے...
ابن حنبل کی نگاہ میں سارے صحابہ برابر تھے اور ان کے بارے میں سوائے نیکی اور تعریفوں کے اور کچھ ان سے نقل نہیں ہوا ہے۔ ابن حنبل کا کہنا تھا: ''معاویہ، عمروابن عاص اور ابوموسی اشعری ان لوگوں میں سے ہیں جن کی وصف میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ظاہر ہیں۔''(۱۶)
چنانچہ احمد بن حنبل کی کتاب السنة، کی شرح کرنے والوں میں سے ایک شخص نے اپنی شرح میں اس طرح سے بیان کیا ہے: ''جب کبھی کسی کو صحابہ کے اعمال پر تنقید اور ان پر طنز کرتے ہوئے دیکھو تو جان لو کہ وہ شخص خواہش نفس میں مبتلا ہے، اس پر پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کا یہ فرمان دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا: جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو ٹھہرجائو۔ کیونکہ حضور اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم جانتے تھے کہ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد صحابہ لغزشوں میں پڑیں گے اور ان سے غلطیاں ہوں گی۔ لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں نیکی کے علاوہ کچھ نہ فرمایا اور فرمایا: میرے صحابہ کی قدر کرو اور ان کے حق میں سوائے نیکی کے اپنی زبان نہ کھولو اور ان کے اشتباہات اور غلطیوں سے متعلق روایات اور اخبار کو ہرگز نقل نہ کرو... اور جان لو اور وہ شخص جو اصحاب پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اعمال و کردار پر چوں چرا کرے، در حقیقت اس نے خود پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم پر انگلی اٹھائی اور ان کو قبر میں تکلیف پہنچائی ہے۔(۱۷)
آٹھوی صدی کے مشہور و معروف فقیہ اور متکلم ابن جَزّی اسی مفہوم کو اس سے زیادہ صراحت اور تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں: ''لیکن علی ـ اور معاویہ کے ما بین اختلاف کو نہ چھیڑو اور بہتر ہے کہ ان حضرات کے متعلق نیکی سے یاد کرو اور جو کچھ بھی پیش آیا اس کی اچھے اور مثبت پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر و توضیح کرو کیونکہ ایسا کرنا اجتہاد کے موارد میں سے ایک مورد ہے۔لیکن حضرت علیـ اور آپ کے چاہنے والے حق پر تھے کیونکہ ا ن لوگوں نے اجتہاد کیا اور ان کا یہ اجتہاد حقیقت اور واقعیت پر تھا، لہٰذا وہ لوگ خدا کے نزدیک ماجور ہیں۔ لیکن معاویہ اور اس کے چاہنے والوں نے بھی اجتہاد کیا اور ان کا یہ اجتہاد خطا واقع ہو گیا اور حقیقت تک نہ پہنچ سکا لہٰذا وہ لوگ خدا کے نزدیک معذور ہیں۔ ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہم ان دونوں (علیـ اور معاویہ) اور بقیہ دوسرے بزرگ اصحاب کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کو دوست رکھیں۔''(۱۸) ایسے بیشمار نمونے پیش کئے جاسکتے ہیں۔
بہر حال صدر اسلام کے حوادث اور واقعات کے متعلق ان کی فہم نے ان کو اس نتیجہ تک پہنچادیا، بلکہ اس عقیدہ تک کھینچ لایا کہ دو مسلمانوں میں آپس میں اختلاف و تنازع ممکن نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں، با وجودیکہ ایک شخص مطلق حق پر اور دوسرا شخص مطلق باطل پر ہو۔ خصوصاً اس نکتہ پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ بہرحال دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تنازع کی صورت میں، جبکہ وہ دونوں مسلمان ہوں یعنی وہ تمام شرائط اور ضوابط پائے جاتے ہوں جو ایک انسان کو مسلمان بناتے ہیں، ایسی صورت میں یقیناً ان دونوں میں سے کوئی بھی باطل پر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، اہم یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان باطل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ گویا وہ ضمنی طور پر اس حقیقت کا اقرار کرچکے تھے کہ اس صورت میں طرفین (دونوں مسلمانوں) کی حقانیت نسبی طور پرہے نہ کہ مطلق۔ کیونکہ جب باطل ہی نہ تھا تو لامحالہ دونوں میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ حق کا حامل ہوگا۔
واقعۂ عاشورا کے بالمقابل سکوت اختیار کرنا
اہل سنت کے نزدیک اس ذہنیت اور اس طرز کی جڑیں اتنی مضبوط اور گہری ہیں کہ ان میں سے بہت سے افراد واقعۂ عاشورا کے بارے میں بھی خاموش ہیں اور سکوت کی لگام کسے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ خاص وجوہات اور دلائل کے سبب ہے کہ وہ ان دلیلوں کو معتبر جانتے ہیں یعنی پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی ان حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں جو امام حسینـ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں اور اسی طرح دیگر احادیث بھی جو صریح یا اجمالی طور پر واقعۂ عاشورا کی طرف اشارہ کررہی ہیں، امام حسینـ کو بر حق اور یزید کو باطل محض جانتے ہیں۔ یعنی ان احادیث کو نظر میں رکھے بغیر گویا حتی ان موارد میں بھی فیصلہ نہیں کرسکتے اور یہ کہنے کی جرأت نہیں رکھتے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ انہیں دلیلوں کی بنا پر جو بیان ہوچکی ہیں ا لبتہ دوسری فقہی اور کلامی دلیلیں بھی اس باب میں موجود ہیں۔
زیادہ واضح انداز میں کہہ دیا جائے کہ اگر ہم ان ساری حدیثوں سے جو بالواسطہ یا بلاواسطہ واقعہ عاشورا اور اہل بیت اور پنجتن پاک(ع) کی شان اور مقام و منزلت اور بنی امیہ اور یزید جیسے فرد کی مذمت پر دلالت کرتی ہیں نظر انداز کردیں تو اہل سنت کی مذہبی عمارت اپنی کلیت میں اور دینی اور اعتقادی رجحان شناسی کا ماحصل کچھ اس طرح سے ہے عاشورا جیسے صریح اور واضح واقعہ اور حادثہ پر خاموش رہے گا۔ چنانچہ خاموشی اختیار بھی کی ہے۔ خود اپنے ہی نزدیک معتبر اور قابل قبول دلیلوں اور معیار کی بنیاد پر نہ کہہ سکے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، وہ لوگ ایسے کیوں تھے؟
تعجب تو یہاں پر ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے زعم ناقص میں اپنے خود ساختہ دینی اور فقہی معیار کی بنا پر امام حسینـ کو غلط ثابت کردیا اور یزید کو بری کرتے ہوئے اس کی طرفداری بھی کی ہے۔ ابوبکر بن عربی اور اس کے ہم خیال، چاہے گذشتہ دور میں ہوں یا دور حاضر میں، اسی نظریہ کے حامل ہیں۔ وہ کھلم کھلا یزید کی تعریف کرتا ہے اور یزید کے خلاف امام حسینـ کے قیام کو اشتباہ اور غلط گر دانتاہے۔ وہ اپنے بعض نظریات کے اظہار میں یوں کہتا ہے: ''انھوں نے (امام حسینـ) اپنے زمانہ کے عالم ترین انسان یعنی عبداللہ بن عباس، کی نصیحت کو قبول نہیں کیا اور شیخ صحابہ عبداللہ بن عمر کی رائے سے سرپیچی کی، انہوں نے آغاز کو انجام میں اور صداقت اور سچائی کو ٹیڑھے راستے یعنی انحراف میں تلاش کیا۔ جب کہ خلافت، فوج کی کثرت اور بزرگان قوم کی ہمراہی کے باوجود ان کے بھائی کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ خلافت کوفہ کے بدمعاشوں اور شریروں کے ذریعہ ان تک پلٹ آتی۔ جب کہ بزرگ اصحاب نے ان کو اس کام اور اس فکر سے منع کیا تھا۔ حسین بن علی کے لئے مناسب تھا کہ وہ اپنے جدکے اس قول پر عمل کرتے کہ آپ نے فرمایا: ''بہت جلد فتنہ و فساد اور برائی اپنا سر اٹھالے گی پس جو شخص بھی اس متحد امت کے درمیان تفرقہ اور جدائی ڈالے اس کو شمشیر کے حوالے کر دو چاہے کوئی بھی ہو۔'' لہٰذا حسین بن علی کو دریادلی اور سعۂ صدر سے کام لیتے ہوئے یزید کی بیعت کرلینا چاہئے تھا۔ یہ یزید بن معاویہ اور اس کے والی عبیداللہ بن زیاد نے امام حسینـ کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو ان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے ان کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور پھر اس کے بعد آپ کو کوفہ کے شریروں اور بدمعاشوں کے حوالے کردیا۔''(۱۹)
یہاں پر اہم یہ نہیں ہے کہ ابن عربی نے کس ہدف اور مقصد کے تحت اس دینی موقف کی تنقید کی ہے، وہ بھی مخلصانہ اور دینی موقف، اختیار کیا۔ بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی گفتگو نتیجةً آرائے اہل سنت کے فقہی اور کلامی قابل قبول اصول و ضوابط سے بھرپور سازگاری رکھتی ہے۔ در حقیقت یہ امام حسینـ کی شان و منزلت اور یزید جیسے شخص کا فسق و فجور تھا کہ جو اہل سنت کے عام علما کی طرف سے اس طرح واضح وصریح اظہار رائے کی راہ میں مانع تھا۔ یا یوں کہہ دیا جائے کہ ثانوی ضروریات کی بناپر عام علما اہل سنت ابن عربی سے موافق نہ ہوسکے وگرنہ ان کے درمیان نظریاتی اختلافات نے عدم موافقت میں اتنا اثر نہیں ڈالا۔ اگر اس مسئلہ میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے تو وہ اصولی اور بنیادی نہیں ہے بلکہ ثانوی اور بعض اوقات اخلافی ہے۔(۲۰)
درست اسی سبب کے تحت علماے اہل سنت کے بہت سارے بزرگ علما نے توقف اور خاموشی اختیار کرلی۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ توقف اور خاموشی کس وجہ سے تھی۔ اس کا سبب کیا تھا؟ کیوں بہت سے علما ئے اہل سنت یزید کے خلاف حکم صادر کرتے وقت پیچھے ہٹ گئے اور توقف کیا اور ان میں کے بعض تو اس کی مخالفت کو قانونی طورپر جائز ہی نہیں جانا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض توقف کرنے والے اور خاموشی اختیار کرنے والے اور منع کرنے والے ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اپنے دین کو اپنی دنیا کے ہاتھوں بیچ ڈالیں اور ظالم و جائر حکمرانوں کی خوشامد کے لئے ایسے نظریات کا اظہار کریں۔ بنیادی طورپر ان میں سے بعض لوگوں نے اس وقت ایسے نظریات کا اظہار کیا جب وہ عمومی افکار اور موجودہ حاکمیت کے خلاف تھا۔ لیکن اپنے نظریہ پر ایک ذمہ داری اور شرعی فریضہ کے عنوان سے اصرار کیا۔ وہ اپنے کلامی اور فقہی معیار اور ثانوی ضرورتوں کو جو کہ ان احادیث کے معتبر جاننے سے وجود میں آئی تھیں جو امام حسینـ کی شان و منزلت اور یزید کی مذمت میں پائی جاتی ہیں ان (معیار) کے درمیان تعارض کے سبب ہیں حتی کہ وہ احادیث جس میں صریحی یا اشارہ کے طورپر واقعۂ عاشورا اور امام حسینـ کی مظلومانہ شہادت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، سکوت اختیار کرنے پر مجبور ہوگئے۔ اس پس و پیش، کشمکش اور گیر ودار میں عافیت احتیاط میں ہی تھی اور احتیاط توقف اور سکوت کی نصیحت اور سفارش کررہی تھی۔(۲۱)
بہرحال بہت ہی محتاط انداز میں جواب کو اسی دینی رجحانات کی شناخت کے اندر تلاش کرنا چاہئے جو صدر اسلام کی تاریخ اورا س کی شخصیتوں کو مقدس جاننے کا بلا فصل نتیجہ ہے۔
اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ احتیاط کے مصادیق، کسی حدتک احتیاط کے مفہوم کے متعلق شیعوں اور اہل سنت کے درمیان بعض شباہتوں کے باوجود سخت اختلاف اور فرق پایا جاتا ہے چاہے وہ مفہوم احتیاط، اعتقادی ہو جو اصول اعتقادات سے متعلق ہے یا فقہی احتیاط ہو جو احکام عملیہ سے متعلق ہے آیندہ اس نکتہ کی وضاحت کی جائے گی۔
جب اصل مسلّم یہ ہوگئی کہ وہ ساری مقدس شخصیتں اور یہاں تک کہ دینی اور معنوی اہمیت کے لحاظ سے مساوی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے جنگ و جدال اور برسرپیکار بھی رہے ہیں، لہٰذا اس اصل کا معلوم ہونا انسان کو اس کے بعد کے فیصلوں میں احتیاط کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ ایک ایسی مفلوج اوربے حس کردینے والی احتیاط کی طرف جو واقعۂ عاشورا جیسے حادثہ کے متعلق، جس میں دونوں فریق کاملاً معلوم اور جانے پہچانے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہوجائے، یہاں پر بھی توقف وسکوت سے کام لے اور طرفین کو بری کردے یہاں تک کہ ایک شرعی ذمہ داری اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے ہی دوسروں کے لئے بھی جستجو، تلاش اور فیصلہ کرنے سے مانع ہوجائے یعنی دوسرے افراد کو بھی فیصلہ لینے سے بھی روک دے۔
مثلاً محمود صبحی اہل سنت کے درمیان جو اس کی نظر میں ایک درمیانی مبہم اور غیر واضح راہ حل کو چاہتے تھے، شہادت امام حسینـ کے اعتقادی اور کلامی نتائج کے بارے میں اس طرح بیان کررہے ہیں: ''شہادت امام حسینـ کے مقابلہ میں اہل سنت کا ردعمل بہت دشوار اور دردناک تھا۔ کیونکہ اہل سنت کے نزدیک مطلوب درمیانی راہ کو حاصل کرنے کے لئے، اس کی بنیاد پر جو اہل سنت کی خواست تھی اس طرح کی ہر کوشش کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی بناپر امامـ کے قیام اور خلفا سے آپ کے دشمنوں کی دوستی کے مابین صائب رائے قائم کی جاسکے، یہ عاشورا کا واقعہ تھا جس نے ایسی کوشش کو ناکام بنادیا۔'' اس وقت وہ (محمود صبحی) اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے شواہد کو ذکر کرتے ہیں۔(۲۲)
ایسے تاریخی طرزفکر کی داستان پوری تاریخ اسلام میں موجود ہے اور ہمیشہ یہ داستان تھی اور دور حاضر میں بھی چھڑی ہوئی ہے اور اسی طرح ہمیشہ چھڑی رہے گی۔
پورے مذہب اہل سنت میں کوئی بزرگ عالم اور دانشور ایسا نہیں گذرا جس نے اس بارے میں کچھ نہ کچھ بیان نہ کیا ہو۔ ابن ابی الحدید اپنی کتاب کے مختلف حصوں میں جو در حقیقت ایک بہت بڑی دائرة المعارف ہے، صدر اسلام سے متعلق، ساری بحثوں کو مختلف عناوین کے تحت تمام ایسے نظریات کو نقل کرتا ہے اور آخری جلد کا اہم حصہ انھیں بحثوں پر مشتمل ہے۔ اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم صحابہ اور اس کے بعد یزید کے سلسلہ میں غزالی کے نظریے کو نقل کریں۔ ایسے شخص کا انتخاب اس کی شخصیت کے ہمہ گیر ہونے، اس کے مرتبہ علمی، عام مقبولیت، نیز زہد و تقوی اور اس کی دنیا سے کنارہ کشی ہے تاکہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ ایسی بات جہل اور لاعلمی کی وجہ سے یا حکام وقت کی خوشامد اور ان خدمت کی خاطر کہی ہے یا یہ کہ عام لوگوں کے نزدیک یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔(۲۳)
وہ اس سلسلہ میں کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہئے، اس کے بیان میں یوں کہتا ہے: ''اس راہ میں نہ افراط کی حدتک چلے جاؤ اور نہ تفریط سے کام لوبلکہ درمیانی راہ کو انتخاب کرو (اسلک طریق الاقتصاد فی الاعتقاد) اور جان لو کہ ایسی صورت میں یا تو یہ ہوگا کہ تم کسی مسلمان سے بد گمان ہوجاؤگے اور اس پر لعن و طعن کرو گے اور تمہاری یہ بد گمانی اور طعن اگر واقع کے مطابق نہ ہوسکا تو تم جھوٹے بن جاؤ گے۔ اور یا یہ ہوگا کہ کسی مسلمان کے سلسلے میں تم حسن ظن رکھو اور اپنی زبان کو اس کی برائی میں نہ کھولو اور تمہارا یہ حسن ظن اور برائی نہ کرنا واقع کے مطابق نہ ہوا اور خطا پر ہو۔ اس درمیان ایسی خطا جو کسی مسلمان کے اوپر حسن ظن کے ہمراہ ہو اس کی ملامت کی بہ نسبت نیکی سے نزدیک تر ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی ابلیس یا ابوجہل، یا ابولہب یا کسی دوسرے شریر انسان کے اوپر لعنت کرنے سے باز رہے تو ایسے انسان کا سکوت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر اتفاقاً کسی بے گناہ انسان کے اوپر لعن و طعن کرے تو گویا اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔''(۲۴)
امام الحرمین جوینی نے بھی ایسے ہی مطالب کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کو ابن ابی الحدید اپنی کتاب کی بیسویں جلد میں نقل کرتا ہے۔
غزالی اپنی مفصل اور معتبر ترین کتاب احیاء العلوم، میں یزید کے اوپر لعنت کے جائز ہونے یا نہ ہونے کے باب میں تفصیلی بحث کرتا ہے۔ جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے: فقہی اور شرعی لحاظ سے یزید اور اس جیسے کسی بھی شخص کے اوپر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ جب تک یہ بات ثابت اور محقق نہ ہوجائے کہ یزید نے امام حسینـ کے قتل کا حکم دیا اور اس پر راضی تھا اور جب تک اس کا اسلام مسلّم اور ثابت رہے اس پر لعنت جائز نہیں ہے۔ کیونکہ احادیث نبوی اور دوسری صحیح دلیلوں کی رو سے مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام ہے۔(۲۵)
اور یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ انھیں نکات کا نتیجہ ہے جو پہلے بیان ہوچکے ہیں۔ اعتقادی اور روحی عمارت کا منطقی اور فطری نتیجہ ہے جس کی بنیاد پر ابتدا ہی سے یہ نظریہ وجود میں آکر پروان چڑھا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت وجودی کیا ہے۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو پہچاننے کے لئے ہم کس فکر اور ذہنیت کا سہارا لیں۔ ایسی فکر اور ذہنیت، واقعۂ عاشورا کو بھی اپنے میزان اور معیار کے لحاظ سے دیکھتا اور پرکھتی ہے اور یہ ایک فطری تقاضا ہے۔
لطف کی بات تو یہاں پر ہے کہ ایسا نظریہ بعض علما ئے اہل سنت کے نزدیک اتنا صحیح، مقبول اور قطعی و یقینی ہے کہ واقعۂ عاشورا اور یزید کی مذمت سے متعلق احادیث کی صحت کو شک و تردید کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ان علما میں سے بعض بادشاہوں کے مزدور اور زرخریدہ غلام تھیاور انہیں میں سے بعض وعاظ السلاطین (سرکاری عالم) تھے (اور آج بھی ہیں اور پوری محنت و کوشش میں لگے رہتے ہیں) لیکن بہر حال ان لوگوں کے درمیان ایسے افراد بھی تھے جو واقعاً اسی طرح سوچتے اور اسی پر عقیدہ رکھتے تھے۔(۲۶)
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں مکتبوں کے ماننے والوں کی اعتقادی اور ذہنی ساخت و ساز (بناوٹ) کے درمیان کم از کم اس حصہ میں، کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ ایک مکتب میں ذہنی ساخت و ساز کچھ اس طرح ہے کہ دو مسلمان فرد یا مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف شمشیر بکف ہیں، متضاد فیصلہ کی قدرت کو کھو بیٹھتا ہے اور دوسرے مکتب فکر میں فکری اور روحی ساخت و ساز اس طرح ہے کہ جو صرف تضاد ہی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی ایک فریق کو حق مطلق جاننے اور دوسرے فریق کو باطل مطلق سمجھے۔ یقیناً یہ فرق بہت ہی باریک اور مرکزی حیثیت کا حامل ہے معاشرتی اور سیاسی تحولات و تغیر کے لئے دو معاشرتی اور ثقافتی میدانوں کو وجود عطا کرے گا۔ ناگوار حوادث سے دوچار ہونے کی صورت میں ایک گروہ کو حسینی اور مخالف گروہ کو یزیدی جاننے والے معاشرہ میں انقلابی جوش و جذبہ یقیناً اس معاشرہ کے انقلابی جوش و جذبہ سے بہت فرق رکھتا ہے ایک ایسا معاشرہ جس کی نظر میں تاریخ اور کم از کم تاریخ اسلام نہ تو خالص یزیدی ہے اور نہ ہی خالص حسینی۔ (اگر بالفرض قبول کرلے کہ یزید باطل محض اور امام حسینـ حق مطلق تھے) یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں کون سا نظریہ اچھا ہے اور کون سا برا بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی خصوصیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ شیعوں اور اہل سنت کے درمیان مختلف فرق میں سے ایک اہم فرق یہ ہے کہ دونوں کے دینی رجحان، ذہنیتوں اور طرز فکر میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشکلات و مسائل کو بھی دوطرح سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے کو بہت مشکل سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ ایک ہی مسئلہ کے متعلق دو مختلف نظر ئے رکھتے ہیں۔ یہ دو نظریے جو بالکل دو مختلف مقدمات پر مبنی ہیں، اگر اتفاقاً کوئی سنی ان موارد میں ایک شیعہ کے فہم و ادراک کی کیفیت کو سمجھ لے اور تاریخی و سیاسی حوادث کو شیعہ ہی کی طرح سمجھ کر اس کی تحلیل کرے تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ اس نے شیعہ کی ذہنیت اور طرز تفکر کو قبول کرلیا ہے نہ یہ کہ اپنی ذہنیت اور اپنے مکتب میں اپنے مخصوص نظریے کے ذریعہ اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہوگئی ہے کہ وہ ایک شیعہ کی طرح مسائل کو دیکھتا اور پرکھتا ہے۔ بعینہ یہی بات شیعوں کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ وہ لوگ (شیعہ حضرات) ایک سنی کے مانند تاریخی اور معاشرتی حوادث کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی ذہنی اور اعتقادی ساخت و ساز (بناوٹ) دو طرح کی ہے اور یہ فطری بات ہے کہ وہ مسائل اور مشکلات کو یکساں نہ دیکھ سکیں اس کی یکساں چھان بین کرکے قدر و قیمت کا اندازہ لگاسکیں۔(۲۷)
نئے تجربہ کی روشنی میں نیا ادراک
اگرچہ آج کل اہل سنت کے درمیان کچھ ایسے افراد خصوصاً ان میں کچھ جوان پائے جاتے ہیں جو شیعوں کے نزدیک بلکہ شیعوں کی طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی نفسیاتی، فکری اور اعتقادی ساخت و ساز (بناوٹ) ان کے مذہب کی تاریخی اور دینی میراث اور ان کے عقائد کے علاوہ دوسرے اسباب و عوامل کے زیر اثر اور انھیں سے متاثر ہیں۔ بعض اسلامی ممالک میں اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی تحولات کے اندر متضاد مسائل و حوادث کو دریافت کرنے کی صلاحیت کو پیدا کردیا ہے۔ تحولات و تغیرات میں جتنی زیادہ تیزی اورگہرائی پائی جا رہی تھی اور معاشرہ جس قدرروایتی اور پیچیدہ تھا یہ خصوصیت بھی اتنی ہی زیادہ قوی، گہری اور وسیع پیمانہ پر رہی ہے۔ اسی طرح جس ملک میں بھی مخفی انقلابی صلا حیتیں زیادہ رہی ہیں، یہ حالت بھی اتنی ہی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے۔ کیونکہ قاعدتاً انقلابی ہونے یا انقلابی فکر رکھنے کا لازمہ یہ ہے، خاص طور سے جوانوں کے درمیان یہ ہے کہ انسان تاریخ اور موجودہ حالات کے بارے میں متضاد معلومات رکھتا ہو اور اس لحاظ سے کہ تیسری دنیا اور دنیائے اسلام کی معاشرتی، سیاسی اور فکری تحولات اورتحریکیں آخری دو تین دہائیوں میں ایسے نظریات اور رجحانات کی کافی مدد کی ہے، لہٰذا ایسی طرزفکر اور ایسے حالات بھی فراہم ہوگئے ہیں۔ فی الحال اس نکتہ کی وضاحت سے صرف نظر کرتے ہیں کہ انقلابی ہونے کا لازمہ یہ کیوں ہے ، مسائل کو متضاد طریقہ سے دریافت کرنا ہو سکتا ہے، البتہ یہ نکتہ عام لوگوں کے لحاظ سے پرکھا گیا ہے اور یہ ان افراد کے لئے نہیں ہے جو دانشور یا صاحبان فکر و نظر ہیں اور ان کی معلومات اور تجربات کی وسعت کے تحت ہے اور وہ لوگ انقلابی رجحان بھی رکھتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ متضاد مسائل کے حصول کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ بحث نظری لحاظ سے بھی چھان بین کے قابل ہے اور تاریخی و معاشرتی پہلو سے بھی قابل بحث ہے۔ مثلاً گذشتہ دہائیوں کے درمیان مارکسیزم (مارکس کے نظریہ کے تحت چلنے والا نظام) کے ساتھ اہل سنت اور شیعوں کے برتاؤ کی نوعیت کیا تھی جس میں مارکس کے نظریہ کے تحت چلنے والے نظام نے اصل تضاد کو اپنے فلسفہ کا معیار قرار دیا تھا وہ کیسے تھا؟ اور اس میں کیا فرق پایا جاتا تھا اور یہ اختلافات، کن اسباب کے تحت وجود میں آئے ہیں۔ اور آخری زمانہ کے تحولات کی تاثیر و کیفیت کی چھان بین، شیعہ اور سنی مذہبی جوانوں کے درمیان جذبہ اور حوصلہ افزائی کے لئے وجود میں لایا گیا تھا۔(۲۸)
آخری موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ سنجیدہ ترین کتاب اور موجودہ صدی میں سنیوں کی انقلابی نسل کے تفکر کے لئے اہم ترین اور مؤثر ترین راہنما، کتاب معالم فی الطریق، سے کچھ مطالب کو نقل کریں۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ موجودہ صدی میں ان لوگوں (سنیوں) اور شیعوں خصوصاً انقلابی شیعوں کے نظریات اس لحاظ سے کہ حوادث اور واقعات سے متعلق متضاد فکر کو درک کرنے میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ اس معنی میں کہ اسلام کی نقاب اور ظواہر دین کی حفاظت ایسے نقاب پوشوں اور دین کا تظاہر کرنے والوں کے غیر قانونی اور شرعی ہونے کے سلسلے میں قاطع اور صریح فیصلہ کرنے میں مانع نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ اس نقطہ تک مختلف مواضع کے ذریعہ پہنچے ہیں جو شیعوں کے اس نقطہ سے فرق رکھتا ہے چاہے گذشتہ دور ہو یا دور حاضر اُس کے ذریعہ اِس مطلب تک پہنچے ہیں۔ شیعوں کی نگاہ میں وہ ائمہ معصومین(ع) کی سنت کے وارث ہیں یہ مسئلہ بہت ہی سامنے کی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو معصومین(ع) کی زندگی میں قاعدتاً ابتدائی مقاصد میں سے ایک ہدف یہ تھا کہ مختلف طریقوں سے دین کی ظاہری نقاب اوڑھنے والوں، دین فروش یا جاہل اور قدرت طلب لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹادیں۔ لیکن جو کچھ کہا گیا ہے اس کی روشنی میں، اہل سنت ایسا نہیں کرسکتے تھے۔ کیونکہ ان کے اعتقادات، افکار اور ان کی ذہنیت کچھ اس طرح پروان چڑھی تھی کہ وہ لوگ ایسا عمل انجام نہیں دے سکتے تھے اور نہ ہی اس کے بارے (اسلام میں رونما ہونے والے حوادث کے بارے) میں فیصلہ کرسکتے تھے۔
لہٰذا آخری دہائیوں میں معاشرتی ، سیاسی اور فکری و دینی فشار نے اہل سنت کے متفکروں کو چارہ جوئی کے لئے آمادہ کردیا اور مذہبی اور انقلابی جوانوں کو بھی ان کی باتوں پر کان دھرنے والے اور طرفداروں بلکہ ان کے مریدوں اور پیروکاروں میں تبدیل کردیا، وہ لوگ اس بات پر مجبور ہوگئے کہ اس مشکل کو دوسری جگہ سے حل کریں اور چاہا کہ اپنے مخالف نظریہ رکھنے والے اسلاف و معاصرین کے اعتقادات و افکار اور ذہنیت سے بے خبر اور بے توجہی کا اظہار کریں اگرچہ اس نے خود ایک دوسری مشکل کھڑی کردی، لیکن بہرحال ایک نیا راستہ کھول ہی دیا۔
مندرجہ ذیل جملوں میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تحلیل وتجزیہ کی روش، چھان بین کی کیفیت، اسلام کا مفہوم، مورد نظر مقاصد اور آخرکار اس پر حاکم روح کس حدتک پوری تاریخ اہل سنت کی فقہی، کلامی اور ان کے دینی تجربہ کی میراث میں کتنا فرق ہے۔
سید قطب کی راہ گشائی
''آج ہم ایک ایسی جاہلیت کی زندگی گذار رہے ہیں جو ظہور اسلام کے دور کی جاہلیت کے مشابہ ہے بلکہ اس (دور جاہلیت) سے بھی زیادہ تاریک ہے۔ ہمارے اطراف میں جو کچھ بھی ہے، وہ زمانۂ جہالت والی ہے... لوگوں کے تصورات اور ان کے عقائد، ان کی رسم ورواج اور ان کی عادتیں، ان کی ثقافت کا سر چشمہ، ان کے ہنر و ادبیات، ان کے قوانین و ضوابط۔ یہاں تک کہ بہت سارے وہ امور جن کو ہم اسلام کی ثقافت، اسلامی مآخذ اور اسلامی افکار اور فلسفہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں وہ سب جاہلیت کی دین ہیں... اور یہ سب کے سب اسی جہالت کا ماحصل ہیں!۔''
''لہٰذا مجبوراً ہم کو اس جاہلیت کے معاشرہ کے تصورات اور جاہلیت کی رسم ورواج اور جاہلیت کے زمانہ کی رہبری کے دباؤ سے رہائی حاصل کرلینا چاہئے... اور خصوصاً ہم کو اپنے اندر... ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم اس جاہلیت والے معاشرہ کی واقعیت کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے بیٹھ جائیں اور اس کی دوستی کو قبول کرلیں۔ کیونکہ وہ اپنی اس صفت، صفت جاہلیت کے ساتھ قابل گفتگو ہی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں تاکہ اس کی بنیاد پر پورے معاشرہ کو تبدیل کریں۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری، اس معاشرہ کی حقیقت کو بدلنا دین ہے۔ ہماری ذمہ داری اس جاہلیت کی واقعیت و حقیقت کی بنیاد کو تبدیل کر دینا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بنیادی طور سے اسلامی راہ و روش کے مقابلہ میں کھڑی ہوگئی ہے اور زور و زبر دستی کے ذریعہ اس بات سے مانع ہے کہ ہم خدا وند عالم کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور مرضی خدا کو معیار اور میزان قرار دیں۔''(۳۰)
''اسلام دوقسم سے زیادہ معاشرہ کو نہیں پہچانتا۔ ایک جاہلیت کا معاشرہ اور دوسرا اسلامی معاشرہ۔ اسلامی سماج اور معاشرہ ایک ایسا سماج ہے جو اپنے عقیدہ اور عبادت کے تمام پہلوؤں میں شریعت و نظام، سلوک و اخلاق کو وجود بخشتاہے۔ جاہلیت کا سماج اور معاشرہ ایک ایسا سماج ہے جو اسلام پر عمل نہیں کرتا۔ نہ تو اس کے اعتقادات اور تصورات ہی اسلامی ہیں اور نہ ہی اس کے قواعدو ضوابط اور مقدسات، نہ ہی اس کا نظام اور اس کے قوانین ہی اسلامی ہیں۔ اور نہ ہی اس کے اخلاق اور کردار ہی اسلامی ہیں۔ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ نہیں ہے جو ایسے افراد سے مرکب ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت ان کا قانون اور آئین نہیں ہے، چاہے جتنی ہی نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہوں اور حج کے لئے جاتے ہوں۔ اسلامی سماج ایسا سماج نہیں ہے جو خدا اور رسول کے مقرر اور بیان کردہ فرمان کے علاوہ اپنی طرف سے احکام ایجاد کرلے اور اس کو مترقی اسلام (اسلام متطور) کا نام دے دے۔''
جاہل معاشرہ ممکن ہے کہ مختلف قسم کی شکلیں اختیار کرلے ۔ ممکن ہے ایسا سماج ہو جو خدا کا انکار کرے اور تاریخ کی ڈیالکٹکی اور مادی تفسیر کرے اور اس چیز کو ''علمی سوشالیزم کا نام دے کر معاشرتی نظام کے عنوان سے وجود عطا کرے۔ اسی طرح ممکن ہے ایک ایسا معاشرہ ہو جو خدا کا انکار تو نہ کرے لیکن خدا کو صرف آسمانوں سے مخصوص کردے کہ خداوندعالم کو اس کی زمین سے محروم کردیتا ہو۔ نہ اس کے قوانین کے آگے سرتسلیم خم کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ثابت مقدسات ہی کو مانتا ہے۔ لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ صومعہ، کلیسا اور مساجد میں خدا وند عالم کی عبادت کریں، لیکن ان لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی مادی زندگی میں دینی قوانین کی حاکمیت کو طلب کریں اور اس طریقہ سے خدا کی الوہیت کا انکار کرتا ہے اور یا اس کو ایسے ہی معطل چھوڑ دیتا ہے۔ جب کہ قرآن مجید اس بارے میں صراحت سے بیان کرتا ہے: ''صرف وہ ہے جو آسمان میں اور زمین میں معبود ہے۔'' لہٰذا دین خدا میں ایسا کوئی معاشرہ نہیں ہے کیونکہ خداوندعالم خود فرماتا ہے: ''اس نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی پرستش نہ کرو۔'' یہ ہے محکم، قیم اور استوار دین۔'' ایسا معاشرہ ہی جاہلیت کا معاشرہ ہوگا چاہے جس قدر خداوندعالم کو قبول کرتا رہے...'' صرف اسلامی معاشرہ ہی ترقی یافتہ معاشرہ ہے اور دوسرے سارے جاہلیت والے معاشرہ اپنی مختلف شکلوں میں عقب ماندہ اور پچھڑے ہوئے معاشرے ہیں۔ اس بزرگ حقیقت کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔''(۳۱)
اسلام جاہلیت کے ساتھ مشارکت کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ نہ تو تصور کے اعتبار سے اور نہ ہی ان حالات اور لوازم کے لحاظ سے جو اس تصور کے حامل ہیں.. یا اسلام یا جاہلیت، ان دونوں کے درمیان کوئی درمیانی چیز نہیں پائی جاتی جس کا نصف حصہ اسلام اور دوسرا نصف حصہ جاہلیت ہو اور اس کے باوجود اسلام اس کو قبول کرے اور اس سے راضی ہوجائے... اسلامی زاویہ نگاہ اس بارے میں بالکل واضح اور آشکار ہے کہ حق ایک ہے اور اس میں تعدد اور کثرت کی گنجائش نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ دونوں کسی دوسرے لباس میں نہیں آسکتے اور آپس میں مل جل (مخلوط) بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ حکم یا تو حکم خدا ہے یا جاہلیت کا حکم ہے۔ قانون یا تو قانون خدا ہے یا قانون ہوا و ہوس۔ اس باب میں قرآن کی متواتر آیتیں موجود ہیں: ''ان کے درمیان اس چیز کے ذریعہ جس کو خداوندعالم نے نازل فرمایا ہے فیصلہ کرو اور ہوا و ہوس کی پیروی مت کرو۔ ان لوگوں سے ڈرو کہ تم کو فتنہ میں ڈال دیں گے، جو کچھ خداوندعالم نے تم پر نازل کیا ہے ان میں سے بعض کے ذریعہ...'' یہ ایسے دو امور ہیں جن کا کوئی تیسرا (ثالث) نہیں ہے۔ یا خدا اور رسول کی آواز پر لبیک کہنا یا تو اپنے نفس اور ہوا ہوس کی پیروی کرنا...۔(۳۲)
''زمین پر خدا اور اس کے قوانین کو حاکمیت عطا کرنا، انسان کی حاکمیت اور اس کے قوانین کو نیست و نابود کرنا، غاصبوں سے اقتدار کو چھین کر خداوندعالم کے حوالہ کرنا... یہ اہداف تنہا تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ حاصل نہیں ہوسکتے، اس لئے کہ ظالم اور جبار اور حکومت کے لالچی حکمران اور حاکمیت خدا کے غاصب تبلیغ اور ارشاد کے ذریعہ اقتدار کو حوالہ نہیں کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو انبیائے کرام نہایت ہی آسانی سے دین خدا کو روئے زمین پر استوار اور برقرار کردیتے اور یہ اس چیز کے بالکل برعکس ہے جس کی تاریخ نشان دہی کرتی ہے۔ اس دین کی تاریخ بھی دوسرے گذشتہ ادیان کے مانند ہے۔
روئے زمین پر ''انسان'' کی آزادی کا عمومی اعلان ہر اس قدرت سے جو کہ قدرت الٰہی سے جدا ہے اور یہ کہ الوہیت و ربوبیت صرف پروردگارعالم کی ذات سے مخصوص ہے، یہ ایک نظری، فلسفی اور اثر قبول کرنے والا اعلان نہیں ہے۔ ایک واقعی، محرک اور مہمیز کرنے والا اعلان ہے۔ ایک ایسا اعلان ہے جو روئے زمین پر قانون الٰہی کو وجود بخشنا چاہتا ہے اور عملی طور پر انسانوں کو بعض انسانوں کی بندگی سے آزادی دلاکر خدا کی بندگی میں داخل کردے...۔ لہٰذا قہراً'' بیان'' کے ساتھ ''تحرک'' کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعہ ''واقعیت'' کے ساتھ زندگی کے تمام گوشوں میں مقابلہ کرے۔(۳۳)
مندرجہ بالا جملات سید قطب کی کتاب سے لئے گئے ہیں اگرچہ ان کے طولانی ہونے کے باوجود، اس بحث اور دوسری بحثوں کو زیادہ واضح ہونے کے لئے اہمیت کے پیش نظر اسے ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ موجودہ اسلامی تحریک اور اہل سنت کے نزدیک ان کے اعتقادی، فکری اور سیاسی معیاروں کو اس وقت تک نہیں پہچانا جاسکتا جب تک کہ اس کتاب کی پوری طرح شناخت کرکے اس کو سمجھ نہ لیا جا ئے ۔ قابل توجہ یہ ہے کہ حتیٰ سید قطب کے انقلابی ہم فکروں اور مبارزہ طلب لوگوں کے علاوہ وہ لوگ بھی جن کا سید قطب سے کوئی رابطہ نہیں ہے وہ بھی اس کتاب سے ایک طرح سے متأثر ہیں۔ ان لوگوں نے اس جگہ سے ابتدا کی ہے جہاں سے سید قطب نے آغاز کیا تھا اور کم وبیش اسی روش اور سیاق کو اپنایا جسے سید قطب نے اختیار کیا تھا۔ سید قطب اور ان لوگوں کے درمیان زیادہ فرق مآخذ اور اس کی حجیت قبول کرنے میں ہے نہ یہ کہ کسی اور سبب کے تحت ہے۔
سید قطب کے افکار کی اہمیت
اس بات کا بنیادی سبب نہ تو سید قطب کی عظمت ہے اور نہ ہی ان کی مستحکم اور مخدوش نہ ہونے والی فکر کی عظمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک خلاق فکر کے حامل، مخلص اور اصیل انسان تھے۔ اس مقام پر مسئلہ یہ ہے کہ سید قطب کی شخصیت اور فکر کی مقبولیت سے زیادہ اس نکتہ میں پوشیدہ ہے کہ اب تک ان کے علاوہ کسی نے اسلامی سیاسی انقلابی فکر کو صدر اسلام کے تقدس کی نفی کے بغیر (خلفا ئے راشدین کا دور مراد ہے اس لئے کہ انھوں نے معاویہ، امویوں اور اس کے بعد کے ادوار پر شدت سے تنقید کی ہے بلکہ بعض مواقع پر عثمان کو بھی اپنی تنقیدوں کا نشانہ بنایا ہے) ایک جدید مقام سے پیش کرے۔ انھوں نے ایک ایسے راستہ کی بنیاد رکھی تھی کہ دوسرے لوگ جب تک کوئی کسی نئے راستہ کی بنیاد نہیں پڑتی اس وقت تک اسی کے بنائے ہوئے راستہ پر چلنے پر مجبور ہیں۔(۳۴)
جب سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اس وقت سے آج تک بے شمار افراد اپنے مختلف دینی یا غیر دینی اغراض کی بنیاد پر، اس کتاب کو اپنی تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آج تک یہ کتاب جوانوں کے لئے ایک موثق ترین اور بھروسہ مند
اسلامی ماخذ کے عنوان سے باقی ہے، جس نے ان آخری دہائیوں میں انقلاب کی طرف مائل کرنے کے لئے مسلحانہ کوششوں کو آگے بڑھایا اس کے باوجود جوانوں نے اپنے سوالوں کا جواب بھی اسی میں ڈھونڈھ نکالا۔ جوانوں کا سید قطب مخصوصاً ان کی کتاب کا عظیم استقبال ان کی تاریخ میں اسلامی افکار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس قسم کے افکار کی ضرورت یہ ہے ایک واقعی اور سنجیدہ نیاز رہی ہے۔ جسے جواب کی ضرورت ہے اور ایسی صورت حال میں جب کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اپنی بات نہیں پیش کررہا ہے تو پھر یہ امر فطری اور واقعی ہے کہ وہ لوگوں کی توجہات کا مرکز بن جائے۔
اس کے علاوہ سید قطب یا کوئی دوسرا متفکر جو کسی اور عقیدہ کا ماننے والا ہوتا کیونکر ایسے مستحکم اور مضبوط باندھ میں سوراخ کرنے پر قادر ہوتا اور ایسے مجموعہ کے اصول (بنیادین) بلکہ اس کے اجزا بالو اسطہ یا بلا واسطہ طور پر اپنے مطلوبہ جواب سے متضاد ہوتے ہوئے اس میں اپنے جواب کا ضرورت مند تھا کہ اپنا جواب طلب کرے۔ اگر یہ طے کرلیا جائے کہ وہ باندھ ( Dame ) اپنے اسی استحکام پر باقی رہے اور تاریخی تنقیدوں کو مسمار نہ کرے پھر اس صورت میں سید قطب کی بتائی ہوئی روش سے متمسک ہونے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچتا ہے، یا اسی روش سے مشابہ دوسرے راستے اس کے جواب دہ ہوسکتے ہیں۔
اکثر مسلمان نقادوں نے سید قطب پر اس وجہ سے تنقید کی ہے کہ انھوں (سید قطب) نے مسلمانوں کو جاہلیت کے سماج کا نام دیا ہے اور اسے دارالحرب کے مثل جانا ہے، اسی بات پر تنقید کی ہے۔ لیکن کسی نے بھی اس مطلب کی طرف غور وخوض نہیں کیا ہے کہ انھوں نے کس فکری اور اعتقادی دبائو یا نسل موجود کی کن ضرورتوں کے تحت یہ اس لئے سبقت کی ہے اور کس قول کا پیش خیمہ کیا ہے۔ سید قطب اور اس کے ہم فکروں اور پیروکاروں کی نظر میں اصل ہدف اپنے جواب کی تلاش تھی، البتہ یہ تلاش ابھی بھی باقی ہے، لہٰذا اس اصل کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اس راستہ کے علاوہ کس راستہ کو اپنے جواب کی خاطر اختیار کرتے کہ اپنے مقصود کو حاصل کرلیتے؟ اس کا اصل ہدف یہ تھا کہ وہ اسلامی تحریک میں پیش پیش لوگوں کے لئے دستورالعمل تحریر کرے اور انھیں یہ کہے کہ وہ اپنے کام کی ابتدا کس طرح کریں اور کس طرح پوری زمین پر جاہلیت کے بچھے ہوئے جال سے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہوں۔ ایسے پیش گام لوگ جنھیں اس راہ کی نشانیوں کی ضرورت ہے (معالم فی الطریق) ایسی نشانیاں جن کی مدد سے اپنی ذمہ داری اور اپنے ہدف کو نیز اس سفر کے نقطۂ آغاز کو پہچان سکیں... اور انھیں بخوبی معلوم ہوجائے کہ کس مقام پر لوگوں کے ساتھ رہیں اور کس مقام پر ان لوگوں سے جدا ہو جائیں۔ موجودہ جاہلیت کی خصوصیت سے آشنائی حاصل کریں اور یہ بھی جان لیں کہ اپنے زمانہ کے جاہلیت زدہ لوگوں سے کس زبان میں بات کریں اور کن مسائل میں انھیں اپنا مخاطب قرار دیں ...۔''(۳۵)
بغیر کسی تعصب کے ایک غائرانہ تجزیہ میں یہ کہا جانا چاہئے کہ سید قطب تمام اعتقادی رکاوٹوں اور ان تمام دبائو اور ضرورتوں جن کے تحت وہ زندگی گزار رہے تھیاور فکر کررہے تھے پھر بھی مجموعی طورپر کامیاب رہے۔ ان پر تنقید کرنے والوں نے ان کے موجودہ اعتقادی پابندیوں اور رکاوٹوں کو مد نظر نہیں رکھے تھے یا ان پر پڑنے والے دبائو اور ضرورتوں کو جن سے وہ روبرو تھے اس کو نظر انداز کردیا گیا ہے۔
البتہ اس مقام پر سید قطب کے نظریات کی تحقیق اور چھان بین مراد نہیں ہے بلکہ ہم اس نکتہ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کی فقہ، کلام اور فکری واعتقادی عمارت جن پر قائم ہے شدید سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی حوادث کے مقابلہ میں کس طرح اور کن نکات کا ملاحظہ کرکے ردعمل ظاہر کرتے ہیں؟ اس بات سے کہ سید قطب اپنی دینی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی عہد کے پابند ہیں وہ اس کے ایک زندہ نمونہ ہیں ہم نے ان کے نظریات کے بعض حصوں کے سلسلہ میں یہاں پر تحقیق ا ور چھان بین کی ہے اور یہ کہ انھوں نے کہاں سے اپنے اسلامی (انقلابی)فکر کا آغاز کیا۔ انھوں نے اسلامی سماج پر مسلط نظام کی دینی لزوم اور وجوب کی ضرورت کے تحت ان کی نفی کوا ثبات کرنے کے لئے مجبور ہوگئے کہ وہ اسی نقطہ سے اپنی فعالیت کو شروع کریں اور اپنے نظریہ کو اس پر تکیہ کرتے ہوئے آگے بڑھائیں۔(۳۶)
تاریخی تنقیدوں کی خطا
اور دوسرے نتائج جو پہلے والے نتائج سے مشابہ اور مشترک ہیں، البتہ تاریخ میں اس کی کیفیت تاثیر اور موجودہ صورتحال پہلی صورت سے مختلف ہے لہٰذا ہم اس کی بحث مستقل اور جداگانہ کریں گے۔
صدر اسلام کی خدا داد قدر ومنزلت اور دینی اعتبار کا بے شمار داخلی تضاد کے باوجود قبول کرنے کا منطقی اور فطری نتیجہ تاریخی تنقید کی خطا ہی تھی کہ بغیر کسی تحقیق اور جستجو کے اس بات کو قبول کرلیا جائے کہ صدر اسلام کے مسلمان مایۂ ناز، محترم اور اچھے لوگ تھے اور ہر ایک نے اپنے فریضہ پر عمل بھی کیا ہے لہٰذا صاحب اجر اور جنتی ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے امور میں چوں چرا کریں۔ ایسے اعتقاد کا بلاواسطہ نتیجہ اصحاب پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے مقابلہ میں روحی ونفسانی نیز ان کا اپنے اعتقاد کی طرفداری اور اس کا تحفظ تھا۔ لیکن جب یہ تصور پیدا ہوا تو صحابہ اور ان کے عصر سے محدود نہیں رہ گیا بلکہ پوری تاریخ اسلام کو اپنے احاطہ میں لے لیا جب کہ یہ تصور صحابہ کی دینی صلاحیتوں کی تحقیق کے بالکل مخالف تھا کہ آیا وہ لوگ حق پر تھے یا باطل پر نیز انھوں نے باطل کی ترویج کی ہے یا حق کی یہی وجہ ہے جس کی بناپر ہم نے اسے ایک تاریخی دینی تنقید سے تعبیر کیا ہے۔
لیکن ایک شیعہ ایسی مشکل سے دوچار نہیں تھا۔ جس طرح وہ صدر اسلام کی تاریخ کے متعلق تنقیدی نظر رکھتا تھا، اسی طرح وہ اسلام کی پوری تاریخ کے سلسلہ میں نقادانہ نظر کا مالک تھا جس طرح صدر اسلام میں اسلام سے منحرف ہونے والوں پر تنقیدیں کیا کرتا تھا، اسی طرح ان کے بعد منحرف ہونے والوں پر شدید تنقید کرتا تھا، لہٰذا اس کے لئے یزید، مروان، عبدالملک، ہشام، منصور، ہارون، متوکل یا حجاج، ابن زیاد، یہاں تک کہ فقہا و محدثین اور علما ئے سوء کوان کے منحرف اعمال کی وجہ سے ان پر شدید تنقیدیں کرنا، اس کے لئے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس مقام پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک یہ مسئلہ اس سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر آسان تھا۔ اس لئے کہ ان لوگوں کے نزدیک حق وباطل کا معیار ہے لہٰذا وہ لوگ بڑی ہی آسانی سے شیعوں کو بھی اسی معیار اور میزان پر پرکھ سکتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صاحبان قدرت جیسے یزید، منصور اور متوکل پر تنقیدیں کی جائیں، بلکہ زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ تمام بادشاہوں شاہ عباس جیسی شخصیت بھی تنقید کا نشانہ بنی، بلکہ یہ شاہ عباس ہی نہیں تھا جس پر تنقیدیں ہوئیں بلکہ تمام شیعہ حکام خواہ وہ صفوی ہوں یا دیلمیوں میں سے ہوں، یا افشاری، یا زندیہ، یا قاجاریہ سلسلہ کے ہر ایک پر تنقیدیں ہوئی ہیں۔
البتہ جیساکہ کہا جاچکا ہے کہ ان مواقع پر ان دو جماعتوں کی صدر اسلام کے متعلق باہمی سمجھ اس فیصلہ کو معین کرنے کا واحد سبب نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے اہم ترین اور مؤثر ترین اسباب میں سے ایک سبب کی حیثیت ضرور رکھتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سنی شاہ عباس جیسے ایک سنی بادشاہ پر دینی رجحانات کے تحت اس پر تنقید کرے اور اساسی نکتہ بھی یہیں پر ہے۔ آج کل سماج میں آزادی ہے، ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کہے اور کرے اور جو نظریہ دینا چاہے اسے بیان کرسکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب قلم اور ایک طالب علم ( Student ) تمام دینی مقدسات کے سلسلہ میں اعتراض کرسکتا ہے۔ لیکن ایک متدین اور دیندار آزاد ہونے کے باوجود اپنی دینداری اور اس پر پابند ہونے کے لحاظ سے اپنی حد سے تجاوز نہیں کرسکتا اور اعتقادات کے مطابق شرعی قوانین سے زیادہ اور کسی معتبر دلیل اور حجت شرعی کے اس میں کوئی شک نہیں کرسکتا۔ بہرحال ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی متدین اور سنی عقیدہ کا حامل کبھی بھی شاہ عباس جیسے حاکم یا اس سے کم تر کسی سنی حاکم کے سامنے اس پر آشکارا تنقید نہیں کرسکتا۔ اس لئے کہ یہ رد عمل ان کے کلامی، فقہی اور متفق علیہ اجماع کے خلاف ہے۔(۳۷)
جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے بے شمار برے آثار اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں صرف فقہی اورکلامی ثمرہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور اس کے تاریخی نتائج مخصوصاً دور حاضر میں اہمیت کا حامل اور ایک عنوان سے سرنوشت ساز ہے۔ ہمارے اور ان کے نزدیک تاریخ کا مفہوم، خواہ وہ تاریخ مذہبی ہو یا ملی یا قومی اور خاندانی ہو، مختلف ہے۔ تاریخ خود اپنی تاریخی حیثیت سے؛ البتہ یہاں پر تاریخ سے مراد تاریخ اسلام ہے، ان لوگوں کے نزدیک بنیادی طورپر ایک خاص اہمیت اور عظمت کی حامل ہے جس سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی اور اس کا نظر انداز کرنا صحیح بھی نہیں ہے۔ لیکن شیعوں کے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ کی بہ نسبت ایک سنی کی نگاہ، شیعہ زاویۂ نگاہ کے بالکل برخلاف ہے، تاریخ اسلام اگر مقدس تاریخ نہ بھی ہو، تب بھی قابل تنقید و اعتراض بھی نہیں ہے۔ اگرچہ اہل سنت کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے گذشتہ کو مقدس اور قابل افتخار سمجھتے رہے ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جواپنے گذشتہ کو ایسا نہ سمجھیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ وہ دینی اعتبار سے تنقید نہیں کرتے اور اس کو مظالم کی داستان، تجاوز، ہوسرانی اور خلفا و سلاطین اور حکام کی بے دینی کی تاریخ کا نام نہیں دیتے۔(۳۸)
بہرحال اہل سنت کی نظر اور انسانی اعتقاد کے جھروکوں سے ان کا گذشتہ یعنی تاریخ ماضی اگر قابل احترام اور فخر کا باعث نہ بھی ہو تب بھی قابل مذمت بھی نہیں ہے، اسی اعتبار سے اہل سنت کے نزدیک تاریخی شعور ہمارے تاریخی شعور کی بہ نسبت کافی قوی ہے۔ جو لوگ پہلے سے ہی تاریخ پر تنقید کرتے آئے ہیں وہ کسی بھی حال میں اس کی اہمیت کے قائل نہیں ہوسکتے۔ وہ لوگ اس لحاظ سے کہ اپنے دینی چاشنی کی بنیاد پر گذشتہ تاریخ کے ضعیف پہلوؤں پر نظر نہیں کرتے، لہٰذا اسے پرافتخار اور پرشکوہ حوادث اور واقعات کا مجموعہ سمجھتے ہیں یہ تاریخ، ان کے دین کی تاریخ ہے۔ عظمتوں اور ان کی سربلندیوں کی تاریخ ہے۔ ان کے فتوحات اور جہاد کی تاریخ فتوت (بہادری) اور جوانمردی کی تاریخ، علما اور اس کے دانشوروں کی تاریخ، ہنرمندوں اور شعرا کی تاریخ، باعظمت ثقافت اور تمدن کی تاریخ، شان وشوکت اور اقتدار والے خلفا اور سلاطین کی تاریخ، یہاں تک کہ (ہزار ویک شب) افسانوں کی تاریخ ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کی شان وشوکت اور قدرت وسطوت اور اسلام اور مسلمین کے معاشرہ کے لئے نمونہ تھے۔(۳۹) لیکن شیعہ لوگ اپنے نفسیاتی سابقہ کی بنیاد پر تعمیری نکات کو نہیں بلکہ منفی پہلو کو دیکھتے ہیں اور فطری طورپر نہ صرف یہ کہ اس کو پسند نہیں کرتے بلکہ کسی نہ کسی سبب سے اس سے اپنا دامن بچالیتے ہیں۔ (یہ بات حتیٰ خود ان کی تاریخ کے بارے میں یعنی سلاطین کی تاریخ اور شیعی سلسلوں میں بھی صحیح ہے) ان کی نظر میں یہ تاریخ ظلم وستم کی تاریخ ہے قتل و خونریزی کی تاریخ، استبداد و جباریت کی تاریخ، دین فروشی اور بے دینی کی تاریخ ہے۔ ریا اور دکھاوے کی تاریخ ہے، تملق اور چاپلوسی کی تاریخ ہے اور آخرکار ایسے گمنامی کے قربانیوں کی تاریخ ہے جو شہ سواروں کے سموں میں پامال ہو کر صاحبان قدرت اور مال جمع کرنے والوں کے فلک بوس قلعوں اور محلوں کے نیچے دفن ہوگئے ہیں۔ ایک تاریخ کو اس کے شکوہ وجلال کے آئینہ میں دیکھتا ہے اور دوسرا اس کی دینداری اور عدالت کے آئینہ میں اور کم از کم یہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر ایک نے اپنے ضمیر میں حق یا ناحق ایسا ضابطہ بنا رکھا ہے اور اس بات کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان چیزوں میں جس کے بارے میں وہ خود حساس ہے اس کو بڑھا چڑھا کر ماضی کو ویسے پیش کرے جیسے خود وہ چاہ رہا ہے۔(۴۰)
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں تصویریں کس حد تک مختلف اور جدا ہیں۔ یہاں ہماری بحث اس بارے میں نہیں ہے کہ کون حق پر ہے یا واقعیت سے زیادہ نزدیک یا پھر دونوں ہی برابر اور واقعیت اور حقیقت سے دور ہیں۔ ہماری بحث اس سلسلہ میں ہے کہ ان دونوں نظریات کے مطابق مختلف نتائج اور اثرات ظاہر ہوں گے جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ اہل سنت کی تاریخ میں دوام و بقا اور استقرار شیعوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ ہے۔ یہاں پر تاریخ سے مراد شیعوں کی مستقل اورمقتدر افراد کے سلسلہ کی تاریخ ہے۔ (ان کی نظر میں کبھی بھی گذشتہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا جب کہ شیعوں میں عموما ایسا ہی ہے ان کے نزدیک حال استمرار گذشتہ ہے۔ یہاں پر اس کی نفی ہے بلکہ موجودہ شدید ترین انقلابی تحریکوں کے درمیان) موجودہ اسلام میں کوئی ایسی تحریک مل ہی نہیں سکتی جس نے اپنے کام کی بنیاد گذشتہ کے بالکل نفی پر رکھی ہو۔ لیکن یہاں پر (شیعوں کے نزدیک) مشکل سے ایسی کوئی تحریک ملے گی کہ جس کا مقصد گذشتہ کی نفی نہ ہو۔(۴۱)
ان دو طرح کے نظریات پر مرتب ہونے والے جامع اور کامل نتائج اور اثرات وہ ہیں کہ انھیں بیان کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب تحریر کرنے کی ضررت ہے۔ اس لئے کہ یہ موضوع آج کے اہم ترین مسائل سے متعلق ہے جیسے ملیت اور اسلامی پہچان، ثقافتی استقلال، پشت پناہی اور تاریخی میراث مستقل شناخت اور معاشرتی تحولات، یہ سب کے سب آج کے مسلمانوں کے لئے بھی بہت ہی اساسی اور روز مرہ کے پیش آنے والے ضروری ترین مسائل میں سے ہیں، ان سے متعلق ہے اور ان سوالات کے جواب کو دریافت کرنے کے لئے مذکورہ موضوع کے سلسلہ میں بطور دقیق تحقیق اور چھان بین کی ضرورت ہے۔
البتہ اس مقام پر بھی اس سے پہلے والے مورد کی طرح وہی تغیرات وجود میں آئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے اہل سنت یہاں تک کہ دور حاضر میں بھی اپنے ماضی کے سلسلہ میں ایسی ہی نظر رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے۔ نئی زندگی کی ضرورتوں کا دباؤ، عقل مندی اور تنقیدی رجحان میں وسعت ایسے عقائد سے کہیں زیادہ قوی تر اور سرنوشت ساز ہیں۔
یہ کہ ابھی تک یہ ضرورتیں کیوں اس نظریہ کو مؤثر انداز میں بدلنے میں ناکام رہی ہیں تو یہ عصر حاضر کی ضرورتوں کا نتیجہ ہے، جو خود عصرنو کی پیداوار ہیں۔ ایک ایسا عصر اور زمانہ جس میں ہر ایک اپنی اور اپنی تاریخی میراث اور ثقافتی حقیقت کی تعریف اور اس کے حدود اربعہ کو معین کرنے کے لئے مجبور تھا، مسلمان بالخصوص عرب دنیا والے اپنی حقیقت کو پہچنواننے پر مجبور ہوگئے۔ وہ اس بات پر مجبور ہوگئے کہ اپنی تاریخ، ثقافت اور میراث کو دوبارہ پہچان لیں۔ تاکہ اسے لوگوں کو پہچنواسکیں۔ وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ اسی پر اعتماد کریں اور اس سے تمسک کے ذریعہ فرنگیوں (انگریزوں) کی دائمی اور موذیانہ تحقیر کے مقابلہ کے لئے اُٹھ کھڑے ہوں۔ فطری طورپر ایسے سخت حالات میں وہ نہ تنہا مجبور تھے کہ اپنے افتخار آفریں تمدن و ثقافت کے عناصر پر زور دیں اور ضعیف و کمزور پہلوؤں سے چشم پوشی کرلیں، بلکہ اہم بات تو یہ تھی کہ اس کے قوی پہلوؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دیکھیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ ضعیف پہلوؤں کو چھپائیں، بنیادی طورپر ایسے پہلو ان کی توجہات کو اپنی طرف جذب نہیں کرتے تھے۔ پس اس میں کوئی شک و شبہہ نہیں ہے کہ اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو ماضی کی یادگار یعنی یہ قدیمی طرز فکر یا بالکل ختم ہوجاتے یا جو مقام اسے آج حاصل ہے، اس سے کہیں پست مقام کا حامل ہوتا اور دنیائے عرب فکر اور ثقافت کے اعتبار سے جن حالات میں آج جی رہی ہے اس کی حالت اس سے کہیں مختلف ہوتی۔(۴۲)
عبد الرزاق کا تاریخی تصور
یہاں پر مناسب ہے کہ ہم عبدالرزاق کی کتاب الاسلام و اصول الحکم، سے اس عبارت کو نقل کریں جس میں انہوں نے گذشتہ زمانہ پر تنقید کی ہے چاہے وہ صدر اسلام کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کے خلفا کا دور ہو۔ اگرچہ، جو حالات سید قطب کو حاصل تھے ویسے عبدالرزاق کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال وہ پہلے روشن فکر انسان ہیں جنھوں نے اس وادی میں قدم رکھا اور اس سلسلہ میں ہر ایک سے زیادہ مؤثر واقع ہوئے۔ اس مورد میں وہ مؤثر ترین اور پرنفوذرترین شخصیات میں سے ہیں اگرچہ عبد الرزاق کی شہرت ان کی فکر کے مقابلہ میں بعض دلائل کے تحت کہیں زیادہ کم ہے۔
اس مسئلہ کے بھی سیاسی اور معاشرتی اسباب و علل ہیں۔ ناصر اور اس سے پہلے کے ادوار میں مصر کی سیاست، بلکہ اس دوران میںپوری دنیائے عرب میں اور دور حاضر میں بھی عربی تعصب پر قائم تھی۔ جس کی ترویج اور تبلیغ کی جارہی ہے۔ ناصر کے چاہنے والے اور سیاست عرب کے مخالفین نے صرف، اس وجہ سے عبدالرزاق کا استقبال کیا کہ انھوں نے عرب کی بعض قدیمی اور خود ان کی لفظوں میں تنزلی پر گامزن کرنے والی سنتوں سے مقابلہ کے لئے قدم اٹھایا تھا، لیکن تاریخ اور گذشتہ میراث پر اس کی تنقیدوں سے وہ لوگ ناخوش تھے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ تاریخ کو زیادہ سے زیادہ باشکوہ اور باعظمت اور انسانی اقدار پر دکھائیں اور اس اعتبار سے وہ عبدالرزاق اور اس کے حامیوں کے مخالف تھے۔(۴۳)
معاشرتی لحاظ سے بھی عبدالرزاق کو اپنے دور میں نفوذ اور آگے بڑھنے کا کوئی خاص موقع فراہم نہیں ہوسکا۔ وہ اپنی کتاب کی وجہ سے دینداروں کے غیض و غضب کا نشانہ بنے جو اس وقت کی اکثریت میں تھے۔ یہاں تک کہ انقلابی نئی نسلیں جو نہایت شدت کے ساتھ مذہبی لوگوں کے افکار و عقائد کے مخالف تھے اور دور حاضر کے دینداروںکے خلاف کتاب تحریر کرڈالی اس (عبدالرزاق) سے نفرت کرتے تھے۔ اس لئے کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ دین سیاست سے جدا ہے اور جدا رہنا بھی چاہئے اور اس صورت کے علاوہ یہ سیاست ہے جو دین کو اپنی خدمت میں لے گی اور اس کے بر خلاف ممکن نہیں ہے یعنی دین سیاست کو اپنی خدمت میں نہیں لے سکتا، لہٰذا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا رہنا چاہئے۔ ایسا نظریہ جوانوں کے عقائد اور ان کی چاہتوں کے خلاف تھا اور اس دور کی ضروریات اور واقعیات کے بھی متضاد تھا۔(۴۴)
یہی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے انھیں معاشرتی اور فکری مقام نہ مل سکا۔ لیکن بہرحال اہم یہ نہیں ہے کہ اس کی شخصیت کس حد تک بانفوذ تھی اور اس حد تک ان کی شخصیت با نفوذ کیوں تھی۔ اہم تو یہ ہے کہ انھوں نے ایسے نظریات پیش کئے جو صحت اور درست ہونے کے لحاظ سے بھی اس کا اہم حصہ اور ہماہنگی اور اتفاق کے لحاظ سے بھی جدید ضرورتوں کے مدنظر نفوذ اور وسعت کے امکانات کہیں زیادہ تھے، ایسے نفوذ جو آئندہ زمانہ میں اور زیادہ فیصلہ کن ہونگے۔ جیسے جیسے عربوں کے درمیان اپنے ماضی کو پرافتخار دکھانے کی حس کم ہوتی جائے گی، ویسے ویسے اس کی اور اس کے ہم فکروں کے افکار کا استقبال بڑھتا جائے گا۔
جو کچھ بھی عبدالرزاق اور ان کی کتاب کے سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ صرف تاریخی نظریات اور ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لئے تھا، نہ کہ اس سے زیادہ۔ (اس کے بیان سے) ہدف یہ ہے کہ اس کے بیان میں غورو فکر کرکے اہل سنت کی تاریخ میں تنقید کی فکر سے متعلق جو ان کی عقائدی بنیادوں کی طرف پلٹتی ہے، اسے واضح ہو جانا چاہئے۔
''بغیر کسی شک و شبہ کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ خلافت کے ہمراہ ہمیشہ قہر و غلبہ رہا ہے۔ کسی بھی خلیفہ کا نام تاریخ نے نہیں لکھا مگر یہ کہ اسے ایک خوف ناک مسلح فوج نے اپنے احاطہ میں نہ لے رکھا ہو۔ غضبناک قدرت اس کے سر پر سایہ فگن ہے اور برہنہ تلواریں جو اس کی حفاظت کررہی ہیں۔ حتیٰ یہ کہنا بھی بعید نہیں ہے کہ خلافت کے ہر سلسلہ میں قہر و غلبہ کی مہر نظر آتی ہے۔ ہاں! جسے تخت خلافت کہا جاتا ہے وہ قائم نہ ہوا مگر یہ کہ انسانوں کے سروں پر اور خلافت مستقر نہ ہوئی مگر انھیں انسانوں کی گردنوں پر۔ جسے تاج کا نام دیا جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہے سوائے لوگوں کی جان لینے کے ذریعہ اقتدار کا مالک بھی نہیں ہے مگر یہ کہ دوسروں سے اچک لے اور کسی عظمت اور کرامت کا مالک نہیں ہے مگر یہ کہ اس عظمت اور کرامت کو دوسروں سے حاصل کیا ہو (بالکل اسی طرح جب شب طولانی ہوجاتی ہے تو دن کو چھوٹا بنادیتی ہے) اور اس کا جلوہ بھی برق شمشیر اور جنگوں کو بھڑکانے سے باقی ہیں۔''(۴۵)
''ملک کی حفاظت کی غیرت، بادشاہ کو اس بات پر ابھارتی تھی کہ وہ چیز جو اس کی حکومت کو لرزا دے یا اس کی حرمت اور عظمت کو ختم کردے یا اس کے (احترام) تقدس کو گھٹادے، اس کی حمایت کرے۔ لہٰذا یہ امر فطری تھا کہ حاکم اس شخص کے مقابلہ میں خونخوار، وحشی قاتل اور شیطان بن جائے جو اس کی اطاعت سے سر پیچی کرے۔ اسی طرح سے امر بھی فطری تھا کہ وہ ہر اس علمی بحث اور مباحثہ کا جانی دشمن بن جائے اور ایسی بحثیں جو اس کے گمان میں اس کی حکومت کے لئے خطرہ بن جائیں۔ اس کی جانب سے کسی خطرہ کے لاحق ہونے کا خوف ہو چاہے وہ خطرہ کتنا ہی بعید کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علم اور تعلیم و تربیت کے مراکز کی آزادی پر سلطنت کی طرف سے ہمیشہ دباؤ لگایا گیا ہے...''(۴۶)
''جس واقعیت کو عقل بھی محسوس کرتی ہے اور تاریخ بھی اس پر بھی گواہی دیتی ہے وہ تاریخ ماضی کی ہو یا حال کی، کوئی تاریخ بھی ہو وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ شعائر کی حفاظت اور دینی مظاہر کی ترویج اس حکومت پر موقوف نہیں ہے کہ جسے فقہا خلافت کا نام دیتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ جن کو عوام الناس اپنا خلیفہ جانتے ہیں۔ واقعیت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس دنیا کی مصلحت پر بھی موقوف نہیں ہے... بلکہ ہم کو اس سے زیادہ کہنا چاہئے۔ خلافت ہمیشہ سے اسلام اور مسلمین کے لئے نحس رہی ہے اور اب بھی ہے اور ہر شرو فساد کا مصدر بنی رہی ہے...۔''(۴۷)
''جیساکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک عظیم دعوت تھی جسے خدا وند عالم نے انسانوں کی سعادت اور دنیا والوں کی فلاح و کامیابی کے لئے بھیجا تھا ۔وہ خواہ شرقی ہوں یا غربی، عرب ہوں یا عجم، عورت ہو یا مرد، فقیر ہو یا غنی، عالم ہوں یا جاہل۔ ہر ایک کے لئے خداوندعالم نے دین واحد کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ بشر سے ارتباط برقرار کرسکے۔ دنیا کے تمام گوشوں کو شامل ہو اسلام کی کوئی دعوت عربی نہیں اور نہ ہی عربی اتحاد یا عربی دین ہے۔ اسلام نے ایک امت کو دوسری امت پر یا ایک زبان کو دوسری زبان پر یا ایک سرزمین کو دوسری سرزمین پر یا ایک زمانہ کو دوسرے زمانہ پر یا ایک نسل کو دوسری نسل پر جز تقویا کسی اور چیز کے ذریعہ برتری نہیں بخشی۔''(۴۸)
''اگر ابوبکر کی بیعت اور اس کی خلافت کے مقدمات کے سلسلہ میں غور کریں تو یہ معلوم ہوجائے گا کہ ابوبکر کی بیعت ایک سیاسی بیعت تھی اور اپنے زمانہ کی تمام حکومتی خصویات کی حامل تھی اور دوسری حکومتوں کی طرح شمشیر اور قدرت پر اعتماد کرکے قائم ہوئی تھی۔''(۴۹)
''شاید بعض وہ لوگ جن سے ابوبکر نے جنگ کی اس کا سبب یہ تھا کہ انھوں نے زکات نہیں دی تھی اور وہ اس وجہ سے دین سے بھی منھ موڑ کر کافروں کے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے کہ ان لوگوں نے بعض دوسری اسلامی شخصیتوں کی طرح ابوبکر کو قبول نہیں کیا تھا اور اس صورت میں یہ امر فطری تھا کہ وہ لوگ اس کو زکات ادا نہ کریں۔ اس لئے کہ اسے قانونی نہیں جانتے تھے اور اس کی اطاعت کے لئے سرتسلیم خم نہیں کیا تھا۔ جب بھی کوئی انسان ابوبکر کے خلاف قیام کرنے والوں کے سلسلہ میں گہرا مطالعہ اور چھان بین کرتا ہے، جنھیں مرتد کا نام دیا گیا، بیٹھ جائے اور جنگوں کے بھڑکنے کے سلسلہ میں غور کرتا ہے جنھیں جنگ ''ردہ'' کا لقب دیا گیا، وہ غور و فکر کرکے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ تاریخ کس قدر تاریک اور ظالم ہے۔ لیکن ہمیشہ نور حقیقت اپنی دمک سے تاریخ کے گھٹاٹوپ اندھیروں کو روشنی بخشتا ہے۔ آخرکار ایک دن وہ آئے گا کہ علما کی توجہات اس کی طرف مرکوز ہوجائیں گی۔ یہی صحیح ہے کہ اسی ذریعہ سے راہ حقیقت کو پالیں۔''(۵۰)
''صدر اسلام سے مسلمانوں کے درمیان یہ گمان رائج ہوگیا کہ خلافت ایک دینی منصب اور رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم کی جانب سے نیابت ہے۔ یہ تصور بادشاہوں کے نفع میں تھا کہ ایسے غلط تفکر کا رواج دیں تاکہ اس طرح اپنے تخت و تاج کی حفاظت کے لئے سپر بنالیں اور اس کے ذریعہ خروج کرنے والوں کی حمایت کریں اور ابھی بھی مختلف راستوں سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں (کس قدر زیادہ ہیں اگر کوئی اس سلسلہ میں غور کرے تو یہ راہیں کس قدر زیادہ ہیں) تاکہ اس طرح لوگوں میں یہ اعتقاد راسخ کردیں کہ خلفا کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی خد اکی نافرمانی ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے خلفا تنہا اس پر قانع نہ تھے اور جس چیز کی ابوبکر رضایت دے دی تھی اس پر بھی قناعت نہیں کی اور جن چیزوں سے وہ (ابوبکر) ناراض ہوئے انھوں نے اس پر اپنی ناراضگی نہیں جتائی بلکہ انھوں نے سلطان اور باد شاہ کو زمین پر خدا کا خلیفہ قرار دیا... اس کے بعد خلافت دوسرے دینی مباحث میں شامل ہوگئی اور عقیدۂ توحید کا ایک جزء بن گئی۔ مسلمان اس کو خدا اور رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم کی صفات کے ساتھ ساتھ حاصل کررہے تھے۔ اس کی تلقین کی جاتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے شہادتین اس کے لئے تلقین کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی بہ نسبت بادشاہوں کے جرائم اور ان کے ظلم و ستم تھے۔ انھیں گمراہ کرکے اندھا بنادیا۔ دین کے نام پر نئے راستوں کو ان سے مخفی رکھا اور دین کے نام پر انھیں دھوکے میں رکھا اور ان کی عقلوں کو محدود کردیا... یہاں تک کہ ان کے دینی شعور کو بھی محدود کردیا۔ ان کی آنکھوں کو بند کردیا اور انھیں علم کے دوسرے ابواب جو ایک طرح سے مسئلہ خلافت سے متعلق تھے ان سے محروم کردیا گیا...''(۵۱)
''کیا خلافت اور قدرت کی طغیانی کے علاوہ کوئی اور سبب تھا جس کی وجہ سے یزید نے امام حسینـ کے پاک و پاکیزہ خون کو ناحق بہا دیا اور رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کے آنکھ کے تارے کو شھید کر ڈالا۔ کیا یہی اسباب نہ تھے جس کی وجہ سے یزید نے اولین خلافت کے سب سے پہلے مرکز مدینہ رسول پر اپنا قبضہ جماکر اس کی بے حرمتی اور اس کی ہتک حرمت کی۔ کیا یہی اسباب نہ تھے جس کی وجہ سے عبدالملک نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ کیا یہی اسباب موجب نہ تھے جس کی بناپر ابوالعباس سفاح اور خونخوار بنا؟... اور اسی طرح عباسی خلفا قتل کے خطرے سے دوچار ہوگئے اور ان میں سے بعض نے بعض کے خلاف بغاوت اور سرکشی پر تل گئے...''(۵۲)
ان دلائل کی بنیاد پر جن میں سے بعض کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ایسی تحلیل اور نظریہ گذشتہ زمانہ میں نہیں دیکھی جاسکتی۔ یہ آخری صدی کے تحولات اور اس کی ضرورتوں کا نتیجہ ہے اور جیسا کہ آپ مشاہدہ کررہے ہیں یہ شیعوں کی تاریخی فہم و شعور کی تحلیل اور تجزیہ کے طریقہ سے بہت زیادہ نزدیک ہوگیا ہے۔ ایک ایسی تحریک جو اپنے بہت سارے اور طرح طرح کے موانع اور رکاوٹوں کے باوجود بہرحال آگے بڑھ کر رہے گی۔(۵۳)
یہاں پر بحث کا پہلا حصہ کامل ہوگیا۔ یعنی صدر اسلام کے متعلق شیعوں اور سنیوں کے فہم مختلف کیوں ہیںاور یہ فرق کیوں اور کیسے وجود میں آیا؟ اور کن اسباب و عوامل کے تحت وجود میں آیا اور مجموعی طورپر ان دونوں گروہوں کے دینی افکار اور ذہنیت میں کیسے نتائج اور اثرات چھوڑے؟ اور کس طرح ان دونوں کی فکری، نفسیاتی اور اعتقادی عمارت کو متأثر کیا؟ ہم نے جس حدتک ضرورت سمجھی بیان کردیا ہے۔ یہ ان دونوں گروہوں کی سیاسی فکر کی پہلی بنیاد تھی۔ اب اس کے بعد دوسری اصل کے سلسلہ میںبحث کریں گے کہ حاکم کے متعلق ان دونوں کے نظریات حاکم بعنوان حاکم کیا ہیں؟
حاکم کی بہ نسبت اہل سنت کا نظریہ
فی الحال حاکم کے متعلق اس مقام پر شیعوں کے نظریہ کو بیان کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں اس لئے کہ قارئین اس موضوع سے بخوبی آگاہ ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حاکم کی نسبت اہل سنت کا نظریہ کیا ہے اور یہ کن عوامل اور اسباب سے متأثر ہیں اور عمل میں اس کے کیا آثار اور نتائج ظہور میں آئے اور ابھی بھی ظاہر ہورہے ہیں؟
حقیقت تو یہ ہے کہ پوری تاریخ میں اہل سنت کے درمیان بعض اصولی (بنیادی طورپر) نظریات کے موافق ہونے کے باوجود اس باب میں، یہ مسئلہ پوری طرح تمام گوشوں میں روشن نہیں ہے اس کا سبب بھی معلوم ہے۔ اس لئے کہ یہ ایک دینی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حکام سے ہمیشہ بہت زیادہ ٹکراؤ پایا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ صاحبان قدرت دین اور دینداروں سے اپنے کو قانونی اور امینیتی طورپر منوانے کے درپے رہا کرتے تھے اور ان پر دباؤ ڈالتے تھے تاکہ ان کو قانونی حیثیت دے دیں۔ یعنی دین اپنے آپ کو ایک ایسی شکل میں ڈھال لے جو ان (حکام) کی آرزؤں اور خواہشات کو بخوبی بروئے کار لانے پر قادر ہو۔ شاید ہی دین کا کوئی بھی دوسرا حصہ اس حدتک تمام پہلوؤں سے اس پر دباؤ ڈالا گیا ہو اور اس حدتک ان سے فائدہ نہ اُٹھایا گیا ہو۔
اس مسئلہ کی تبعیت میں اس موضوع کے متعلق منابع اور مصادر بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو مختلف اور رنگ برنگ کے ہونے کے ساتھ ساتھ پراکندہ اور ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں۔ کنزل العمال، جو حقیقت میں اہل سنت کی احادیث کے سلسلہ میں منظم اور طبقہ بندی شدہ دائرة المعارف ہے، اس میں تقریبا چار سو احادیث تنہا کتاب الامارة، کے عنوان سے مذکور ہیں اور یہ احادیث اس مجموعہ کا تنہا ایک حصہ ہیں۔ اس لئے کہ ان کے علاوہ بہت سی احادیث موجود ہیں جو اس موضوع سے بلا واسطہ مستقلاً متعلق ہیں جنھیں اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے اس باب کی احادیث کا یہ مختصر حصہ ہے اس لئے کہ اکثر احادیث اس بارے میں جن سے استفادہ کیا جاسکتا ہے غیر مستقیم طورپر اس سے متعلق ہیں کہ اس کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔(۵۴)
ان احادیث کی سند اور رجال احادیث کے سلسلہ میں تحقیق کئے بغیر، البتہ اہل سنت کے اپنے معیار کے مطابق نہ کہ شیعوں کے معیار کے مطابق، موضوع بحث کو نظر میں رکھنے کے ساتھ ساتھاور ان کے درمیان تعارض و تنوع کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ بات بڑی ہی آسانی سے معلوم ہوجاتی ہے کہ اس سلسلہ میں جعل و تحریف کا بازار خوب خوب گرم رہا ہے۔ اگرچہ بہت کم ایسے محدثین اور علما گذرے ہیں جنھوں نے اپنے آپ کو اس بات کی اجازت دے دی ہو کہ وہ ان احادیث (نصوص) میں تنقید کریں، لیکن یہ مسلّم ہے کہ ابتدا میںیہی مطلب ذہن میں آتا ہے، البتہ سیاست کی دخالت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امر فطری بھی محسوس ہوتا ہے۔
یہ کہ بہت کم لوگوں نے ان احادیث میں تنقید کی جرأت کی ہے یہ خود اپنے مقام پر حائز اہمیت ہے اس لئے کہ طول تاریخ میں اس موضوع سے متعلق مختلف مسائل مخصوصاً معتزلہ کی نہائی شکست اور اشاعرہ کی شہرت حاصل کرلینا اس قدر اجماع اور اتفاق کا حامل تھا کہ قاعدتاً ابتدائی منابع اور مصادر کے بارے میں صحت و سقم کی گفتگو ہی فضول تھی یہاں پر بحث یہ نہ تھی کہ یہ احادیث (نصوص) آیا علم رجال اور درایہ کے اصول وضوابط کے مطابق ہیں؟ یا اس کے معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان احادیث کے متعلق کوئی دوسری تفسیر اور بیان کو اس لحاظ سے حاصل کرنے کی کوشش جو فقہا، متکلمین اور محدثین کے اجماعی اور متفق علیہ نظر یات کو باطل کرے وہ پہلے سے ہی محکوم تھی۔
اس دوران ایک دوسری مشکل تھی وہ اس شخص کے متہم ہونے کا ڈرتھا مخصوصا ان علما کی تہمت جو بلا واسطہ یا غیر بالواسطہ حکام کی حمایت کررہے تھے۔ ا س لئے کہ ان کے بارے میں معمولی جستجو جز کی حیثیت اور موقعیت کے تنزل اور ان کی حکام کی مشروعیت کو کم کرنے کے کچھ اور نہیں تھی۔ جو چیز عملی طور پر موجود تھی آخری نظریہ وہ تھا جس میں درحد امکان حکام وقت کی تائید اور اس کی تقویت میں نظر دی جائے اور چونکہ حالات بھی ایسے تھے، لہٰذا کوئی بھی نئی کوشش اس کی بیشتر تائید اور تقویت میں مفید واقع نہیںہوسکتی تھی اور عملی طور سے وہ ان کو کمزور بنانے میں ان کی معاون ہوسکتی تھی۔ جب یہ فکر ایک اصل اور قاعدہ کے عنوان سے قبول کر لی گئی تھی تو صرف قہر اور غلبہ کے زور پر اور اقتدار کے استقرار کے ذریعہ کسی پر مسلط ہوجانا اور شمشیر و خونریزی کے ذریعہ حکومت کو حاصل کرلینا مشروعیت لاتا ہے، لہٰذا اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے خلاف اعتراض اور قیام کرنا منع اور حرام ہے، اس صورت میں اس کی اس سے زیادہ تائید اور تقویت کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچتا جس سے تمسک کرتے ہوئے دوبارہ احادیث میں جمع و تاویل اور جرح و تعدیل کا راستہ اختیار کریں، جب حالات ایسے تھے تو ایسی صورت میں فطری طورپر نہ تو نظام حکومت اس قسم کی بحث اور چھان بین کو پسند کرتے تھے اور نہ ہی ان سے ساز باز رکھنے والے علما چھان بین کو پسند کرتے تھے۔ یہ دو عوامل اور دوسرے اسباب اس بات کے باعث ہوئے کہ بحث ایسے ہی مجمل اور بغیر تنقید کے رہ جائے۔
موجودہ صدی کی تیسری دہائی کے نصف میں خلافت عثمانی کے ساقط ہوتے ہی جس اہم شخص نے ایک دوسرے انداز میں اس مسئلہ کی تفسیر و تحلیل کی، وہ الاسلام و اصول الحکم، نامی کتاب کے مؤلف علی عبد الرزاق ہیں جنھوں نے ایسے وقت میں دنیائے اسلام مخصوصاً دنیائے عرب میں ایک عظیم ہنگامہ کھڑا کردیا۔ انھوں نے بطور مستقیم خلافت کی بحث اور اس کی دینی و تاریخی حیثیت اور اس کے وجوب شرعی یا عدم وجوب شرعی کے موضوع کو چھیڑا اور یہ دور ایسا تھا جس میں خلافت عثمانی کے سقوط نے، بڑی شدت سے تمام اذہان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، اس کو چھیڑ دیا اور امامت و حکومت کے مسئلہ کو عمومی طورپر اپنی بحث و نقد کا مرکز بنالیا۔
اس کتاب نے جو ہنگامہ کھڑا کیا وہ اس نکتہ کو بتا رہا تھا کہ اس موضوع کے متعلق اہل سنت کے عقائد ان مورد میں کس حدتک غیر قابل تنقید اور مناقشہ ہیں۔ واقعیت تو یہ ہے کہ یہ ہنگامہ اس سے زیادہ کہ (عبدالرزاق کے مخالفوں کے بقول) مؤلف کے دین اور اسلام مخالف رجحان کی نشاندہی کرتا ہے اور مثال کے طور پر یہ ان کے کفر و الحاد کی علامت ہے، اس سے کہیں زیادہ اس موضوع کے متعلق اہل سنت کی حساسیت کا موضوع وہ مباحث تھے جس پر انھوں نے تنقید و تحلیل و تجزیہ پیش کیا تھا۔ وگرنہ اسی دور میں ان کے علاوہ بہت سے دوسرے بھی مصنفین تھے جولوگ اسلام کے اصولی مسائل میں بھی خدشہ اور شک و تردید ظاہر کیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں سے کسی کو بھی اس شدت سے چہار جانب مخالفتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ اس کتاب کے سلسلہ میں یہ کہا گیا: ''جب سے ہمارے ملکوں میں کتابوں کے چھاپنے کی صنعت کا رواج ہوا ہے، اس وقت سے آج تک کوئی کتاب بھی ایسی نہیں چھاپی گئی ہے جو عبدالرزق کی کتاب کی طرح کسی اور کتاب نے اس حدتک شورشرابہ، شر و فساد اور ہنگامہ کھڑا کیا ہو۔''(۵۵)
حکومت اور حاکم
بحث میں وارد ہونے سے پہلے ایک نکتہ کی طرف یاد دہانی ضروری ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حکومت سے مراد اسلامی اور دینی حکومت ہے، جس کی خصوصیات ایک مسئلہ ہے اور حاکم اور اس میں پائی جانے والی شرائط اور صفات ایک دوسرا جدا گانہ مسئلہ ہے۔ یہ دونوں باہم باطنی ارتباط رکھنے کے باوجود عملی طور سے دو متفاوت چیزیں ہیں اور دو مختلف عوامل کے تحت متأثر ہوئے ہیں۔
حکومت کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ عموماً قرآن اور سنت رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم نیز بعض مواقع پر صحابہ کی میراث سے متأثر ہے۔ لیکن حاکم کی بہ نسبت مسئلہ ان کا نظریہ صدر اسلام سے عباسیوں کے دور اقتدار کی ابتدا کے سیاسی اور تاریخی حالات سے متأثر ہے۔ یا واضح تر الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حکومت کے متعلق ان (اہل سنت) کا تصور اور فہم اسلام کے نظری معیار سے متأثر ہے اور حاکم کی حیثیت سے اس کا تصور تاریخی حقائق سے متأثر ہے۔ اگر یہ تعبیر حکومت اور اس کی خصوصیات کے سلسلہ میں مناسب ہو تو پھر آرزوؤں کے طالب اور اسوہ و نمونہ کے فکرمند حاکم کے متعلق واقعیت پسند اور واقع بین ہیں۔ ان لوگوں کی نظر میں ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں پایا جاتا (بالکل شیعوں کے نظریہ کے بر خلاف) یہ دونوں دو مختلف چیزیں ہیں اور ان دونوں کو مختلف ہی دیکھا جانا چاہئے۔(۵۶)
اب یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اسلام ایک وسیع اور جامع دین ہے۔ جو دین ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ہے عبادت بھی ہے اور قانون و سیاست بھی۔ یہ خصوصیات ایک دین ہونے کے عنوان سے خود اسلام کی طرف پلٹتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لئے دوسرے ادیان کے ماننے والوںکی طرح اس پر اسلام کے تمام عقائد پر ایمان رکھنا واجب ہے اور چونکہ حقیقت ایسی ہی ہے لہٰذا اسلام کے غیر عبادی حصہ سے بھی چشم پوشی کرنا ناممکن ہے۔ وہ شخص مسلمان ہی باقی نہیں رہ سکتا و حالانکہ اس نے ان حصوں کو فراموشی کے حوالہ کردیا ہے۔ اگر وہ ان پر عمل نہ کرنا چاہے یا ان پر عمل نہ کرسکے اس کا معتقد اور ملتزم نہ رہے ۔ اس لئے کہ ان عقائد پر ایمان نہ رکھنا اس کے عقائد کی صحت کے لازمہ کے بر خلاف ہے۔
لیکن یہ مسئلہ کا صرف ایک پہلو ہے اور نظریہ پردازی سے متعلق مسائل ہیں لیکن یہی مسائل عملی طور پر ایک دوسری شکل اختیار کرلیتے ہیں، جیساکہ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اسلام دین بھی ہے اور ایک حکومت بھی، قرآن اور سنت نبوی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اس حکومت کو کس حاکم کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور اس مسئلہ میں قرآن و سنت کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے کیا ان دونوں نے جسے بیان کیا ہے ویسا ہی وجود میں بھی آیا ہے یا مسئلہ دوسری طرح پیش آگیا، جو تغیرات وجود میں آئے وہ کیا تھے اور کیوں وجود میں آگئے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
یہی ان حساس ترین نقاط میں سے ایک ہے جس کے ذریعہ سیاست و امامت اور حکومت کے متعلق شیعوں اور سنیوں کے نظریات میں شدید اختلاف ہے۔ دنیائے اسلام کے متعلق ان دونوں کا فہم دینی اعتبار سے اسلامی دنیا میں کوئی فرق نہیں رکھتا ہے اس لئے یہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ دنیائے اسلام کے قوانین اسلام ہی کے قوانین کا ایک حصہ ہے اور اس پر ایمان رکھنا اور اس پر پابندی بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں گروہ یکساں طورپر حکومت اسلامی کی ضرورت کے قائل ہیں۔ لیکن اس کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے، یہاں تک کہ اس کے فروعات میں بھی بہت زیادہ فرق کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا اساسی فرق اور اختلاف صرف حاکم سے متعلق ہے۔ حکومت کے متعلق دونوں ایک جیسے نظریات کے حامل ہیں۔ اہل سنت کے نظریہ کے مطابق حاکم عملاً نظری اعتقاد کے لحاظ سے حکومت سے جدا اور ایک الگ مفہوم ہے اور جو چیز اس سے متعلق ہے حالانکہ شیعوں کے نظریہ کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ بلکہ ایک دوسرے سے متصل ہیں۔(۵۷)
اس نکتہ کی وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم امامت و وصایت کے متعلق ان دونوں کے نظریات کو بیان کریں۔ اس مقام پر مسئلہ یہ نہیںہے کہ رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم کا وصی کون ہے؟ مسئلہ کا آغاز یہاں سے شروع نہیں ہوتا۔ شیعوں کے نزدیک بنیادی طورپر مسئلہ، امام اور وصی کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ امامت و وصایت ہے۔ کسی شخص کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے مقام اور مرتبہ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ امامت و وصایت کا مرتبہ کیا ہے اور اس کی منزلت کیا ہے اور اس کے مطابق کون امام یا وصی بن سکتا ہے۔ ان کی نظر میں امام اور خلیفہ وہ ہے جس میں اس منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ پہلے شان و منزلت کی تعریف اور اس کی حدبندی کی جاتی ہے اور پھر اس مقام کے حائز شخص کو معین کیا جاتا ہے۔(۵۸)
یہ نکتہ زیادہ وضاحت طلب ہے اور اگرچہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ ہماری بحث کو ایک حدتک موضوع سے منحرف کردے؛ لیکن اس چیز کے واضح ہونے کے لئے کہ بہتر سمجھنے میں یہ بحث خاصی اہمیت کی حامل ہے، مجبوراً ہم پر لازم ہے کہ اس بارے میں مزید گفتگو کریں۔
شیعوں کا موقف
آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بعد خلافت و وصایت کے متعلق شیعوں کا نظریہ اور ان کا موقف تنہا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنے بعد امام علیـ کو اپنا جانشین مقرر فرمادیا ہے اور بار بار اس موضوع کی تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ بنیادی طورپر اس موضوع کے متعلق ان کا درک وسیع و عمیق اور اس کی کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ یا ایک دوسرے بیان کے مطابق ایک فرد اور آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کا جانشین کون ہے؟ مسئلہ اس میں منحصر نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی جانشینی کا مفہوم کیا ہے؟ اور اس کے جوانب اور خصوصیات کیا ہیں؟ اور ان خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے کون اس منصب کو سنبھال سکتا ہے اور کس کو یہ منصب سنبھالنا چاہیئے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ شیعہ حضرات آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خلافت و وصایت کے سلسلہ میں مختلف عقلی و نقلی دلائل کی رو سے ایک خاص مقام و منزلت کے قائل ہیں اور انھیں اس بات کا اعتقاد ہے کہ خلافت و وصایت اپنے اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے سیاسی رہبری کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بلند و بالا درجات کی حامل، حساس تر اور سرنوشت ساز ہے۔ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم اپنے دور میں مسلمانوں کے سیاسی رہبر (اس کے رائج مفہوم و معنی میں) نہیں تھے کہ صرف اپنے ہاتھ میں اقتدار لئے رہتے نتیجةً یہی کیفیت ان کے جانشین کی ہے کہ مقام رہبری میں وہ ایک معمولی سیاسی رہبر کا کردار ادا نہیں کرسکتا۔ ایک عام انسان آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کا جانشین نہیں ہوسکتا جو صرف عوام کی سیاسی رہبری کو اپنے ہاتھوں میں لئے رہے۔ اور یہ خود پہلے درجہ پر ان خصوصیات کا ہونا اسلام کی انفردی شان ہے۔
جیساکہ ہم نے بیان کیا کہ اسلام دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکومت بھی ہے۔ ایمان بھی ہے اور سیاست و حکومت بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ اور بہم متصل ہیں اور ان میں جدائی نا ممکن ہے پیغمبر اسلامصلىاللهعليهوآلهوسلم مدینہ کے حاکم اور زمام دار ہونے کے عنوان سے اس بات پر مصر تھے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی سیرت اور مدینہ میں زمام داری کا طریقہ خود اس بات پر بہترین دلیل ہے۔ اس سماج کی قرآنی تعلیمات اور اس کے احکام کے مطابق رہبری کرنی چاہیئے۔ یہاں پر سماج کو اسلام کے دستورات کے مطابق ادارہ کرنا مقصود تھا نہ کہ تنہا لوگوں کا انتظام سنبھال لینا۔ بلکہ اصلی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی زندگی عدل کے مطابق ادارہ ہو اور ان کی زندگی کے تمام گوشوں، فردیاور مختلف معاشرتی گوشوں میں اسلامی قوانین کو حاکمیت حاصل رہے۔ اور یہ امر اسی وقت پورا ہوسکتا تھا جب اس سماج کا رہبر اپنے اندر اخلاقی اور معنوی لیاقت کو علم و بصیرت باہم ملائے ہوئے ہو اور پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم ایسی ہی خصوصیات کے اتم اور اکمل مصداق تھے۔
مسئلہ یہ ہے کہ کون ایسی رہبری کو سنبھال سکتا ہے اور کون ایسا شخص ہے جسے ایسے راہبر کا جانشین ہونا چاہیئے جو سماج کو بھی چلائے اور لوگوں کی زندگی کے تمام فردی اور معاشرتی پہلوؤں میں اسلامی قوانین کو جاری کرسکے۔ زیادہ واضح عبارت میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ اسلامی قوانین میں سے کسی بھی قانون کے سلسلہ میں معمولی خطا کے بغیر سماج کی رہبری کرے۔ کیا وہ شخص جو تنہا سماج کے سیاسی امور کو ادارہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ مطلوبہ شرائط کا مالک ہوسکتا ہے؟ اور کیا اس منصب ( وصایت اور ولایت) کے لئے کم سے کم شرائط کا حامل ہے؟
اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کو لوگوں کی رہبری کے سلسلہ میں ایک سیاسی رہبر کے مقابلہ میں برتری حاصل تھی تو اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے جانشین کو بھی ایک سیاسی رہبر کے مقابلہ میں مخصوص صلاحیتوں اور فضیلتوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو قبول کرلیں کہ ہر دور میں نہ تنہا یہ کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے دور میں سماج کو قرآنی اور اسلامی قوانین کے مطابق چلانا ایک فریضہ ہے تو اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے جانشین اور حرضی کو بھی اپنے فریضہ کی انجام دہی کے لئے علمی قدرت اور لازم دینی بصیرت کے ایسی خصوصیات سے بہرہ مند ہونا ضروری ہے۔ آخرکار اگر ہم نے یہ قبول کرلیا کہ ایک اسلامی سماج کا رہبر جو احکام اسلامی اور اس کے اقدار کو محقق کرنے کی فکر میں ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس میں روحی اور معنوی امتیازات اور خاص تقویٰ پایا جاتا ہو اور خود ایسے فضائل کا مالک ہو جسے سماج میں رواج دینا چاہتا ہے اور مسلماً یہ قاعدہ اس شخص کے بارے میں جو آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بعد قدرت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے بدرجۂ اولی اس میں ان خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔
اسی وجہ سے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی خلافت و وصایت یا ایک دوسری تعبیر کے مطابق اصل امامت شیعوں کے نزدیک ایک خاص فضیلت اور مرتبہ کی حامل ہے۔ اس سے پہلے کہ مسئلہ، جانشین کے سلسلہ میں اٹھے اور یہ کہ وہ کون شخص ہے، اصل مسئلہ مفہوم جانشینی کے مختلف گوشوں کا ہے اور یہ کہ کون شخص ایسے منصب کا عہدہ دار اور ان صلاحیتوں کا حامل ہوسکتا ہے اور کون فرد اس عہدہ کو سنبھا لے۔
یہ صحیح ہے کہ حضرت امیر المومنین علیـ کی بلا فصل خلافت کے سلسلہ میں شیعوں کا عقیدہ پہلے مرحلہ میں حضرت رسول خداصلىاللهعليهوآلهوسلم کی جانب سے آپ کی جانشینی کی سفارشیں اور مکرر و صریح تاکیدیں تھیں لیکن اس مقام پر اس نکتہ کو اضافہ کرنا ہوگا کہ امیر المومنین حضرت علیـ اس وجہ سے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بلافصل خلیفہ تھے کہ وہ ان خصوصیات کے مالک تھے کہ جو ایسے منصب کے لئے ضروری ہیں اور ہر دوسرے شخص کے مقابلہ میںسب سے زیادہ منصب خلافت کے لئے شائستہ اور اس کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق وہ سبب جو اس بات کا باعث بنا کہ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم امام علیـ کو بلافصل خلیفہ متعین کردیں، ان میں وہ منحصر بہ فرد خصوصیات موجود تھیں جو کسی دوسرے شخص میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ یہی خصوصیات باعث ہوئیںجس کی وجہ سے آپ دوسرے شخص کے مقابلہ میں اس منصب کے لئے زیادہ شائستہ ہوں۔ آپ کا یہ امتیاز شائستگی اور کفایت جو آپ کو اس منصب کے لئے شائستہ بنارہی تھی۔ خود آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کا آپ کو انتخاب کرکے آپ کے بارے میں سفارش کرنا اس مدعا کی عملی تائید تھی۔
خلاصہ یہ کہ شیعوں کے نزدیک امامت و خلافت کے مسئلہ میں بحث، کسی فرد کے سلسلہ میں ہونے سے پہلے اس کی منزلت اور فضیلت کے سلسلہ میں ہے۔ سب سے پہلے مقام و منزلت کی تعریف اور حدبندی کی جائے اس کے بعد صاحب مقام و منزلت کو منتخب کیا جائے۔ امام وہ ہے جس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہوں جو منصب امامت کے احراز کے لئے ضروری ہیں اور ایسا ہر گز نہیں ہے کہ امامت و خلافت کی کوئی زاتی شان اور حیثیت ہو جس کے خلفا اور ائمہ حامل رہے ہیں، وہ حاصل ہو جائیں۔(۵۹)
لیکن اہل سنت کے نظریہ کے مطابق مسئلہ بالکل برعکس ہے۔ ان کے وہاں اس شان کا حامل پہلے معین کیا جاتا ہے پھر اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شان اورحیثیت تعریف اور اس کی حدبندی کی جاتی ہے۔ وہ پہلے وصی اور خلیفہ کو معین کرتے ہیں اور اس کے بعد خلافت اور وصایت کی تعریف کرتے ہیں۔ حاکم کے متعلق ان لوگوںکا نظریہ اسی اصل کے زیراثر ہے۔ جو کچھ واقع ہوجاتا ہے اسے قبول کرلیا جاتا ہے اور پھر حاکم کے اختیارات اور اس کی خصوصیات، حالات کی تعریف اور اس کی حدبندی کی جاتی ہے۔
اب تک جو کچھ بیان کیا جاچکا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بطور اختصار یہ کہا جاسکتا ہے: اہل سنت اور شیعوں کے نظریات سیاست اور حکومت سے متعلق اور کلی طورپر اسلام کے غیر عبادی قوانین چونکہ ایک ہی منابع اور مصادر کی طرف پلٹتے ہیں، لہٰذا ایک حد تک یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں اور اگر ان دونوں میں کوئی اختلاف بھی ہے تو وہ صرف فروع میںہے اور اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی ان کی سنت کی تحقیق اور چھان بین کے سلسلہ میں تنقید کے معیار کی طرف پلٹتا ہے۔ اس لئے کہ سنت نبوی کو پہچاننے میں ان دونوں کے معیار مختلف ہیں۔ حاکم کے حالات اور خصوصیات کے متعلق ان دونوں کے نظریات میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں اہل سنت کا نظریہ ان حکام کو قانونی حیثیت دینے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا جو صدر اسلام (ابتدائی صدیوں) میں حکومت کو اپنے اختیار میں لئے ہوئے تھے۔ اسی کو قانونی مان لینے کے سبب اس باب میں ان کے کلامی اور فقہی مباحث وجود میں آئے اور انھیں ترقی ملی لیکن شیعوں نے بنیادی طورپر اس مسئلہ کو ایک دوسرے زاویہ سے دیکھا ہے۔ حاکم کے متعلق ان لوگوں کے نظریات اصل حاکمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وجود میں آئے۔ حاکمیت جس طرح آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کے ہاتھوں میں تھی اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے جانشینوں کے ہاتھ میں پہنچی یا جس طرح ان تک پہنچنا چاہئے تھا۔ ان لوگوں کی نظر میں حاکمیت نبوت و رسالت کا ایک جزو ہے اور چونکہ امامت و وصایت بھی اسی طرح نبوت کا ایک سلسلہ اور اس کی بقاکا نام ہے اور اس کا مر تبہ اسی کے جیسا ہے، لہٰذا یہاں بھی وہی حاکمیت سرایت کرے گی (یہاں پر ادامہ کو استمرار سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اصل خاتمیت کے منافی نہیں ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے) درست یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ان لوگوں کی فکر حاکمیت کے باب میں ان کے حالات و خصوصیات اور اس کے اختیارات وجود میں آجاتے ہیں۔ لہٰذا اس زاویہ کے مطابق اسلام کی ابتداء میں جو کچھ ہوا وہ سب قانونی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور اس کو فطری طورپر حاکم کے شرائط اور خصوصیات کو قانون مند کرنے کے لئے معیار نہیں بنایا جاسکتا۔
یہاں پر مناسب ہے کہ خوارج کا بھی ذکر کیا جائے۔ ان لوگوں نے نفسیاتی، معاشرتی اور قبیلہ جاتی اسباب کی بنیاد پر اہل سنت کے برخلاف پہلے موجودہ حالات کی بالکل اس کی نفی کردی اور پھر حاکم اور اس کے شرائط کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا۔ شیعوں کی طرف سے موجودہ حالات کی نفی کرنا خاص قسم کے نظریاتی دلائل کی بنا پر ہے اور خوارج کے نظریات موجودہ حالت کی نفی کے ذریعہ ہی وجود میں آئے تھے۔
بہرحال ہماری بحث یہ تھی کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ ان کے حکومت کے نظریہ کی بہ نسبت نہیں تھا۔ حکومت کے سلسلہ میں ان لوگوں کی فکر سماج کو اسلام کے قوانین کے مطابق ادارہ ہونا چاہئے یہ قرآن و سنت سے متأثر تھا حاکم اور اس کی خصوصیات کے متعلق ان کا نظریہ تاریخی حقائق سے متأثر تھا۔
دو نظریئے
دو طرح کے زاویۂ نگاہ کا آغازان دومسئلوں کی نسبت آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی رحلت کے بعد والے ایام کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کی وفات کے بعد کسی کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سماج پر اسلامی احکام اور اس کے دینی موازین اور معیار ہی کومعاشرہ پر حاکم ہونا چاہئے۔ یعنی سماج کو کن قوانین کے تحت ادارہ کرنا چاہئے یہ مسئلہ بالکل واضح اور متفق علیہ تھا لیکن اس حاکم کے بارے میں جسے خلافت کے لئے انتخاب ہونا چاہئے، مسئلہ بہت واضح نہیں تھا۔ جو چیز اہمیت کی حامل تھی اور عملی طور پر موجود تھی وہ یہ کہ سماج کو منظم اور ادارہ ہوناچاہئے اورایک فرد کو اس منصب کے لئے منتخب ہونا چاہئے تھا۔ جب ابوبکر کو لوگوں نے خلیفہ بنادیا، عموماً لوگوں نے اس کی بیعت کرلی۔ اس کی بیعت خاص ان اوصاف کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی یا ایسی خصوصیات کی بناپر نہیں ہوئی تھی جس کے لئے وہ لوگ اپنے حاکم کے لئے قائل تھے۔ ان لوگوںکی نظر میں یہ مسئلہ کہیں زیادہ عملی اور اسے فوراً انجام پانا تھا، بلکہ ان۔ غور و خوض اور تنقیدوں سے بھی یہ مسئلہ زیادہ سادہ تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کرلی اور بقیہ دوسرے لوگوں نے بھی وقت ضائع کئے بغیر ان لوگوں کا اتباع کرلیا۔
ابوبکر کی حاکمیت اور خلافت ایک تاریخی حقیقت کے طورپر قبول کرلی گئی۔ اس زمانہ میں ابوبکر کے علاوہ اگر کسی دوسرے شخص کی بھی بیعت کرلی گئی ہوتی تو اس کی بھی خلافت اور حاکمیت کو قبول کرلی گئی ہوتی۔ جس چیز نے خلیفہ اول کی خلافت کو مستقر اور پائدار بنا دیا، وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کرلی اور بقیہ لوگوں نے یہ کہہ کر بیعت کرلی کہ ہم بھی انھیں کے تابع ہیں۔ اس مقام پر قابل غور بات تو یہ ہے جب اہل مدینہ نے حضرت زہرا٭ کی لگاتار دعوتوں کے جواب میں ان لوگوں سے یہ چاہ رہی تھیں کہ وہ لوگ آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی وصیت کو فراموش نہ کریں اور حق کو اس کے راستہ سے منحرف نہ کریں تو وہ لوگ کہہ رہے تھے: ''آپ کو اس سے پہلے اقدام کرنا چاہئے تھا۔ اب تو ہم نے بیعت کر لی ہے اور مسئلہ تمام ہوچکا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے آتیں تو ہم ضرور علی کے ہاتھوں پر بیعت کرلیتے۔''(۶۰)
اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا آخری انجام کیا ہوا، پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کا ایک حاکم اور زمام دار کے عنوان سے ان کا اپنا مقام خود تھا اور یہ خاص مقام بعنوان شارع، سیاستمدار اور ایک سیاسی رہبر کے عنوان سے بھی شرعی مقبولیت کے ساتھ تمام لوگوں کے نزدیک قابل قبول تھا۔ آپ کے بعد قدرت ابوبکر کے ہاتھ میں آگئی اس زمانہ کے لوگ اس کے لئے چاہے اس کے قبل ہو یا بعد خاص دینی مقام کے قائل نہ تھے۔ ان لوگوںکی نظرمیں وہ بھی دوسرے مہاجرین و انصار کی طرح ایک فرد تھا۔ لیکن اہمیت کا حامل یہ تھا کہ اس کی بیعت آنے والے ادوار میں ایک فکر کی پیش خیمہ بنی جو بعد میں حاکم اور اس کے شرائط کے متعلق اہل سنت کی اصلی فکر میں تبدیل ہوگئی۔ اس مطلب کو واضح کرنے کے لئے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے۔
جن لوگوں نے سب سے پہلے ابوبکر کی بیعت کی، ان کی تعداد بہت کم اور انگشت شمار تھی۔ ان لوگوں کی بیعت دوسروں کی بیعت کا اصلی مقصد بن گئی۔ یعنی بعد میں بیعت کرنے والوں نے کہا کہ چونکہ ان لوگوں نے اس کی بیعت کرلی ہے لہٰذا ہم بھی اس کی بیعت کریں گے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم واقعیت کے سامنے سرتسلیم خم ہیں۔ ان کا تسلیم ہوجانا یعنی اس کو قانونی حیثیت دے دینا۔ اس لحاظ سے اس کو قانونی حیثیت سے تسلیم کرلینا ایک حقیقت بن گیا تھا۔
اگرچہ خلیفہ اول و دوم کے سلسلہ میں یہ واقعیت اس حد تک محسوس نہیں تھی لیکن ان دونوں موارد میں بھی حقیقت اس طرح تھی۔ ابوبکر نے عمر کو معین کیا یعنی اس کی خلافت اور جانشینی کو قانونی حیثیت دے دی اور لوگوں نے بھی (اس مسئلہ میں) اس کا اتباع کیا۔ عثمان کو عبد الرحمن نے چھہ نفرہ کمیٹی کی نیابت میں قانونی حیثیت دے دی، لوگوں نے بھی اسے قبول کرلیا۔ لیکن حضرت علیـ کے خلیفہ بننے کا واقعہ ایک دوسری منطق کی بنیاد پر استوار تھا۔ آپ کو لوگوں نے وسیع پیمانہ پر اپنے بے حد اصرار کے ذریعہ اپنا خلیفہ بنالیا تھا۔
اس مسئلہ میں جو نکتہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ حاکم کی حکومت کے سامنے اپنا سرتسلیم خم کردینے کی فکر کے سبب جو اس کی حکومت کی ایک واقعیت ہے لہٰذا خلفائے راشدین کے دور میں اس فکر کا نطفہ وجود میں آیا۔ اگرچہ اس تفکر کا نطفہ بعد میں خاص طور سے بنی امیہ کے برسرکار آنے کے وقت بارآور ہوگیا اور عملی طور خلفائے راشدین کے دور میں اس نے کہیں زیادہ متفاوت اور مختلف مفاہیم اور مطالب پالئے اور ان کے زمانہ سے جو کچھ ہوتا تھا اسے عملی شکل دے دی گئی اور اسی دور کو دینی اور قدسی احترام مل گیا۔ اس تفکر میں بھی سرایت کرگیا بلکہ اس کی کم و بیش متفق علیہ مشروعیت نے اس کی شایان شان مدد کی۔
جیساکہ ہم نے بیان کیا کہ اس تفکر کا تانا بانا بنی امیہ کے دور میں بُنا گیا اور اس کو ترقی ملی اور اس مسئلہ میں دوسرے مسائل کی مانند معاویہ کا بہت ہی کلیدی اور بنیادی کردار تھا۔ جب اقتدار اس کے ہاتھوں میں آیا تو اس نے خلافت کو اپنے خاندان کی میراث بنانے کے لئے بہت کوشش صرف کردی۔ ایک ایسا سلسلہ جو اس زمانہ تک بے سابقہ تھا۔ تمام اہمیت کی حامل مخالفتوں کے باوجود آخرکار وہی کامیاب ہو ا اور خلافت ان کی موروثی بن گئی۔ اب اس کے بعد خلیفہ کی تعیین ایک خاص سوچے سمجھے انداز سے ہونے لگی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں رہا اور اسے مسلمانوں کے مقابلہ میں استقلال مل گیا۔ مسئلہ یہ نہیں تھاکہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں یا حاکم سے متعلق دینی ضوابط و قوانین کیا ہیں تاکہ ان (قوانین) کے مطابق خلیفہ اور حاکم کو معین کیا جائے۔ اس دور میں پہلے والا خلیفہ اپنے بعد والے خلیفہ کوجو بیٹا اور بھائی ہوا کرتا تھا اسی کو خلیفہ بنادیا کرتا تھا۔ واقعیت یہی تھی اور اسے بدل دینا بھی نہایت مشکل امر تھا اس دور کے بہت سے لوگوں کی نظر کے مطابق یہ کام ناممکن تھا۔ وہ لوگ بھی جو اس کو امر ممکن لیکن مشکل جانتے تھے وہ خوداسے پسند نہیں کرتے تھے، اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے کیونکہ بہت زیادہ مشقت، ایثار اور فداکاری کا موجب تھا۔(۶۱)
اس طرح یہ واقعیت عقیدہ، ارمان اور قانون و ضابطہ کے مقابلہ میں کامیاب ہوگئی۔ اس لئے کہ پہلے ہی سے بنا حقیقت کو قبول کرلینے پر ہی تھی۔ اگرچہ وہ واقعیت جسے بعد میں قانونی مان لیا گیا اس سے بالکل جدا تھی اس حقیقت سے جو ابتدا میں قبول کرلی گئی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں حاکم کے جو شرائط اور حدود و اختیارات تھے، بعد میں یہ شرائط بدل گئے اور آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ حاکم کو صرف اس اعتبار سے کہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے مشروعیت بخشتا تھا اور واجب الاطاعت یہاں تک کہ اگر معمولی اور کم سے کم لازمی شرائط کا مالک بھی نہ ہو یا قہر و غلبہ کے زور پر حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی ہو اور یا ظلم و ستم کرے اور وہ حدود شریعت کو بھی پامال کردے اور فاسق ہوجائے۔(۶۲)
جیسا کہ معروف قاضی اور فقیہ ابن جماعة کہتے ہیں: ''تیسرا راستہ جس کے ذریعہ جبری بیعت منعقد ہوجاتی ہے وہ کسی فرد کی قدرت اور شان و شوکت اور قہر و غلبہ سے تعبیر کی جاتی ہے اگر کسی زمانہ میں باصلاحیت اورشرائط کا حامل امام نہ ہو اور اس کی عدم موجودگی میں ایسا باصلاحیت شخص ہو جو اس منصب کو سنبھال لے اور فوجی طاقت کی بنیاد پر بغیر اس کے کہ کوئی جامع الشرائط اس کی بیعت کرے وہ اگر اس عہدہ کا احراز کرلے، ایک قوی انسان اپنی نظامی قدرت اور طاقت کے ذریعہ بغیر بیعت کے یا اس کا جانشین ہوجائے جس کی بیعت صحیح تھی، اس کو اپنے ما تحت کرلے تو ایسی حالت میں اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی... یہاں تک کہ مسلمانوں کے امور پھر سے ادارہ ہونے لگیں اور ان میں اتحاد پیدا کرلیں جہل و فسق اس کے اجرا کرنے سے مانع نہ ہوں گے۔'' اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں: ''اگر امامت قہر و غلبہ کے ذریعہ کسی پر محقق ہوجائے اور پھر کوئی دوسرا شخص قیام کرے۔ اور پہلے والے شخص کو شکست دے دے تو اس صورت میں شخص اول معزول ہوجائے گا اور بعد والا شخص امام ہوجائے گا، جو کچھ ہم نے یہاں پر مسلمانوں کی وحدت اور ان کی مصلحت کے سلسلہ میں بیان کیا۔ یہ وہی اسباب ہیں جس میں واقعہ حرہ میں ابن عمر نے کہا:'' ہم اس کے ساتھ ہیں جو کامیاب ہوجائے''۔(۶۳)
فطری طورپر ان حالات میں حکام بھی خاموش نہیں بیٹھے اور ان کا بیکار بیٹھنا منطقی بھی نہیں تھا۔ یہ طرزفکر اس حاکم کی رضایت کی موجب تھی بلکہ اس کے لئے اسوہ (نمونہ) تھا وہ اس بات کی کوشش کررہا تھا کہ قرآن، روایات، فقہ، تاریخ، کلام اور فلسفہ کے ذریعہ اپنے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ اور اس نے ایسے ہی کیا بھی اور چونکہ لوگوں کے روحیات اور ان کی، تاریخی اور ثقافتی قدمت اور اس دور کے معاشرتی اور سیاسی بدلاؤ سے ہماہنگ تھا لہٰذا فوراََ ہی شدت کے ساتھ اس میں جذب ہوگیا۔ اگر ہم یہاں پر اس موضوع کے سلسلہ میں بحث کریں اور اسی طرح احادیث کو جعل کرنے اور ان میں تحریف کا رواج کیسے پیدا ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا تو اس بحث کے ذریعہ اصل موضوع سے خارج ہونے کا سبب ہوگا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے تنہا دو نکات کے ذکر پر ہی اکتفا کریں گے۔(۶۴)
قضا اور قدر کا مسئلہ
اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دور کے قدرتمندوں کے سامنے کون سی مشکل کھڑی تھی؟ ان لوگوں کا ہدف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو حکام کی اطاعت کے لئے آمادہ کریں۔ صرف اس لئے کہ ان کی قدرت اور حکومت ایک حقیقت ہے، اس کے ماننے پر لوگوں کو مجبور کریں، امویوں کی تنہا یہی ایک آرزور تھی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے یاد دہانی کرائی ہے وہ اس قدر مائل نہیں تھے کہ دینی اعتبار سے اپنے واسطے کسی مقام و منزلت کے قائل ہوں۔ نہ تو وہ اس کے محتاج ہی تھے اور نہ ہی اسے پسند ہی کرتے تھے اور اگر انھوں نے کبھی دینی فکر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہا ہے، وہ بھی محض اپنی دنیاوی قدرت کو مستحکم بنانے کے لئے تھا نہ کہ اپنے کو مسلمانوں کے دینی خلیفہ کے سبب دینی حیثیت اور موقعیت کو مستحکم کرنے کے لئے تھا۔ جبکہ یہ عباسی خلفا کی سوچ بالکل بر خلاف تھا تاکہ وہ اپنے لئے دینی حیثیت فراہم کرلیں اور اس کے سایہ میں اپنے دنیوی اقتدار کو مزیدمستحکم کرلیں۔(۶۵)
کون سا ایسا سبب تھا جو ان کے اہداف کی تکمیل میں ان کا مددگار اور معاون ثابت ہو؟ اور لوگوں کو کسی قید وشرط کے بغیر اطاعت کے لئے مجبور کرے۔ روحی ونفسیاتی، ثقافتی اور تاریخی سابقے کو مد نظر رکھتے ہوئے قضا و قدر سے تمسک ہی ایک بہترین ذریعہ تھا۔ دوران جاہلیت کے عرب بے شک و تردید تقدیر اور قسمت کے متعلق راسخ اعتقاد کے مالک تھے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کی زندگی اور قسمت اس کے ارادہ اور اختیار سے خارج ہے اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز پہلے ہی سے معین کئے جاچکے ہیں اور ان میں تبدیلی ایجاد کرنا انسانوں کے بس سے باہر ہے۔
یہ تفکر جس حد تک ان بدو اعراب میں پایا جاتا تھا، اسی حد تک قریش اور مکہ میںرہنے والوں کے درمیان بھی کاملاً رائج اور راسخ تھا۔ بنیادی طورپر ان کی بت پرستی ایسے ارتباط میں قابل درک اور اس کی تحلیل کی جاسکتی ہے۔ ان لوگوں کا متعدد خداؤں پر اعتقاد اور ان سے تقرب طلب کرنا نیز قربانی کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اس بات کے معتقد تھے کہ صرف یہی بت ان کی زندگی میں اثر انداز ہیں۔ وہ لوگ زندگی کے تمام مراحل میں ولادت سے لیکر موت تک بیٹے یا بیٹی ہونے سے لیکر قحط سالی اور سوکھا میں مبتلا ہو جانے تک، تجارت اور اس کے منافع سے لیکر جنگ میں کامیابی اور شکست تک، خطرناک اور مہلک بیماریوں زمین گیری سے لیکر فقر و غربت مفلوک الحالی تک غرض کہ زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق مسائل میں وہ انھیں بتوں یا ارباب کو دخیل سمجھتے تھے اور اس دوران انسانوں کے کردار کو بے اہمیت سمجھتے تھے۔(۶۶)
قاعدتاً بت پرستی یا متعدد خداؤں کے رجحان اور مختلف آلہہ اور معبودوں پر اعتقاد انسان کی آزادی اور ذمہ داری کے متضاد ہے،ایک ایسی دنیا میں جہاں اس کے مقدرات کا ہر حصہ ایک نامرئی اور مستقل طاقت کے ہاتھ میں ہو، انسان کی آزادی کے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ایک انسان اسی صورت میں آزاد رہ سکتا ہے جب وہ اپنی تقدیر کا خود بنانے والا (یا کم ازکم ایک حد تک) ہو، ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کی تقدیر مستقل خداؤں کے ہاتھ میں ہے تو پھر آزادی کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہے گا۔
بہر حال زمان جاہلیت میں جبر اور تقدیر کی طرف رجحان معاشرہ کی رائج فکر جاہلیت کے زمانہ کی فکر تھی جو اس لحاظ سے مسخ اور انسان کے باطن کی نابودی کے باعث تھے، وہ لوگ قرآن کے سخت حملات اور تنقید کا نشانہ بنے۔ ایسی تنقیدیں جن کے اہداف مختلف تھے۔ پہلا ہدف یہ تھا کہ ایسے منحرف اور غیر واقعی عقائد کاخاتمہ کردیا جائے۔ یہ جاہلی اور احمقانہ وہم و خیال تھا جو اس دنیاکو متعدد خداؤںاور مختلف ارباب کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ دوسرا ہدف یہ تھا ان کے وجدان، ضمیر اور فردی ذمہ دار ی کی حس کو ایسے انسانوں میں بیدار کرنا جو اپنے آپ کو مسلوب الاختیار اور مجبور سمجھتے تھے۔ اور اسی معیار کے تحت وہ کسی بھی پستی، ذلت اور انحراف و پلیدگی کے مقابلہ میں سرتسلیم خم کردیتے تھے اور اپنے باطنی دباؤ کے مقابلہ میں کہ فطری طورپر پستی اور پلیدی سے منھ موڑے ہوئے تھے اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ان متعدد خداؤں سے تقرب کے ذریعہ اپنے زعم ناقص میں کامیاب ہوجائیں نہ کہ خود اپنی باطنی اصلاح کے ذریعہ۔ ان کے ذہنوں میں اس حالت کو بدلنے کی طرف کوئی توجہ بھی نہ تھی، جب ایک انسان کی سعادت اور شقاوت اس کے ہاتھ میں نہ ہو اور وہ اپنے اعمال کا مرہون منت بھی نہ ہو اور جوکچھ بھی ہے وہ متعدد آلہہ خداؤں اور بتوں کے ہاتھ میںہے، اس صورت میں یہ امر فطری ہے کہ کوئی فرد بھی اپنی سعادت اور خوش بختی کو حاصل کرنے کے لئے اپنی اس حالت کی اصلاح کی فکر بھی نہیں کرسکتا اور ان بتوں کے علاوہ کسی دوسرے سے توسل نہیں کرسکتا، ان کے کہنے کے مطابق اپنی شفاعت کرنے کے علاوہ کسی اور سے متوسل نہیں ہوگا۔ آخرکار یہ چاہتا تھا کہ اعتقادی اور معاشرتی بلندی و فکری سروری کی بنیادوں کو منتخب کرے اور اسی طرح سخت بے رحم اور مادی و پلید حاکم کو ختم کردے۔ اس دور کے جاہلی معاشرہ میں جو چیز حاکم کی سروری کو ایک خاص موقعیت عطا کرتی تھی نہ تو وہ قدرت شمشیر ہی کے ذریعہ حاصل ہوسکتی تھی جس کے زور بازو پر جبری خرافات رائج تھے۔ اس دور کے حجازی سماج میں قومی تعصب اور اس میں تفرقہ اور مرکز واحدنہ ہونے کی وجہ سے انھیں مطیع بنانے میں تلوار کی طاقت کارساز نہیں تھی۔ اس دور کے ظالم اور فاسد حکام کی قدر و منزلت لوگوں کی جہالت اور ان کے تعصب سے وجود میں آئی تھی نہ کہ ان کی ناتوانی اور کمزوری۔ ٹھیک اسی وجہ سے وہ لوگ نبی اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی نسبت آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک آپصلىاللهعليهوآلهوسلم سے سخت کینہ توزی کرکے آپ کے سرسخت دشمنوں میں رہے اور آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے جب وہ لوگ خوف یا طمع کی بنیاد پر مسلمان ہوئے تو پھر بھی انتقام کے لئے موقع کی تلاش میں لگے رہے اور آخرکار ان لوگوں نے امویوں کے سایہ تلے اپنا انتقام لے ہی لیا۔
حقیقت تو یہ ہے کہ توحید پر ایمان لانا اور اس کو ماننا، جس معنی میں ادیان الٰہی خاص طور سے دین مبین اسلام میں وارد ہوا ہے، اگرچہ ایک فطری اور باطنی امر ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لئے معمولی عقلی کمال کی ضرورت ہے۔ وہ انسان جس کے پاس اتنی عقل بھی نہ ہو وہ اتنی آسانی سے اس بات کو درک نہیں کرسکتا کہ اس دنیا میں سب کچھ خداکے ہاتھ میں ہے اور جن چیزوں کو انسان مؤثر اسباب میں سے شمار کرتا ہے، وہ سب کے سب خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی خدا کی مخلوقات میں سے ہیں اسی مادی دنیا کے وسائل اور آلات ہیں اور اس کی طاقت میں ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا چاہئے کہ زمانۂ جاہلیت کے اعراب کمترین عقل اور معمولی فہم و درک سے بھی محروم تھے۔ ان لوگوں کی ثقافتی و تاریخی سابقہ اور معاشرتی ماحول ہر قسم کی تبدیلیوں سے دور تھا کہ وہ عقل و رشد کے درک کرنے کا سبب بنے۔
جیساکہ ہم نے بیان کیا کہ وہ روشنی کے علت و معلوم کے مفہوم کو سمجھنے سے بھی قاصر اور معذور تھے۔ اگرچہ روشنی کے مفہوم کو اجمالی طور سے پہچانتے تھے۔ لیکن مختلف اسباب سے باہمی روابط کو کشف کرنے پر قادر نہ تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان خرافات، کہانت اور تطیر (فال بد) اپنی ممکنہ حماقت کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان رائج تھا۔ البتہ ہر قوم و ملت میں کچھ نہ کچھ خرافات پایا جاتا ہے، لیکن جو چیز ان جاہلیت کے عربوں کے درمیان رائج تھی وہ خرافات سے بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ عموماً یہ سب کچھ خرافات پسندی اور اس سے لگاؤ ہی کا نتیجہ نہیں تھاجو روحی اور نفسیاتی ضروریات کے دبادینے یا ان پر فشار نہ دینے کے ذریعہ وجود میں آتے ہیں۔ بلکہ یہ ان کی حماقت، سفاہت اور عقل کو خاموش کردینے سے وجود میں آتے تھے۔ یہاں پر مناسب ہے کہ ہم ''دور جاہلیت میں اعراب کی عقلانی زندگی'' کے سلسلہ میں احمد امین کی باریک اور دقیق توصیف کو نقل کردیں۔''
''دوران جاہلیت میں اعراب علت و معلول اور سبب و مسبب کے درمیان رابطہ کو بخوبی درک کرنے پر قادر نہیں تھے۔ اس زمانہ میں اگر کوئی انسان مریض ہوجاتا اور درد میں مبتلا ہوجاتا تو اس درد کو لاعلاج تصور کرتے۔ اگرچہ ایک طرح سے وہ مریض اور دواؤں کے درمیان ارتباط کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ باہمی ارتباط اور قانون مندی ان لوگوں کے لئے پوری طرح روشن نہیں تھا۔ بس انھیں صرف اسی حد تک سمجھتے تھے کہ اس کے قبیلہ والوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اس دوا کو فلاں درد میں استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی جان لینے پر قادر تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے لئے یہ امر تعجب کا باعث نہ تھا جب ان کا عقیدہ یہ ہو کہ رئیس قبیلہ کا خون کتے کیلئے شفا ہے یا انسان کے مریض ہونے کی علت اس کے بدن میں خبیث روح کے حلول کر جانے کے سبب ہے، لہٰذا اس کے علاج کے لئے اس روح کواس کے بدن سے خارج کرنا چاہئے۔ یا یہ کہ اگر کسی کے دیوانگی میں مبتلا ہونے سے خائف ہوتے تو اسے قاذورات اور مردوں کی ہڈیوں سے آلودہ کردیتے اور دوسرے بہت سے خرافات کے نمونے ان کے درمیان رائج تھے یہ تمام خرافات اس وقت تک مورد قبول تھے جب تک اس قبیلہ کے لوگ انھیں انجام دیتے رہتے، اس وقت تک نہ تو ان کے بارے میں کوئی سوال کرتا اور نہ ہی کوئی انکار کرتا تھا۔ اس لئے کہ یہ نظر میں گہرائی اور اسباب و علل اور مرض میں جستجو کی قدرت کا پایا جانا وہ ہے کہ انسان کو ایسے اعمال کے ارتکاب کے لئے اکساتا ہے جبکہ زمانۂ جاہلیت کے اعراب اس وقت تک ترقی کے اس مرحلہ پر نہیں پہونچے تھے۔
یہی سببیت کے رابطہ کو درک نہ کرنے کی ناتوانی باعث ہوئی جس کی وجہ سے ان کے درمیان خرافات اور خیالاتی داستانوں کا دور دورہ اعراب کی جاہلیت کو بیان کرتا ہے تھا اور یہ کہ ادبی کتابیں ایسی داستانوں سے کیوں بھری پڑی ہیں... یہی وہ اسباب ہیں جن کے مدنظر یہ نکتہ سمجھ میں آتاہے کہ وہ گذشتہ وآئندہ حوادث کو سمجھنے کے لئے کہانت اور فال بد (تطیر) سے توضیح دیتے ہیں۔''
''یہ حقیقت ہے کہ ہر قوم اور سوسائٹی چاہے جتنی بھی متمدن اور ترقی یافتہ ہوں، اس سو سائٹی میں ایسے لوگ طبیعت کے حامل ہوتے ہیں جو خرافاتی مل جاتے ہیں، لیکن عربی ادب کی کتابیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ یہ عقائد، اس زمانہ کے عام لوگوں کے عقائد تھے یہ کسی خاص گروہ سے مخصوص نہ تھا بلکہ ہر قبیلہ ان پر ایمان رکھتا تھا اور نہ یہ کہ استثنائی طور پر مخصوص افراد بلکہ انہیںکے ایسے اس زمانہ کے تمام قبیلے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو قانونی اور آئینی حیثیت دیتے تھے اگرچہ اس بات کا امکان ضرور ہے کہ ان کی مثلوں یا جاہلی اشعار میں سے ایک شعر یا ان کے قصوں میں بلند افکار کی جھلک یا اسباب و مسببات کی نسبت سببیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اور اگر ایسے تفکرات کا وجود ہے بھی تو ان موارد میں بھی گہری فکروں یا تحلیلی شرح کو واضح اور روشن انداز میں تلاش نہیںکرسکتے ہیں۔''(۶۷)
اس کے بعد امین سیرہ ابن ہشام سے ایک داستان کو نقل کرتے ہیں: ''قبائل ثقیف میں سے ایک قبیلہ کے لوگ ستاروں کے ٹوٹنے (مراد شہاب آسمانی ہے) کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے اور اپنے ہی قبیلہ کے ایک فرد عمرو ابن امیہ جو بنی علاج سے تھا اس کے پاس گئے اور وہ عربوں کے درمیان ہوش و ذکاوت میں معروف بھی تھا، اس سے کہا: ''اے عمرو کیا نہیں دیکھا کہ آسمانوں میں ستاروں کے ٹوٹنے سے کیا اتفاق اور حادثہ پیش آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا اور اس کے بعد یہ کہنے لگا: ''دیکھو اگر ٹوٹنے والے ستارے ان میں سے ہیں جن کی مدد سے خشکی اور دریاؤں میں راستے معلوم کئے جاتے ہیں، موسم سرما اور گرما کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور لوگوں کی معیشت ان سے وابستہ ہے، یہ آسمان سے ٹوٹ گئے ہیں، تو خدا کی قسم یہ اس دنیا کے تمام ہونے اور مخلوقات کی نابودی کی علامت ہے اور اگر ٹوٹنے والے ستارے یہ نہیں ہیں بلکہ وہ آسمان پر ثابت ہیں، تو یہ مخلوقات کی تقدیر کی علامت ہے جسے خداوندعالم نے خلائق کے لئے مقدر فرمایا ہے۔ اب تمہیںبتاؤ ٹوٹنے والے ستارے ان دونوں دستوں میں سے کون سے تھے؟''(۶۸)
عجیب بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی ان عربوں کے درمیان ایسے عقائد پائے جاتے ہیں، البتہ وہ لوگ جنھوں نے قدیم وراثت کو ابھی تک بچائے رکھا ہے اور اس کے مطابق پلے بڑھے اور پروان چٹ ھے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان اب بھی ایسے مسائل پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے اخباروں میں شائع ہوا تھا کہ سعودی عرب کے عظیم مفتی شیخ عبد العزیز بن باز نے ایک عرب کے بدن سے ایک شیطان کو خارج کیا اور پھر وہ شیطان ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوگیا!۔(۶۹)
اس مقام پر جو بات قابل توجہ اور غور طلب ہے وہ یہ کہ ایک ملک کی ایک عظیم مذہبی شخصیت بلکہ مکتب وہابیت کی پہلی شخصیت جس کا عقیدہ ہے کہ اس کا اسلام سلف صالح کے اسلام کے مانند خالص اور اصیل ہے شک و شبہہ خرافات اورجعلیات (جعلی چیزوں) سے دور ہے، وہ خود اس دور میں ایسے تفکرات کا مالک ہے۔ وہ خود ایک شیطان کو بھگانے کے لئے خود ایسا اقدام کرتاہے اور پھراس شیطان کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور وہ بھی اسلام قبول کرلیتا ہے۔ زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ سعودی عرب کے اخباروں نے خود اس واقعہ کو کسی تردید کے بغیر درج کردیا گویا وہ ان چیزوں کے متعلق ایسے عقائد کے حامل ہیں جن کے مقابلہ میں دوسروں کے طعنوں اور تمسخر سے نہیں ڈرتے ہیں۔
بہرحال زمانۂ جاہلیت کے اعراب کی صحیح اور ہمدردانہ درک کے لئے ان کی فکری اور ذہنی خصوصیات کا جاننا اس بحث اور بہت ساری پیش کی ہوئی بحثیں کلیدی حیثیت کی حامل ہیں۔ لہٰذا امین کی توصیفات کے طولانی ہونے کے باوجود بہتر ہے کہ اس کی کتاب کے دوسرے حصہ کو بھی یہاں پر نقل کریں۔
قدیم ایام میں اعراب کی خداشناسی
''اس دنیا کے متعلق ایک عرب کی نگاہیںایک یونانی باشندہ کی طرح کلی اور وسیع النظر نہیں ہوسکتیں ہیں۔ اس لئے کہ یونانی اپنی فلسفیانہ کوشش کے پہلے ہی مرحلہ میں اس جہان پر نظر دوڑاتا ہے اور پھر اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی ہے؟ میری نظر میں یہ دنیا تبدیلیوں اور انقلابات کا ایک مجموعہ ہے۔ کیا ان تغیرات اور تبدیلیوں کے پس پشت کوئی واحد اور ثابتحقیقت نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پانی ہے یا ہوا ہے یا آتش؟ میرے احساسات کے مطابق یہ تمامی اجزاء ایک شے واحد کی طرح ایک دوسرے سے مرتبط اور معین اور ثابت قوانین کے تابع ہے۔ یہ نظام کیا ہے اور کیسے وجود میں آیا اور کس نے انھیں وجود بخشا ہے؟
یہ سوالات اور اسی قسم کے دوسرے بہت سارے سوالات ایک یونانی اپنے آپ سے کررہا تھا اور یہی اس کے فلسفہ کی بنیاد اور یہ سب اس کی عمومی اور کلی نظریہ کا نتیجہ تھا۔ لیکن ایک عرب نہ اسلام سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد دنیا کو اس فکر اور زاویۂ نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب بھی اس کی نظریں کسی خاص چیزوں کی طرف جذب ہوتیں تو اس کی طرف لپک کر بڑھتا اور اس کے وصف میں اپنے سینہ کو حکمت و شعر اور مثل سے مالامال کرلیتا اور اس کی توصیف میں اپنی زبان کھول دیتا یعنی اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوجاتا۔
اس کی نگاہیں وسیع النظر اور کامل نہیں تھیں۔ اس اسباب اور عوامل کے بارے میں تحلیل و تجزیہ نہیں کرسکتا تھا۔ اس سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ جب وہ کسی شے سے پیش آتا تھا تو کبھی بھی اس شے کی کلیت کے بارے میں غور و خوض نہ کرتا بلکہ جو پہلو اس کی نظروں کو اپنی طرف جذب کرلیتا اس کی طرف متوجہ ہوکر غور سے دیکھتا تھا۔ جیسے جب وہ کسی درخت کے سامنے کھڑا ہوجاتا، تو وہ اس کا مل و جود کے سلسلہ میں کبھی بھی غور و فکر نہ کرتا۔ بلکہ اس کے بعض اجزا اس کی نظر کو اپنی طرف جذب کرلیتے اس کے تنے اور اس کی شاخوں کے مانند کہ وہ ان کی خوبصورتیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا اور اس کی توصیف میں اپنا سر دھننے لگتا۔ پورے باغ کو وہ اپنی نظروں میں نہیں سموپاتا تھا اور اس کا ذہن ایک دوربین کی تصویر کی طرح صورتوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتا تھا۔ اس کی مثال شہد کی مکھی کے ایسی ہے جو ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف پرواز کرتی ہے اور تمام پھولوں سے اس کے رس کو چوس لیتی ہے۔ ایک عربی شخص کی ذہنی و عقلی خصوصیت یہی ہے جو نقائص کی توجیہ کرنے والی ہے اور عربی ادب کی خوبصورتی بھی ہے یہاں تک کہ اسلامی ادوار میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔(۷۰)
شہرستانی اسی مسئلہ کو ایک دوسرے انداز میں وضاحت کرتے ہیں: ''عرب میں حکما بہت کم تھے اور ان کی حکمت بھی اکثر دفعی اور ناگہانی فکریں اور خودجوش تھیں... عربوں اور ہندیوں کی فکری فعالیتیں تقریباً ایک جیسی رہی ہیں۔ ان کا مقصد اشیا کے خواص کو معلوم کرنا تھا۔ ان کے ا فکار میں غالباً فطرت و طبع کا غلبہ تھا۔ ایرانی اور رومی لوگ اپنی فکری فعالیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت نزدیک تھے۔'' ان کا ہدف اشیا کی کیفیت معلوم کرنا اور ان کے افکار میں وجہ غالب اکتساب اور سعی و تلاش کرنا رہا ہے۔''(۷۱) امین مندرجہ بالا عبارت کو نقل کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہیں: ''شہرستانی کی طرح بہت سے مستشرقین کا نظریہ یہ تھا کہ اس دنیا کے متعلق اعراب کا زاویۂ نگاہ وسیع اور سب پر شامل نہیں ہے اور اصولاً اس دنیا کے متعلق اس طرح غور و خوض بھی نہیں کرسکتے تھے۔
فطری طورپر جبر کے رجحان نے ایسے ماحول میں ترقی کی اور اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ اسے وسعت بخشنے کے لئے کسی شخص کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایسے حالات میں اصولاً کوئی فکر کامیاب نہیں ہوسکتی جز جبر کے رجحان کے افکار کو مزید آگے بڑھانے اور نفوذ کے لئے کسی اور کو ایسا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کی طبیعت (ذہنیت) اور روحی اور نفسیاتی عمارت کا حال یہ ہے کہ وہ جز دلیل و برہان ہر شے کو ماننے کے لئے آمادہ ہیں اس لئے کہ عملاً ان کی عقلی فعالیتیں تحلیل کے لحاظ سے معطل ہوچکی ہیں۔ یہی وہ سبب ہے جو اشاعرہ، اہل حدیث، جبر کے طرفداروں اور عقل کو خطا جاننے والوں کی آخری کامیابی ہے۔ اس مسئلہ کے سیاسی اسباب کے حامل ہونے سے زیادہ، معاشرتی، نفسیاتی، ثقافتی اورتربیتی اسباب کا حامل تھا۔ انھیں اس دور میں یقینی کامیابی ملی جب موجودہ سیاسی حاکمیت ضعیف اور اس میں اختلاف ایجاد ہوچکا تھا اور حکومت افراتفری کا شکار تھی۔ ان کی کامل کامیابی کے حصول میں حکام کے اقتدار کی پشت پناہی یا تبلیغی اور دینی تسلط کے تحت ایسا اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سماج خود جبری فکر کا مالک اور جبر پسند تھا جس کی وجہ سے وہ عقل و ارادہ اور آزادی کے طرفداروں پر غالب آگئے اور اس میں جبر کی ترویج کرنے والے حکام کا کوئی دخل نہیں تھا۔
لیکن عین اس عالم میں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوران جاہلیت میں جبری رجحان کے قوانین اور اصول تدوین ہوکر رائج رہے ہوں یا ایک فلسفی اور کلامی مکتب کی شکل میں موجود رہا ہوں جیساکہ ہم نے بعد کی صدیوں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ موجود تھا۔ وہ ایک عمومی اور ایسا وسیع اور با نفوذ عقیدہ تھا۔ اس طرح سے اس نے عربوں کی نفسانی اور عقیدتی یہاں تک کہ ان کی معاشرتی اور سیاسی عمارت کو اثرانداز کردیا تھا اور اسی ماحول میں وہ لوگ پھلے پھولے اور پروان چڑھے تھے۔ البتہ یہ بھی اضافہ کرنا چاہئے کہ یہ عقیدہ اور طرزفکر ایک مدت کے لئے اس وقت کے سیاسی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے تحت الشعاع میں قرار پاکر بے چینی اور امیدوار کرنے والے ایام بھی تھے جس زمانے میں اسلام قدرت پاکر تیزی سے پھیلتا جارہا تھا اس وقتاپنا سکہ جمالیا۔ لیکن جب اسلام کی توسیع آہستہ آہستہ کم ہوگئی اور مائل بہ زوال ہو گیا اور دوسری قومیں اور ملتیںجدید بادشاہت میں اپنی جگہ بنالی تو اس فکر اور عقیدہ کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع ملا اور دوبارہ اس کے لئے حالات فراہم ہو گئے۔ مخصوصا ًیہ تازہ مسلمان اس کے میدان میں ایک خاص مہارت اور تجربہ اور منظم و مدون افکار و عقائد کے حامل تھے۔ اور یہ سب کچھ معاویہ کے بر سر اقتدار آتے ہی اور اس کی حکومت کے جڑ پکڑتے ہی شروع ہوگیا اور اسی مقام سے داستان کا سنجیدگی سے آغاز ہوجاتا ہے اس لئے کہ ایسی شروعات کے حالات مہیا ہوچکے تھے۔(۷۲)
حالات بھی پرسکون ہوچکے تھے اور فتوحات کا سلسلہ بھی ختم ہوگیا تھا اور عثمان اور حضرت علیـ کے زمانہ کا ناقابل ہضم اور سنگین تجربہ اور مسلمانوں کے درمیان کی جھڑپیں اور آپسی جنگیں موجود تھیں۔ یہی وہ دور ہے جس میں اہل کتاب اور دوسرے مذاہب کو موقع مل گیا ، تاکہ وہ لوگ اسلام کے اس جدید نظام میں اپنی حیثیت کو پھر سے پالیں اور اپنے عقائد کی تبلیغ و ترویج کا آغاز کردیں۔ زیادہ اہمیت کا حامل تو یہ ہے کہ معاویہ اور بنی امیہ کے برسر اقتدار آتے ہی زمانۂ جاہلیت کی میراث کو امکانی صورت میں دوبارہ احیا کرنے کا موقع مل گیا۔ اس لئے کہ عربوں کی بدوی اور جاہلی طبیعتیں بھی ایام جاہلی سے عمیق اور گہرا تعلق رکھتی تھیں اور وہ خود بھی اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لئے اس کو زندہ کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بیشتر عرب کے عوام الناس کے دلوں میں ان ایام سے محبت کی کچھ چنگاریاں باقی رہ گئیں تھیں اس حدتک کہ وہ زمانۂ جاہلیت سے عشق کرتے تھے۔(۷۳)
جبر کے رجحان کی تبلیغ
گویا اس دور میں جاہلیت کی میراث کے زندہ ہونے کے لئے تمام جہات سے حالات فراہم تھے مخصوصاً جبر و تقدیر کی طرف رجحان کو دوبارہ زندہ ہونے کا موقع فراہم ہوگیا اور عملی طور پر ایسا ہی ہوا۔ اس فکر نے فاتحانہ شان سے اپنے قدم آگے بڑھادیئے اور آہستہ آہستہ اس نے پورے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، البتہ اسے حکام کی جانب سے سرکاری طورپر حمایت بھی حاصل تھی۔ اگر اتفاق سے معاویہ اور بنی امیہ کی جانب سے منظم طورپر پشت پناہی بھی نہ ہوتی تب بھی اس دور کے مجموعی حالات پر توجہ کرتے ہوئے اسے اپنا راستہ بناہی لینا تھا۔ لیکن جب اسے حمایت اور پشت پناہی بھی مل گئی اور اس کے ساتھ ضمیمہ ہوگئی تو اس کا چوطرفہ قاہرانہ تسلط چھا گیا۔ اور سب سے بدتر تو یہ تھاکہ اس نے دینی اور قرآنی لباس پہن لیا اور اس لئے کہ یہ لباس ہر قسم کے عیب و نقص سے محفوظ ہوجائے، جعل و تحریف اور تاویل و تفسیرکا سلسلہ شروع ہوگیا اور جبری رجحان کی اصل کے مطابق اسلام اور قرآن کی ہماہنگ تصویر بنالی۔ اب اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا تھا کہ یہ تفکر قرآن کی تائید کے مطابق ہے، بلکہ زیادہ اہم یہ تھا کہ یہ کہہ دیا کہ بنیادی طورپر اسلام اور قرآن، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔(۷۴)
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعہ کس مقصود کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور وہ لوگ اس طرح سے پوری شدت کے ساتھ اس کی حمایت کیوں کرتے تھے۔ جیساکہ ہم پہلے بھی اس بات کو بیان کرچکے ہیں کہ وہ لوگ اس فکر کے مقابلہ میں، لوگوں سے سکوت اور اپنی اطاعت چاہتے تھیاور وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے تابع رہیں اور ان کے سامنے تنقید و اعتراض میں اپنی زبانیں نہ کھولیں۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے اور ایساکیوں نہیں کیا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ ظلم کیوں کر رہے ہو اور دین کو کیوںپائمال کررہے ہو؟ یہ نہ کہیں کہ کیوں حدود الٰہی کو پائمال کررہے ہو؟ اس کی حرمت پائمال کرنے والوں کو کیوں سزا نہیں دے جارہے ہو؟یہ اعتراض نہیں ہونا چاہئے کہ کیوں بیت المال کو تاراج کیا جارہا ہے ؟ اور اسے اپنی بولہوسی اور افسانوی عیش و نوش میں صرف کررہے ہو؟ اپنے حکام اور والیوں کے ظلم و ستم اور تجاوز و لاابالی گری سے ان کی روک تھام کیوں نہیں کررہے ہو؟ وہ مطلق العنان رہنا چاہتے تھے کہ بغیر کسی مانع اور رکاوٹ کے حکومت کریں۔ دیہاتی طبیعت، زمانۂ جاہلیت کی خصلتیں، بے حدثروتاور بے شمار رفاہ و آسائش لامحدود قدرت، بے پناہ شہوترانی کم ظرفیتی اور نفس کی حقارت نیز تمام سیر حاصل چوطرفہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی حس نے ان لوگوں کو اس حد تک مست کردیا تھا کہ ہوسرانی اور عیش و عشرت کے اسباب فراہم کرنے کے علاوہ وہ کچھ اور سوچ نہیں سکتے تھے۔ ایسے لوگ جن کے باپ دادا کی نظروں کو چند اونٹوں کے بار خیرہ کردیتے تھے اور یہی بات ان کو حسد کرنے پر آمادہ کردیتی تھی، آج وہی لوگ بزرگترین شہنشاہیت کے اہم لوگوں میں ہوگئے ہیں اور حکومت کے اہم عہدو ں پر فائز ہوگئے ہیں فطری طورپر ان لوگوں کے اعمال، کردار اور ان کی غیر فطری اور بیجا توقعات، توقع کے خلاف نہیں تھیں۔(۷۵)
وہ لوگ حاکم، خلیفہ یا گورنروں اور سرداروں سمیت کسی قید و بند کے بغیر کیسے آزادانہ حکمرانی کر یں۔ اس لئے کہ اس کو ایک طرف شرعی قوانین رکاوٹ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف سے عوام بھی انھیں احکام شرعی پر پابند رہنے کے لئے مجبور کرتی تھی۔ اس سے مقابلہ بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسلامی معاشرہ ایک جاہلی سماج نہیں تھا جو ہر قسم کے قانون اور ضابطہ سے بے نیاز ہو۔ بلکہ اس سماج میں اسلام موجود تھا جس کا وہ لوگ علانیہ طورپر انکار نہیں کرسکتے تھے۔ کیونکہ اسلامی قوانین کا انکار خود انھیں کے انکار کا باعث تھے۔ ہاں وہ لوگ قوانین کو پائمال کرسکتے تھے لیکن وہ لوگ اس کے اصل قوانین کا انکار نہیں کرسکتے تھے۔
ان کی نظر میں بہترین راہ حل جو نہ اسلام کے انکار کا سبب بنے اور نہ ہی ان کی آزادی، قدرت اور شہوترانی میں رکاوٹ کا باعث ہو، یہی سبب تھا جس کی وجہ سے جبر کے رجحان کی تبلیغ کی جائے اور وہ یہ کہیں کہ انسان کے پاس اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ مجبور مخلوق ہے اور وہ اپنی تقدیر بنانے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے اور اس میں کوئی دخالت کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اس کی تقدیر خدا کے اختیار میں ہے اور انسان کو اس کی زندگی میں جو کچھ بھی کو ملتا ہے وہ اسی کی جانب سے ہے اور اس کی مشیت کے تحت ہے۔ اس طرح اسی زمانۂ جاہلیت کے جبر کے رجحان کی فکر کی کا مسئلہ ٔجبر اسلامی کے رنگ میں ڈھال کر اس کی ترویج کی جارہی تھی بس فرق اتنا تھا کہ متعدد خداؤں کے مقام پر خدائے واحد یہ کردار ادا کر رہا تھا۔(۷۶)
اس تفسیر کے مطابق جو کچھ بھی انسان کو ملتاہے وہ سب کچھ اس کے ارادہ سے خارج اور مشیت خداوندعالم اور قادر مطلق کی مشیت کے مطابق ہے۔ وہ خواہ فطرت اور فطری حوادث سے ہو یا یہ چاہے حاکم یا خلیفہ یا کسی دوسرے انسان کی طرف سے ہو اہمیت کا حامل یہی آخری نکتہ ہے۔ یعنی جو کچھ حاکم کی جانب سے انجام پائے وہ تقدیر الٰہی ہے جو اس کے ذریعہ سے اپناوجود پاتا ہے لہٰذا اس میں تغییر اور اعتراض کے لئے زبان کھولنا ممکن نہیںہے۔ جیساکہ خود حاکم کا وجود بھی ایک تقدیر الٰہی ہے جس کو بدلا نہیں جاسکتا اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں لائی جاسکتی ۔ وہ مو جود ہے کیونکہ خداوندعالم نے ارادہ کیا ہے اور وہ قادر ہے اس لئے کہ خود خداوندعالم نے ایسا چاہا ہے۔(۷۷) بطور نمونہ عباسی خلفا میں سے دوسرے خلیفہ منصور کی تقریر کی طرف توجہ دیں۔ جسے اس نے اپنے مکہ کی مسافرتوں میں سے ایک مسافرت میں عوام سے اس طرح خطاب کیا: ''ائے لوگو! میں روئے زمین پر خدا کی طرف سے سلطان ہوں۔ جو اس کی بصیرت اور تائید و حمایت کے ذریعہ تم پر حکومت کررہا ہوں۔ اس کا خزانہ دار ہوں اور اسی کی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہوں اور اسی کے ارادہ کے مطابق تقسیم کرتا ہوں اور اسی کی اجازت سے عطا کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے اپنے خزانہ کا قفل بنایا ہے۔ لہٰذا جب تم پر بخشش کرنا چاہتا ہے تو مجھے کھول دیتا ہے اور جب روک دینا چاہتا ہے تو مجھے قفل کر دیتا ہے۔ لہٰذا خد ا کی طرف متوجہ ہوجاؤ اور اس مبارک دن کے صدقہ میں وہ تمھیں نعمتیںعطا کرے گا، جس کی اس نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: ''آج میں نے تمھارا دین کامل کردیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کردیں اور تمھارے لئے دین اسلام کو انتخاب کرلیا۔ '' اس سے چاہو کہ وہ مجھے صواب اور راہ ہدایت کی توفیق دے اور تم پر احسان و مہربانی کیلئے میرے دل میں الہام کرے اور مجھے عدل کے مطابق تمھارے درمیان روزی کی تقسیم کی توفیق عنایت کرے۔''(۷۸)
اس کاایک دوسرا نمونہ معاویہ کی بات ہے۔ اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة، نامی کتاب میں موجود ہے جو ایسے ہی مطالب سے پٹی پڑی ہے، اس (معاویہ) کے قول سے اس طرح نقل کرتا ہے: ''ہم بادشاہ لوگ زمانہ کی طرح ہیں۔ لہٰذا جسے چاہتے ہیں اسے سربلند کردیتے ہیں اور جسے نیچا کرنا چاہتے ہیں وہ پست ہوجاتا ہے۔'' اس وقت مؤلف معاویہ کے اس کلام کی تائید اور توضیح کیلئے اضافہ کرتے ہیں: ''معاویہ کے یہ کلمات اس کی بلند ہمتی اور کمال بزرگواری کی حکایت کرتے ہیں کہ بادشاہی کے عالم میں کامل الٰہی حمایت کی حامل ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بادشاہ لوگ خداوندعالم کے نائب اور اس کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے فرمان لوگوں کے اموال، خروج، کسی کی آزادی اور غلامی اور ان کے خون (قصاص و دیات) پر نافذ ہیں اور جو بھی عظیم مرتبہ اور شریف رتبہ کا خواہاں ہو تو اس پر لازم ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کرے اور اس کو قلباً بھی تسلیم کرے۔(۷۹)
اسی سلسلہ میں محمود صبحی اپنی کتاب نظریة الامامة، میں معاویہ کی سیاست کے متعلق اس طرح تحریر کرتے ہیں: ''معاویہ نے اپنی حکومت کے ارکان کو تنہا مادی قدرتوں کے سہارے مستحکم نہیں کیا، بلکہ اس نے اس راہ میں دینی عقائد کا بھی سہارا لیا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اس میں اور علیـ میں خلافت کے سلسلہ میں اختلاف تھا لہٰذا حکمیت کو خدا کے سپرد کردیا گیا اور خدا نے اسے علیـ پر برتری عطا کردی اور علیـ کو خلافت سے معزول کردیا اور مجھے خلیفہ بنادیا، اسی طرح جب اس نے اہل حجاز سے اپنے بیٹے یزید کے لئے بیعت لینا چاہی تو ان سے کہا کہ خلافت کے لئے یزید کا انتخاب قضاء الٰہی میں سے ایک ہے اور اس کے بندوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح نزدیک تھا کہ مسلمانوں کے اذہان میں یہ بات بیٹھ جائے کہ خلیفہ جو چاہے اور جس امر کا حکم دے اگرچہ وہ خدا کے دستور کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ خد اکی جانب سے اس کے بندوں کے حق میں قضا اور حتمی فیصلہ ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کردیا ہے۔
عثمان کے دور میں اپنی گورنری کے زمانہ میں معاویہ یہ بات صریحی طورپر کہتا تھا کہ بیت المال میں موجودہ مال و دولت خداوندعالم کا مال ہے اور مسلمانوں کا مال نہیں ہے۔ اور یہ اس وجہ سے تھا تاکہ انھیں خود اپنے لئے محفوظ کر سکے۔ بالکل اسی طرح جب اس نے اپنی حکومت کو قائم کرنے اور مستحکم بنانے کے لئے اور تفویض الٰہی کی فکر نیز بادشاہوں کے دینی حق ہونے کے ذریعہ مدد حاصل کی اور یہ مسلمانوں کی سیاست شرعی کی بہ نسبت بری طرح مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا۔ اس لئے کہ وہ چاہتا تھا دین کے نام پر جتنا ہوسکے اپنی ذاتی قدرت کو بڑھانے کے لئے فائدہ اٹھائے اور دینی عقائد کو حکام کے ہوا و ہوس کے تابع بنادے۔''(۸۰)
معاویہ اور اس کے جانشینوں کی بہت سے اسباب کے تحت کہ یقینا ان میں سے متعدد اسباب معاشرتی اور فکری حالات اور تاریخی سابقہ اور اس زمانہ کے لوگوں کی روحی عمارت کی طرف پلٹی ہے۔ ان کی کامیابی تنہا ان کے پرپیگنڈہ اور اقدام سے نہیں تھی بلکہ معاویہ اور اس کے ہم عقیدہ جس ہدف کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس وقت کے عرب عوام بھی واقعات اور مسائل بالکل ویسے ہی دیکھتے اور نیتجہ گیری کرتے تھے۔ ایسی طرز فکر کے نمونہ کو اس نظریہ میں جس کو حسن بصری نے حجاج بن یوسف کے متعلق اظہار کیا، اس کو بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ اہمیت کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے معاصر فقہا اور محدثین کی بہ نسبت ان لوگوں میں سے کہیں زیادہ گستاخ اور آزادی خواہ تھا۔ یہاں تک کہ معتزلی لوگ اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ اس نے اپنے دور کے حاکم کے جبری رجحان کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا اور اسی سلسلہ میں عبدالملک اور حجاج سے مکاتبات برقرار رکھااور دلیل پیش کرنے کے ضمن میں ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی، بعض قرآنی آیات کو اپنے مدعیٰ کے شاہد کے طورپر پیش کرکے جبرکو ثابت کرنے کے لئے مدد لی جارہی تھی ان کی دلیلوں کو رد کیا ہے۔(۸۱)
یہاں تک کہ وہ ایسا شخص ہے جس نے بارہا معاویہ پر اس کے برے اعمال کی وجہ سے، تنقید کی ہے۔(۸۲) لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کو حجاج جو ہر طرح کی جنایت کرنے سے اس کو کوئی باک نہیں ہوتا تھا، کے خلاف جنگ کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا: اور اس کی توجیہ اس طرح کرتا: ''اس سے جنگ نہ کرو اس لئے کہ اگر وہ عذاب الٰہی ہے تو عذاب الٰہی کو تم اپنی تلواروں سے دفع نہیں کرسکتے اور اگر خدا کی مصیبت ہے تو اس پر صبر کرو تاکہ خدا تمھارے اور اس کے درمیان حکومت کرے اس لئے کہ وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔''(۸۳) جب کہ وہ حجاج کو بدترین خلق خدا شمار کرتا تھا اور اس کے بارے میں اس طرح اظہار نظر کیا کرتا تھا: ''اگر ہر امت اپنے اشرار اور پست لوگوں کو ایک میدان میں لائیں اور ہم بھی حجاج کو اس میدان میں لائیں تو ہم اس رقابت میں جیت جائیں گے۔''(۸۴)
تاریخی شواہد (نمونے)
اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم بطور مثال چند تاریخی نمونے ذکر کریں۔
عاشورا کے خونیں واقعہ کے بعد جب اہل بیت حرم کو ابن زیاد کے دربار میں اسیر بناکر لے جایا گیا، اس دربار میں جناب زینب اور امام سجاد اور ابن زیادہ کے درمیان کچھ باتیں ردّوبدل ہوئیں جو ہماری اس بحث سے متعلق اور قابل تأمل اورقابل غور و خوض ہیں۔ ابن زیاد نے اشارہ سے امام سجادـ کے سلسلہ میں سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ علی ابن الحسین ہیں۔ اس (ابن زیاد) نے کہا کہ کیا وہ علی ابن الحسین نہیں تھے کہ جسے خدا نے قتل کردیا؟ امامـ نے فرمایا کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام بھی علی ابن الحسین تھا جسے تیرے لشکریوں نے اسے قتل کردیا۔ ابن زیاد نے کہا بلکہ اسے خدا نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر امامـ نے یہ آیت پڑھی۔(اَللّٰہُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِھَا) ''یعنی خدا وندعالم انسان کو جب اس کی موت کا وقت آجاتا ہے تو اسے موت دے دیتا ہے۔ '' یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہوگیا اور کہا کہ تم میں اتنی جرأت کہ میرا جواب دو اور میری بات ردّ کرو، (جلاد کو حکم دیا کہ) اس کی گردن مار دو۔ البتہ اس کے بعد کچھ نا خوش گوار واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا گیا۔(۸۵)
اسی قسم کی ایک بحث یزید کے دربار میں پیش آئی۔ یزید نے امامـ کو مخاطب کرکے کہا، اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے تمھارے باپ کو قتل کرڈالا۔ امامـ نے فرمایا کہ اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یزید نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو آپ کے قتل کا حکم جاری کردیا لیکن بعض اسباب کی بنا پر آپ کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کو اپنے نزدیک بلانے کا حکم دیا۔ جب آپ اس کے نزدیک پہنچے تو اس نے اس زنجیر کو کاٹنا شروع کردیا جو آپ کی گردن میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے ضمن میں یہ آیت پڑھی (ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر) ''لوگوں پر جو مصیبتیں وارد ہوتی ہیں وہ سب انھیں کے اعمال کا نتیجہ ہیں اور خدا تو بہت سی خطاؤں کو معاف کردیتا ہے۔ '' اس آیت کو سن کر امامـ نے فرمایا: نہیں، ایسا نہیں ہے یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں ہے جیساکہ تونے سوچ رکھا ہے بلکہ جو ہمارے سلسلہ میں ہے وہ یہ ہے: (ما اصابکم من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل نبرأ ھا لکیلا تأسوا علی مافاتکم ولاتفرحوا بما آتاکم) ''تم پر کوئی مصیبت وارد نہیں ہونے والی ہے، چاہے وہ مصیبت تم سے اور تمہاری جان سے متعلق ہو؛ ایسے حوادث جو باہر سے تم تک پہونچتے ہیں، مگر وہ چیزیں جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں جو نعمت تم سے اُٹھ گئی ہے اس کے بارے میں افسوس نہ کرو اور جو چیز تمہیں حاصل ہوگئی ہے اس پر شاد و خرم نہ ہوؤ۔'' اس کے بعد امامـ نے فرمایا کہ ہم ہیں وہ لوگ جو ایسی صفات کے مالک ہیں۔(۸۶)
کیا اس کے علاوہ تھا جو یہ دونوں کہنا چاہتے تھے : امام حسینـ اور آپ کے اصحاب پر جو مصیبتیں بھی نازل ہوئیں وہ سب خد اکی طرف سے تھیں اس میںحاکم کی کوئی دخالت نہیں تھی؟ اور حاکم تو صرف خداوند عالم کے ارادہ کو وجود میں لانے کا سبب رہا ہے۔ یہ ابن زیاد، یزید اور اس کے فوجیوں نے امامـ کو شھید نہیں کیا فقط خداوند عالم نے انھیں قتل کیا ہے اور خدا نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی انھیں کے اقدامات کا نتیجہ تھا اور وہ لوگ انھیں سزاؤں کے مستحق تھے۔ یہاں پر اہمیت کا حامل یہ تھا کہ حاکم پوری طرح اس جرم سے بری نظر آرہا تھا، ساری ذمہ داریاں خدا کے دوش پر پلٹ رہی تھیں اور اس میں حاکم کا کوئی اپنا کردار اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔
اور اس طرح سے حاکم اختیار، قدرت اور اپنے آپ کو بالکل محفوظ پارہا تھا اس لئے کہ اس کے تمام اعمال و کردار اور اسوہ اور اقدامات خداوندعالم کے ارادہ کی تجلی اور اس کے مظا ہر تھے لہٰذا ا نہیں نہ بدلا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس پر اعتراض کیا جاسکتا تھا۔ یہ امویوں کے نظریات کی تفسیر تھی۔ اس لئے کہ نہ تو وہ دین کا انکار کرسکتے تھے اور نہ ہی ان کا یہ انکار نہ کرنا ان کی آزادی کو سلب کرتا تھا۔ انھیں قدرت، آزادی عمل اور نامحدود اختیار چاہیئے تھا انھیں دینی شان وحیثیت اور احترام وغیرہ سب کچھ اس تفسیر کے سایہ میں حاصل ہورہا تھا۔
اموی لوگ قاعدتاً اسی فکر کی بنیاد پر سوچتے، اپنی زندگی، حکومت اورا س کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان کی پوری خلافت کا زمانہ اسی قسم کے حوادث اور نمونوں سے بھرا پڑا ہے۔ جب معاویہ مر گیا تو یزید نے مدینہ کے گورنر (حاکم) کو لکھا: ''معاویہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ خداوندعالم نے اسے کرامت عطا کی اور اپنا جانشین بنادیا اور لوگوں کے امور کو اس کے حوالہ کردیا اور اسے قدرت و مقام اور سیادت بخشی۔(۸۷) اسی طرح سے خود معاویہ بھی ان لوگوں کے اعتراض کے جواب میں جو لوگ یزید کی جانشینی کے مخالف تھے ان سے کہا: ''یہ خدا کا ملک اور اس کی سلطنت ہے اور وہ جسے چاہے عطا کرے۔ یزید کی ولایت عہدی کو خداوندعالم نے مقدر فرمایا ہے اور تقدیرات الٰہی میں سے ہے اور تمہیں چوں و چرا اور اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔''(۸۸)
ان لوگوں کے گورنر بھی اسی روش کے مطابق خطبہ دیتے اور تبلیغ کرتے تھے۔ ایک روز ابن زیاد نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: ''ائے لوگو! ہم توتمھارے رؤسا ہیں اور ہم ہی تم سے بلاؤں کو دفع کرتے ہیں۔ ہم خدا کی دی ہوئی قدرت سے حکومت کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی عطا جو اس نے ہمارے اختیار میں قرار دی ہے اس سے تمہارے لئے بخشش کرتے ہیں۔ ہماری اطاعت تم لوگوں پر واجب ہے اور جو ہم پسند کرتے ہیں ویسے ہی تم عمل کرو، ہم تمھارے ساتھ عدل کے مطابق حکم کریں گے۔ پس اپنی اطاعت و نصیحت اور ہمکاری کے ذریعہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ہماری عدالت کے مشمول اور مستحق بناؤ۔''(۸۹) اسی طرزفکر کے ترقی یافتہ نمونہ کو قرآن و حدیث کے بہت سے عناصر کو اپنے اندر سموئے ہوئے مطالب کو جسے یزید ابن عبدالملک کے تفصیلی وصیت نامہ میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جسے اس نے اپنے دوبیٹوں کی ولایت عہدی کے سلسلہ میں لکھا تھا۔(۹۰)
جعل حدیث
اسی طرزفکر کی بنیاد پر ''یعنی جو کچھ بھی حاکم انجام دیتا ہے، وہی خداوندعالم کی جانب سے تقدیر ہے'' بہت زیادہ مقدار میں حدیثیں گڑھی گئیں۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے کہ اگر اس نے صحیح عمل کیا تو اسے اجر ملے گا اور تمھیں شکر گذار رہنا چاہیئے اور اگر اس نے صحیح عمل نہیں کیا تو اس کے گناہوں کا بوجھ اسی کے سر پر ہے اور تجھے صبر کرنا ہوگا یا اگر یہ کہ حاکم کی جانب سے تمہیں کوئی اذیت پہنچے تو اس کے مقابل میں صبر کرو اور اس کی بیعت نہ توڑو اس لئے کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی طرف نسبت دے ڈالی کہ آپ نے فرمایا: ''میرے بعد ایسے حکام آئیں گے جو میری ہدایت پر نہ ہوں گے اور میرے طریقہ پر نہیں چلیں گے یعنی میری سنت کو نہیں اپنائیں گے، وہ اپنے سینوں میں شیطانوں کے ایسے دلوں کو انسانی جسم میں حمل کرتے ہوں گے لیکن وہ شیاطین کے قلوب جیسے ہوں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم ان کے مقابلہ میں کیا کریں؟ آپصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا: نہیں، ان کے فرامین کو کان دھرکے سنو اور ان کی اطاعت کرو اس لئے کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے اگرچہ وہ تم پر تازیانہ ہی کیوں نہ برسائیں اور تمھارے اموال کو غصب ہی کیوں نہ کرلیں۔ آخرکار یہ کہیں گے کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے فرمایا کہ ہر حاکم کی اطاعت کرنا اس لئے کہ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے آپ بطور نمونہ کتاب الامارة؛ کنزالعمال، میں رجوع کرسکتے ہیں قابل توجہ بات تو یہ ہے کہ اس باب میں جتنی احادیث بھی مذکور ہیں وہ سب کے سب ایسے مطالب پر مشتمل ہیں۔(۹۱)
جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ وہ اصلی محرک جو اس بات کا موجب ہوا کہ ایسی بے شمار احادیث گڑھی جائیں وہ یہی جبری رجحان کے متعلق تفکر تھا اور یہ کہ خود حاکم اور اس کے اعمال و کردار خدا کی تقدیر ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحبان اقتدار اتنے پر بھی قانع نہ تھے اور اسے اپنی حاکمیت کو مستحکم بنانے کے لئے کافی نہیں سمجھتے تھے۔ لہٰذا بہت ساری جھوٹی احادیث گڑھ ڈالیں اور یہ حدیثیں وجود میں آئیںکہ کسی بھی صورت میں بیعت کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ جو اپنے امیر کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ وہ جیسا بھی ہو خواہ اچھا ہو یا برا، عادل ہو یا فاجر، اس کے پیچھے نماز ادا کرو اور اس کے دستور کے سامنے گردن جھکادو۔ انھیںبرا بھلا نہ کہو کہ انھیں برا کہنا مجھے برا کہنے کے برابر ہے۔ ان لوگوں نے نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کردی تو کسی اعتراض کے بغیر نماز میں ان کی اقتدا کرو، حاکم کے خلاف خروج کرنے کی فکر کو ذہن سے نکال دینا اورجو بھی ایسا کرے گا وہ دین سے خارج ہوجائے گا۔ اور جو بھی حاکم کے خلاف قیام کرے گا اس کی گردن مار دو۔ جو بھی مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بنے اسے قتل کردو۔ ہر صورت میں، خواہ رضایت کے ساتھ ہو یا اکراہ کے ساتھ، اپنے حاکم کی اطاعت کرو۔ اقتدار کی خاطر ان سے مقابلہ کے لئے قیام نہ کرو۔ ہر وہ قوم جو سلطان کو ذلیل کرنا چاہے تو خداوندعالم اس کو اس دنیا میں ذلیل کرے گا اور ہر وہ شخص جو کسی امیر کے ہوتے ہوئے لوگوںکو اپنی طرف دعوت دے تو اس پرخدا، ملائکہ اور لوگوں کی لعنت ہو اور ایسے شخص کی گردن ماردو۔(۹۲)
یہ بھی جبر ہی کے رواج دینے کی امویوں کی ایک داستان تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حاکم کو ایک ایسی موقعیت عطا کردیں جہاں پر وہ ہر قسم کی تنقیدوں سے محفوظ رہے، واقعیت تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس ہدف میں کامیاب بھی ہوگئے ان لوگوں نے اس راہ میں اس قدر سعی و تلاش کی کہ بعد میں اس طرح معروف ہوگیا ''الجبر و التشبیہ امویان و العدل و التوحید علویان'' یعنی اموی وہ لوگ ہیں جبر و تشبیہ کے مروج، طرفدار اور اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور علوی وہ لوگ ہیں جو عدل و توحید کے داعی ہیں۔ در حد امکان ائمہ(ع) اندھا مفلوج، بے حرکت اور بے حس بنا دینے والے جبری رجحان کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے اور اس سے مقابلہ کیا لیکن متعدد اسباب کے تحت جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے اس کو وسعت ملی اس فکر نے اپنی جگہ بنالی اور حاکم کے متعلق اہل سنت کے تفکر کو بنانے میں بنیادی حصہ حاصل کرلیا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اہل سنت نے بعد میں جبر کے متعلق ان مبلغین کی تفسیر کو مان لیا۔ پھر بھی یہ بات ان کے حق میں ایک حدتک صحیح ہے لیکن اس مقام پر یہ نکتہ تھا کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظریہ ایسی فکر سے متاثر ہوکر پھلا پھولا اور یہ مورد قبول قرار پایا۔(۹۳)
یہ احادیث اگرچہ جبری رجحان کے موضوع کے ساتھ امویوں کی مستقیماً تبلیغ و ترویج اور حمایت حاصل نہیں تھی لیکن اس کے برے اثرات کا نتیجہ ضرور تھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ قوی اور اسے مستحکم بنانے کی خاطر گڑھی گئیں تھیں۔ یہ احادیث حاکم کے اقدامات اور اس کے اوامر کے متعلق تھیں جو الٰہی مشیت اور اس کے ارادہ کے متعلق ہونے پر دلالت کرتی تھیں، درحقیقت یہ احادیث حاکم کو ایک ایسے مقام پر پہنچانا چاہتی تھیں جس کے بعد وہ ہر قسم کے نقصان اور تنقید سے محفوظ کررہا تھا، اس کے بغیر کہ اس کے لئے دینی شان اور منزلت کو بتانے کی کوئی ضرورت پڑے تا کہ اس طرح اس کے سایہ میں اس کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھا جاسکے۔ اور وہ احادیث جو حاکم کی اطاعت کے وجوب اور اس کے خلاف قیام یا بیعت کے توڑنے کی حرمت پر دلالت کرتی تھیں در حقیقت وہ بھی اس خدشہ ناپذیر حیثیت کو باقی رکھنے اور ہر قسم کی تنقید سے بری اور محفوظ تھیں۔
اہل سنت کے تمام فقہا اور محدثین اور متکلمین، علما حاکم کے متعلق اسی زاویہ سے فکر کیا کرتے تھے اور اسی کی بنیاد پر ان لوگوں نے اس کی اطاعت کے وجوب اور اس کی مخالفت کی حرمت اور اس کے حدود و اختیارات کے متعلق تعریف اور تحلیل و تجزیہ کیا۔ ان لوگوں کے کلام کا لب لباب یہ تھا کہ خود حاکم، ہونے کے عنوان سے کہ وہ کون ہے اور کیسے قدرت کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے عقائد کیا ہیں اور وہ عمل کیسے کرتا ہے؟ وہ بھی مشروعیت رکھتا اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس لئے کہ اس کاحضور اور اس کی قدرت ایک واقعیت ہے اور یہ خدا کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے جس نے اسے ایک واقعیت میں متجلی کردیا ہے۔(۹۴)
اگرچہ اہل سنت کے متکلمیناور ان کے بزرگ فقہا اور علما کے درمیان ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے، جن کے نظریات حاکم کے متعلق ایسے نہ تھے یعنی مثال کے طورپر حاکم میں عدالت، دینداری، شجاعت، سیاست، ذہانت، قرشی ہونا، یہاں تک کہ مجتہد ہونے کی شرط کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ لیکن اولاً ایسے لوگ اقلیت میں تھے اور دوسرے یہ کہ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات فراموشی کے حوالہ کردیئے گئے اسی طرح کہ جیسے معتزلہ کا کوئی نام نشان نہیں بچا اور ان کے عقائد اور افکار اشعریوں اور سلفیوں کے خشک عقائد کے تحت الشعاع قرار پاگئے۔ ایسے متکلمین اور فقہا کا ایک گروہ ان کے ہم فکر آزاد فکر معتزلیوں کی طرح ابتدائی صدیوں کے شکوفائی اور ترقی کے زمانہ اور تمدن اسلامی کے عقلانی دور میں معروف ہوگئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناپید ہوگئے۔ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ ان کے افکار نہ تو خود انھیں کے دور میں اور نہ ان کے بعد والے ادوار میں بدرجہ اولیٰ بے توجہی کا شکار ہوگئے، نہ ہی ان کے افکار کو فقہی و کلامی یا سیاسی و معاشرتی حیثیت مل سکی اور نہ ہی اہل سنت کے دینی (سیاسی) عقائد کا حصہ نہ بن سکے۔ بلکہ جس چیز کو حاکمیت حاصل تھی اور کلیدی حیثیت کی حامل تھی وہ وہی عمومی فکر تھی جس نے تاریخ اسلام کو وجود بخشا اور اب بھی تمام تغیرات کے باوجود قائم ہے اور فعالانہ طور پر عمل کررہا ہے۔
مرجئہ کی فکر
اس مقام پر دوسرا عامل ایک ایسی فکر تھی جو امویوں کی حکومت کے وسط میں ظاہر ہو ئی اور بڑی ہی تیزی سے ترقی پاکر پھیلی چلی گئی اور وہ مرجئہ کی فکر تھی۔ یہ کہ تفکر کیوں وجود میں آیا اور کیسے پھیل گیا، یہ خود ایک مستقل بحث ہے۔ لیکن جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ امویوں نے بڑی بے صبری سے اس (تفکر) کا استقبال کیا اور وسعت اور رواج دینے کی سعی و تلاش کی اور اس سے بہت زیادہ فائدے اُٹھائے۔(۹۵)
مرجئہ کی فکر در اصل خوارج کے شدت پسند طرز فکر کے مقابلہ میں عکس العمل کے طورپر وجود میں آئی جو اس بات کے قائل تھے کہ گناہ صغیرہ کا مرتکب بھی کافر ہے اور اس کا قتل بھی واجب ہے۔ خوارج کی یہ شدت پسندی ایک طرح کی اباحہ گری کا موجب بنی جو اس بات کا عقیدہ رکھتی تھی کہ ایسا عمل ایمان کو نقصان نہیں پہونچا سکتا۔(۹۶) لوگوں کی نیکیوں یا برائیوں کو ان کے اعمال و کردار کی بنیاد پر اس کے سلسلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اہمیت کا حامل یہ ہے کہ وہ شخص باایمان ہو۔ لیکن یہ کہ اس کے اعمال کیسے ہیں؟ نہ تو اہمیت کے حامل ہیں اور نہ ہی اس دنیا میں افراد کو اس معیار پر پرکھنے کے قابل ہیں۔ نہ ہی ان کا مواخذہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ عقیدہ ایک طرح سے اعتقادی اور دینی توجیہ اور پناہ کی حیثیت رکھتا تھا تاکہ اس کے ذریعہ ہر قسم کی معصیت اور بے بندوباری سے توجیہ کے ذریعہ اپنے آپ کو ان سے بچایا جاسکے۔ لہٰذا یہ لاابالی لوگوں کے لئے مطلوب ہے اور اس دور کے معصیت کاروں کے حق میں تھا جو اس زمانہ کی اکثریت میں تھے؛ یہی دوران جاہلیت کی میراث کے مطابق اور اس کے موافق بھی تھا۔ ایسی میراث اب بھی اپنی قدرت اور پورے تسلط کے ساتھ پابرجا اور باقی تھی۔(۹۷)
دوران جاہلیت کی خصوصیا ت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس دور کے لوگ ہر قسم کی قید و بند اور قانون و ضابطہ سے دور بھاگ رہے تھے۔ دور جاہلیت کی ثقافت آزاد ثقافت اور ہر قسم کے قانون اور ضوابط سے دور تھی۔ زیادہ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ہر چیز کو مباح اور ہر قید وبند سے آزادی کی ثقافت خاص طورپر شہوت کی ثقافت حاکم تھی۔ اس دور کے حالات بھی اسی قسم کی خصوصیات کو پسند کرتے تھے اور موجودہ شواہد بھی اسی امر پر دلالت کرتے ہیں اور اسلام ان خصوصیات کا چوطرفہ مخالف اور اس کا مخالف تھا۔ اگرچہ دین اسلام نے اہم تبدیلیاں پیدا کیں، لیکن وہ ثقافت جنھوں نے اپنی اولاد کو انھیں خصوصیات اور ان کے پسندیدہ نظام کے مطابق ان کو پروان چڑھایا تھا اتنا ہی طاقتور، زیادہ اثر انداز اور اس کے کہیں زیادہ دیرپا اثرات تھے اوراتنی جلدی آسانی سے ممکن نہ تھا کہ اپنے مخالف کے حق میں میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ اگرچہ وہ اس قدر قوی بھی نہ تھے کہ دین کا انکار کردیتے اور خود دوبارہ حاکم بن بیٹھتے۔ لیکن کم سے کم اتنا ضرور تھا کہ وہ دین کے لباس کو اتار کر پہلے ہی کے مانند اپنی (اسی جاہلیت کے اصول پر) زندگی گذارے اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔(۹۸)
شہوت پرست اعراب کی شہوانی فطرت، حدود و قیود اور پابندی سے گریزاں رہنا، وسیع پیمانہ پر رفاہ جیتی ہوئی زمینوں کی بے انتہا دولت و ثروت، اس کی خوبصورت کنیزیں اور بڑی تعداد میں اسیر بنائے ہوئے غلام عیاشی کے نئے نئے آلات جو اس سے پہلے قابل تصور بھی نہ تھے، مجموعی طور سے حالات ایسے بنا دیئے گئے تھے،(۹۹) خود وہ لوگ کسی ایسے سہارے کی تلاش میں تھے تاکہ اس کی مدد کے ذریعہ اپنے باطنی اور وجدانی دباؤ کو کم کردیں اور کوئی عذر شرعی تلاش لیں اور وہ اپنی عیاشی میں مشغول ہوجائیں۔ اور واقعیت تو یہ ہے کہ لوگوں کا لاابالی گری اور ہر قسم کی قید سے آزادی اور عیاشی امویوں کے دور میں خود امویوں سے کم نہ تھی۔ نمونہ کے لئے آپ کتاب الاغانی میں رجوع کرسکتے ہیں۔(۱۰۰)
زمانۂ جاہلیت کی طبیعت، اس دور کی روحی اور نفسانی تشنگی اور اسی طرح معاشرتی اور ثقافتی حالات مرجئہ کی فکر یعنی بے بند باری کی فکر کو طلب کررہی تھی۔ اسی وجہ سے جب یہ تفکر وجود میں آیا تو لوگ ماہی بے آب کی طرح اس کی طرف ٹوٹ پڑے البتہ خود اموی لوگ بھی انھیں حالات کو دو اسباب کے تحت پسند کرتے تھے۔ اس لئے کہ اولاً: یہ تفکر شہوترانی اور خواہشات نفسانی کے مطابق تھا اور جب عوام حلال طلبی اور عیش و نوش کی بدولت دینی اور اخلاقی پابندیوں سے منھ موڑ کر اپنی انتخاب کی ہوئی ڈگر میں چل پڑے تو اس صورت میں کوئی بھی دوسرا شخص ان پر تنقید نہیں کرسکتا تھا۔ دوسرے: اس اصل کے مطابق جو کہتا ہے کہ عمل اور کردار ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتا، یہ اصل انھیں بچالیتی تھی، اس لئے کہ اس کی مدد سے وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر حاکم یا اس کے والی خود حاکم سے عیاشی میں ان کے آدھا بھی نہیں تھے۔ ان کے حکام ان لوگوں سے زیادہ لاابالی اور بے بند وبار تھے اور فسق و فجور میں مبتلا ہوں، شراب پیتے ہوں، ظلم و ستم کرتے ہوں، تعدی و تجاوز کرتے ہوں تو اس کے لئے یہ اعمال اتنے اہم نہیں ہیں اہمیت کا حامل تو صرف ایمان ہے اور اس کے اعمال اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اسے یہ اعمال نہ تنہا دین سے خارج نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان و معنویت کے مرتبہ کو بھی کم نہیں کرسکتے۔ اس طرح بڑی ہی آسانی سے اپنے تنقید کرنے والوں کو افکار عمومی کے مقابلہ میں نہتھا کردیں گے۔ اس لئے کہ آخرش ان کے کلام کا لب لباب یہ تھاکہ یہ لوگ ایسے اعمال کے ارتکاب سے اپنے ایمان و تقوی کو کھوبیٹھتے ہیں اور اس طرح حاکمیت کی صلاحیت اور شائستگی کو بھی کھو بیٹھیں گے۔(۱۰۱)
بہرحال یہ مسلم ہے کہ اس طرزفکر کو امویوں کی طرف سے حمایت اور تشویق حاصل رہی ہے اور حاکم کو شرعی اور قانونی حیثیت دینے اور اس کو محفوظ کرنے، جو حاکم کو مستحکم بنانے اور ہر قسم کی تنقید سے روک دیتا ہے، کم از کم امویوں کے دوسرے دور میں حائز اہمیت کردار ادا کیا ہے۔ البتہ جیساکہ اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اس درمیان دوسرے عوامل بھی دخیل رہے ہیں کہ ہم ان کے بیان سے صرف نظر کرتے ہیں۔
تیسری فصل کے حوالے
(۱)ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں کہ بنی امیہ کے کچھ لوگ ایک ساتھ ہوکر معاویہ کے پاس گئے اور اس سے کہا: ''اے امیر المؤمنین! تمہیں جو چاہیئے تھا وہ حاصل کرلیا۔ لیکن ابھی تک کیوں اس مرد (حضرت امام علی ابن ابی طالب) پر لعنت کرنے سے باز نہیں آتے؟ معاویہ نے جواب میں کہا: خد اکی قسم میں اس وقت تک اپنے اس عمل سے دست بردار نہیں ہوں گا جب تک کہ بچے اسی لعنت پر بزرگ نہ ہوجائیں اور بزرگ لوگ اسی پر بوڑھے نہ ہوجائیں اور کوئی بھی ذاکر اس کی ایک بھی فضیلت کو بھی نقل نہ کرے۔'' النص والاجتھاد، کے ص۴۹۹ پرجو شرح ابن ابی الحدید، کی ج۱، ص۴۶۳ سے منقول ہے۔ اسی مطلب کو ابوجعفر اسکافی کے کلام سے مقائسہ کریں کہ اس نے کہا: ''اگر خد اکی خاص توجہ اس مرد (حضرت امام علیـ) کے ساتھ نہ ہوتی تو جو کچھ بنی امیہ اور بنی مروان نے اس کے خلاف انجام دیا ہے، ان کی فضیلت میں ایک حدیث بھی باقی نہیں بچتی۔ '' دوسرے نمونوں کو حاصل کرنے کے لئے شرح ابن ابی الحدید، کی ج۴، ص۵۶۔ ۱۱۶، پر رجوع کریں۔
(۲)گولڈزیہر نقل کرتاہے: اموی لوگ نماز عید کے خطبہ کو نماز پر مقدم کرتے تھے تاکہ لوگوں کے متفرق ہونے سے پہلے ان کے کلام کو سن لیں اور اس کے بعد مزید اضافہ کرتا ہے وہ لوگ نماز پڑھ کر مسجد کو ترک کر دیتے تھے تاکہ وہ خطبے جو حب اور حضرت امام علیـ کی لعنت کے سلسلہ میں ہوتا تھا اسے نہ سنیں۔
Goldziher, Muslim Studies, Vol.۲nd, P.۵۱
(۳)اس سلسلہ میں مخصوصاً آپ الاسلام واصول الحکم، نامی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ جس میں اس واقعہ کی بخوبی تحلیل و تجزیہ اور تنقید بھی کی گئی ہے۔ ص۱۱۳۔ ۱۳۶، ۱۸۰۔ ۱۸۲۔
(۴)اموی لوگ عباسیوں کے بر خلاف نہ تو دین کے ضرورت مند تھے اور نہ تو اس کا تظاہر ہی کرتے تھے۔ تربیت اور ان کے نفسیات، عادات اور ان کے اخلاقیات زیادہ تر جاہلیت اور بدویت سے تال میل کھاتے تھے، ان کا کردار بھی اسی کے مطابق تھا۔ ان لوگوں کی سیاست بیشتر ایک قبیلہ کے سردار سے میل کھاتی تھی نہ کہ خلیفہ اور ایک بڑی سلطنت کے بادشاہ سے۔ یہی وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی تیزی سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ معاویہ جو دوسروں سے زیادہ حفظ ظاہر کی رعایت کرتا تھا وہ خود کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: ''میرا ہدف تم لوگوں پر حکومت کرنا ہے اور مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ تمھیں نماز کے لئے آمادہ کروں اور زکاة کے لئے ابھاروں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایسا ہی کرتے ہو۔ '' الامویون والخلافة، کے ص۱۳، یا یہ کہ عبدالملک آشکارا کہا کرتا تھا: ''ائے لوگو! راہ مستقیم پر آجاؤ اور اپنی ہواء و ہوس کو چھوڑ دو اور تفرقہ سے پرہیز کرو اور ہمیں مسلسل مہاجرین اولین کی طرح اعمال انجام دینے کے لئے نہ کہو اور تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں کی روش اور کردار کیا تھا...'' الامویون والخلافة، کے ص۱۲۲۔
لیکن عباسی (خلفا) لوگ ایسے نہ تھے ان کی ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ جہاں تک ہوسکے دین کے احکامات پر پابند رہنے کا دکھاوا کریں، ''عباسیوں کے دور خلافت کا ابتدائی حصہ دینی رنگ لئے ہوئے تھا، تاکہ اس طرح وہ لوگوں کے درمیان ان کی دینی عظمت میں اضافہ ہوجائے۔ یہ روش منصور کے زمانہ میں شدید ہوگئی تھی، اس لئے کہ اس دور میں ان لوگوں کی کمی نہیں تھی جن لوگوں نے اس کے خلاف قیام کیا...'' مبادی نظام الحکم فی الاسلام، ص۵۸۴۔ امویوں کی جاہلی تعصب کا ایک نمونہ یہ ہے: ''اموی خلفا اس شخص کی بیعت کو پسند نہیں کرتے تھے جس کی ماں کنیز رہ چکی ہو۔ '' تاریخ ابن عساکر، ج۵، ص۲۰۶۔ یا یہ کہ ابن ابی الحدید یہ کہتا ہے: ''امویوں کے یہاں یہ مشہور تھا کہ ان کا آخری خلیفہ وہ ہے جس کی ماں کنیز ہو۔ اسی وجہ سے خلافت کو ایسے شخص کے حوالہ نہیں کرتے تھے۔ اس لئے کہ اگر قرار یہی ہوتا تو پھر مسلمة بن عبد الملک ان میں سے سب سے بہتر ہوتا۔ '' شرح ابن ابی الحدید، کی ج۷، ص۱۵۷، پر رجوع کریں۔ اور اسی طرح الامویون والخلافة، نامی کتاب کے ص۴۵، پر رجوع کریں۔ فجر الاسلام، ص۹۱۔
عباسیوں کی روش بالکل اس کے بر عکس تھی اور عباسی لوگ صرف موالیوں (کنیزوں) سے شادی کرتے تھے۔ ۸۰۰ئ کے بعد کوئی ایسا خلیفہ ہوا ہی نہیں جو کسی آزاد عورت سے پیدا ہوا ہو۔
G. F. Grunebaum, Classical Islam, P.۸۰. Goldziher, Muslim Studies, Vol ۲nd PP.۳۸-۸۸
عباسیوں اور امویوں کی سیاست اور ان کی روش کے اختلاف کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے آپ مذکورہ کتاب کے ص۸۹۔ ۸۰، پر خاص طور سے رجوع کریں:
(۵)البیان والتبیین، ج۲، ص۱۰۲۔ ۱۰۳۔
(۶)صدر اسلام کے متعلق شیعوں کے تنقیدی نظریات کی محکومیت کو معلوم کرنے کے لئے آپ کتاب السنة مؤلفۂ بر بہاری، طبقات الحنابلہ، کی ج۲، ص۱۸۔ ۴۵ پر رجوع کریں۔
(۷)تحول و ثبات، ص۸۷۔ ۱۰۰۔
(۸)نظریة الامامة لدی الشیعة الامامیة، ص۳۱۹ اور ۳۲۰۔
(۹)سابق حوالہ، ص۳۲۱۔
(۱۰)مثلا مقریزی جو صدرا سلام اور اس کے بعد والی صدیوں کے حوادث کی تاریخ اور اس ثقافت کے متعلق مطلع ترین افراد میں سے شمار کئے جاتے ہیں وہ ہر اس عبارت کو رد کرتے ہیں جس میں صحابہ کرام نے آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم سے قضا و قدر، صفات خدا یا آیات متشابہ کے سلسلہ میں سوال کیا گیا ہے، ان کی نظر میں وہ سب روایات جعلی اور وضع کی گئی ہیں اس لئے کہ رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم سے صرف عبادات اور اس کی کیفیات کے سلسلہ میں سوال کیا جاتا تھا۔ خطط مقریزی، ج۴، ص۱۸۰، پر رجوع کریں۔ اسی نظریہ کے نقد کو معلوم کرنے کے لئے کتاب النظم الاسلامیة، کے ص۷۴۔ ۷۷، پر ملاحظہ کریں۔
(۱۱)اعلام الموقعین، ج۴، ص۱۱۸۔ ۱۵۶ جس میں اصحاب اور تابعین کی اتباع کے وجوب کے سلسلہ میں سیرحاصل بحث کی گئی ہے اور آپ اسی طرح کتاب تراث الخلافة الراشدین کے ص۱۴ اور ۱۵، پر بھی رجوع کرسکتے بر بہاری اپنی کتاب السنة ابن حنبلکی شرح میں صحابہ کے اتباع کے وجوب کے باب میں بیان کرتے ہیں: ''جان لو کہ دین تقلید ہے۔ تقلید بھی اصحاب پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی... پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم نے اپنے اصحاب سے خطاب کرکے فرمایا: تم میں سے وہ لوگ جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات کا مشاہدہ کریں گے لہٰذا خبردار! کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انھیں جدید اور حادث امور میں گرفتار ہوجاؤ کہ اس میں گرفتار ہونا ضلالت ہے۔ تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفا ئے راشدین کی اطاعت کرو۔ جو کتاب طبقات الحنابلة، کی ج۲، ص۲۹ سے منقول ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر کہتے ہیں: ''خدارا! خدارا! اپنے نفس کو بچائے رکھنا، صحابہ اور سلف صالح کے آثار کی اتباع تم پر واجب ہے۔ اور ان کی تقلید بھی تم پر لازم ہے، اس لئے کہ دین خود تقلید کا نام ہے۔ رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم اور ان کے صحابہ کی تقلید۔ جو انھیں قبول کرلے گا وہ غلطی میں نہیں پڑے گااور ان لوگوں کے بعد ان کی تقلید کرنا اور سکون و چین کا سانس لینا اور اس (تقلید) سے تجاوز نہ کرنا۔'' سابق حوالہ، ص۳۹۔ ایک اور مقام پر اس سے زیادہ واضح انداز میں کہتے ہیں: ''اگر تم نے یہ سنا کہ کوئی شخص رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم اور صحابہ سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس پر طعنہ کر رہا ہے اور اسے قبول نہیں کرتا یا پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی اخبار میں سے کسی خبر کا انکار کررہا ہے، اس کے اسلام کو متہم (مشکوک) جانو۔ اس لئے کہ وہ بے دین انسان ہے اور ااس نے رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم اور صحابہ کو برا بھلا کہا اور ان پر طعنہ کئے ہیں۔ کیونکہ ہم نے خدا و رسول، قرآن، خیر و شراور دنیا و آخرت کو گذشتگان کے آثار کے ذریعہ ہی پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اضافہ کرتا ہے: ''قرآن زیادہ محتاج ہے سنت کا قرآن کی نسبت احتیاج کے مقابلہ میں، سابق حوالہ، ص۴۵۔
(۱۲)الفتاوی الحدیثة، ص۳۰۵۔ عبداللہ ابن مبارک کے سلسلہ میں ایسے ہی نظریہ کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی شخصیت اور خصوصیات کے لئے آپ، الاسلام بین العلما والحکام، ص۲۲۸ اور ۲۲۹۔
(۱۳)طبقات الحنابلة، ج۲، ص۲۱۔
(۱۴)اس نظریہ کی تنقید کے با ب میں کہ اصحاب پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کے درمیان قطعاً منافق اور فاسق بھی موجود تھے اور یہاں تک کہ بعض ایسے بھی تھے جن پر خود رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم نے لعنت کی تھی، اس سلسلہ میں معلومات کے لئے آپ: الملل والنحلکی طرف رجوع کر سکتے ہیں استاد سبحانی، ص۱۹۱۔ ۲۲۸۔ نیز النص والاجتہاد، ص۵۱۹۔ ۵۲۵؛ اور مخصوصاً اس سلسلہ میں محمد تیجانی کی زندہ بحث کو کتاب ثم اھتدیت، میں ملاحظہ کرسکتے ہیں ص۷۷۔ ۱۲۲۔ اضواء علی سنة المحمدیة، کے ص۳۲۹، ص۳۵۶۔ ۳۶۳ پر ملاحظہ کریں۔
(۱۵)خصوصاً کتاب الفصل فی الملل والاھواء والنحل، کی ج۴، ص۹۴ پر مراجعہ فرمائیں؛ نیز کتاب الفصول المھمة فی تألیف الامة، کے ص۷۔ ۶۰؛ پر بھی رجوع کرسکتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ کتاب ثم اھتدیت، کے ص۴۱۔ ۴۴ کی طرف رکوع کیا جائے۔
(۱۶)الائمة الاربعة، ج۴، ص۱۱۷۔
(۱۷)طبقات الحنابلة، کی ج۲، ص۳۵۔ ۳۷، پر اسے ملاحظہ کریں۔ کتاب العواصم والقواصم فی الذب عن سنة ابی القاسم، کی ج۳، ص۲۳۔ ۲۳۰ پر رجوع کریں۔
(۱۸)القوانین الفقہیة، ص۱۸۔
(۱۹)العواصم من القواصم، کے ص۲۳۱ اور ۲۳۲ پر رجوع کریں، محمود صبحی ابن عربی اور انھیں کے جیسے افراد کی شدید تنقیدوں کے سلسلہ میں اس طرح اظہار نظر کرتا ہے: ''اس کے باوجود کہ امام حسینـ کی نسبت اہل ظاہر اور سلفیوں کا عقیدہ دینی عقائد کے باعث وجود میں آیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا زاویہ نگاہ خالص دینی نہیں تھا۔ ان میں سے اکثر شام کے باشندے تھے، مانند ابن تیمیہ یا اندلس سے متعلق تھے جیسے ابن حزم اور ابن عربی، ان لوگوں کے نظریات اقلیمی تعصب کے شایبوں اور یا اموی تعصبات سے خالی نہ تھے۔ اور اصولاً ان لوگوں کے نظریات شیعوں کے عقائد کے مخالف تھے... اور چونکہ امام حسینـ کی شہادت شیعوں کے عقائد کے بنیادی منابع میں سے ایک تھا، شیعوں کے مختلف فرقوں کا وجود اور ان کا باقی رہنا اسی واقعہ کے مرہون منت ہے، لہٰذا اسے غلط اور کم اہمیت دکھانا اور یا اس جرم کی نسبت کوفیوں کی طرف دینا جو دراصل پوری شیعت کو نابود کرنے کی ایک کوشش تھی۔'' نظریة الامامة، کے ص۳۳۸ پر رجوع کریں۔
(۲۰)امام حسینـ پر دوسری تنقیدوں کے بارے میں جو آپ پر اعتراضات کئے گئے ہیں ان کے متعلق معلومات کے لئے آپ نظریة الامامة، نامی کتاب کے ص۳۳۸ اور ۳۳۹ پر رجوع کرسکتے ہیں۔
(۲۱)تعجب کی بات تو اس مقام پر ہے کہ ابن حنبل، ابن عربی کے نقل کے مطابق تنہا اس سخن کی وجہ سے کہ وہ خود یزید کی زبان سے مطلب کو نقل کرتا ہے، اسے جلیل القدر اور عظیم المنزلت مانا ہے اس حدتک کہ اسے انھوں نے اپنی کتاب الزہد، میں اس کا نام زہاد اور صحابہ و تابعین کی صف میں شمار کیا ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے آپ العواصم من القواصم، نامی کتاب کے ص۲۳۲ اور ۲۳۳، پر تلاش کریں۔ یزید سے دفاع کے باب میں جسے انھوںنے دینی رجحان کے تحت ذکر کیا ہے، اسی طرح اسی کتاب کے حاشیہ میں محب الدین خطیب کے قول کی طرف رجوع کریں، ص۲۲۷ اور ۲۲۸، اس مقام پر جہاں معاویہ کا یزید کو ولی عہد بنانے کے اقدام کے بارے میں اس کا دفاع کرتے ہیں، نیز اسی شخص کی کتاب کے حاشیہ کے ص۲۱۵ اور ۳۴۸ پر رجوع کریں۔
(۲۲)نظریة الامامة لدی الشیعة الاثنی عشریة، ص۳۴۷، ۳۴۸۔
(۲۳)شرح ابن ابی الحدید، ج۲، ص۸۔ ۳۵۔
(۲۴)الاقتصار فی الاعتقاد، کے ص۲۰۳ اور ۲۰۵؛ کتاب شرح ابن ابی الحدید، میں امام الحرمین جوینی کے نظریات کے لئے ج۲۰، ص۱۰۔ ۱۲؛ اس کے نظریات کی تنقید کا بھی جو بہترین اور بے طرف ترین تنقیدوں میں سے ایک ہے اسی مقام پر ص۱۳۔ ۳۴؛ میں تلاش کریں۔
(۲۵)ایھا الولد، فارسی ترجمہ، ص۳۰؛ جو غزالی نامہ کے ص۴۱۹۔ ۴۳۶، سے منقول ہے۔ غزالی کا استدلال کہ وہ کہتا ہے: ''اس لئے کہ احادیث نبوی اور دوسرے صحیح مدارک اور مآخذ کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے۔'' اسی مطلب کو اس کے استاد امام الحرمین جوینی ایک مستدل اور جامع ترین بیان کے ذریعہ وضاحت کرتے ہیں۔ شرح ابن ابی الحدید، کی ج۲۰، ص۱۱، پر رجوع کریں۔
(۲۶)یزید پر لعنت بھیجنے کے مخالفین اور موافقین کے نظریات اور دونوں طرح کے مطالب پر مشتمل احادیث اور دونوں طرف کے دلائل کو معلوم کرنے کے لئے ابن الجوزی کی کتاب الرد علی المتعصب العنید کے عنوان سے مذکور ہے جو بہترین اور مستند ترین کتاب ہے آپ اس پر رجوع کریں۔
(۲۷)اہل سنت اور شیعوں کی تاریخی فہم اور نظریات ابتدا سے ہی جدا رہے ہیں۔ یہ فرق گذشتہ زمانہ میں عموماً صدر اسلام کی تاریخ میں خلاصہ ہوجاتا تھا اور آج کل پوری تاریخ اسلام کو شامل ہے بلکہ تاریخ اپنے عام مفہوم میں بھی تمامی ادوار کو شامل ہے۔ صدر اسلام کے متعلق ان دونوں زاویۂ نگاہ اور فہم کے فرق کا مقایسہ کریں کتاب العواصم من القواصماور اس پر محب الدین خطیب کے مقدمہ اور حاشیوں کو النص و الاجتہاداور اسی طرح الغدیر، مخصوصاً اس کی ۴، ۶ اور ۷ویں جلد کی طرف رجوع کریں۔
لیکن آج کل تبدیلی آچکی ہے۔ اس معنی میں اہل سنت کے روشن فکروں کی تاریخی فہم خاص طور سے صدر اسلام کے متعلق بعض اسباب کے تحت شیعوں کے نظریات سے نزدیک ہوگئی ہیں۔ اس مدعا کی پہلی دلیل، دینی تعصبات میں کمی آجانا اور دوسری دلیل تاریخی تنقید کے جدید قواعد و ضوابط کی طرف متوجہ ہوجانا ہے۔ شاید اس گروہ کے بہترین نمائندہ طہ حسین ہیں جنھوں نے اپنی کتاب الفتنة الکبری، کی پہلی جلد جس میں ان کے نظریات اور تحلیل و تجزیہ کیا ہے اور دوسری جلد میں بھی بہت سے مواقع پر وہ شیعوں کے نظریات سے بہت نزدیک بلکہ ان سے موافق ہیں۔ اگرچہ علامہ مرحوم امینی الغدیر، کی ج۹، ص۲۵۱۔ ۲۵۴، پر نیز انور الجندی اپنی کتاب مؤلفات فی المیزان، کے ص۶۔ ۱۹، میں اس کتاب پر تنقید کی ہے لیکن اس کی طرح کے بہت سے نمونے تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ بطور نمونہ آپ کتاب اندیشہ سیاسی در اسلام معاصر، نامی کتاب کے ص۳۰۸۔ ۳۳۲، پر کہ اس مقام پر جہاں دور حاضر کے سنی مصنفین کا واقعہ عاشورا کی بارے میں اس کی چھان بین اور تحلیل و تجزیہ کے طریقہ کو بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ ابھی بھی دینی علما اور روشن فکروں کی کمی نہیں ہے جو گذشتہ متعصبین کی روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بطور نمونہ مراجعہ کریں محمد الحامد الفقی کے حاشیہ کی طرف جو کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، مؤلفہ ابن تیمیہ انصار السنة المحمدیة، کی جماعت کے صدر اور مذکورہ کتاب کے مصحح بھی ہیں مخصوصاً ص۱۶۵ و ۱۶۶؛ التاریخ الاسلامی و فکر القرن العشرین، نامی کتاب میں بھی رجوع کریں خصوصیت کے ساتھ اس کتاب کے مقدمہ اور ص۸۷۔ ۱۰۶، اس کتاب کے مؤلف فاروق عمر جو روشن فکروں میں سے ایک ہیں۔
(۲۸) Maqime Rodinron. Marqiom and The Muslim World, PP. ۳۴-۵۹, ۱۹۴-۲۰۳
(۲۹), v ifclrhgcsu ۳/۴ hg ۳/۴ dk hfvhidl ۳/۴ vfhvc ?v iihxlfhv. hsblx ۳/۴ vlwv ۳/۴ v
(۳۰)معالم فی الطریق، ص۱۷۔ ۱۹۔
(۳۱)سابق حوالہ، ص۱۰۵۔ ۱۰۶۔
(۳۲)سابق حوالہ، ص۱۴۹۔ ۱۵۰۔
(۳۳)سابق حوالہ، ص۶۰۔ ۶۱۔
(۳۴)الازہر کی فتوا کمیٹی کے رئیس شیخ سبکی، قطب کی کتاب کے سلسلہ میں اس طرح فرمایا: ''اگرچہ کتاب معالم فی الطریق، پہلی نظر میں ایک ایسی کتاب نظر آئے جسے دیکھ کر ایسا معلوم ہو کہ اس میں اسلام سے توسل کیا گیا ہے لیکن اس کا فتنہ انگیز طریقہ اور اس کے مصیبت بار اثرات جوانوں اور قاریوں کا وہ طبقہ جو اسلام کے متعلق کافی معلومات کے حامل نہیں ہیں، ان کے لئے اس کتاب کا مطالعہ اسلام سے بیزاری کا موجب ہے۔ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے نزدیک زمانہ کے علاوہ دوسرے ادوار کو جاہلی دور کا نام دینا کفر آمیز عمل ہے۔'' پیامبر و فرعون، ص۶۲۔ دوسرے ناقدین کی تنقیدوں کے بارے میں اسی مقام پر ص۶۳۔ ۷۱ پر رجوع کریں اس سلسلہ میں خاص طور سے آپ رائد الفکر الاسلامی المعاصرمؤلفہ یوسف العظم ص۳۰۵۔ ۳۰۹، کی طرف رجوع کریں واسی طرح سید قطب کی طرف بھی: خلاصة حیاتہ و منھجہ فی الحرکة، کے ص۲۱۵۔ ۲۲۰، پر رجوع کریں ان لوگوںکے سلسلہ میں جنھوں نے دینی فریضہ سمجھتے ہوئے سید قطب پر تنقید یا ان سے دفاع کیا ہے۔ سید قطب کے بارے میں کتاب الادیب الناقد، مؤلفہ عبد اللہ عوض الخباص نامی کتاب کے ص۳۲۵، ۳۲۹ پر رجوع کریں۔
(۳۵)معالم فی الطریق، ص۹۔
(۳۶)سید قطب نے اپنی کتاب معالم فی الطریق، میں جس میں انہوں نے حالات کا اجمالی جائزہ لینے کے لئے مذکورہ کتاب کو تحریر کیا اور ان کے موافقین و مخالفین کے نظریات کا خلاصہ معلوم کرنے کے لئے الادیب الناقد، مؤلفہ سید قطب، کی کتاب کے ص۳۲۵۔ ۳۲۹ پر رجوع کریں۔
(۳۷)بطور نمونہ سبکی نے قطب پر تنقید کرتے ہوئے اس طرح اظہار خیال کیا: ''سید قطب نے خوارج کی طرح لاحکم الا لِلّٰہ کے مفہوم سے استفادہ کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہر قسم کی دنیاوی حاکمیت سے مخالفت کی دعوت دیں۔ '' اس کے بعد اضافہ کرتے ہیں: ''اس کے برخلاف قرآن نے مسلمان حاکم کی اطاعت کی وصیت کی ہے اور حاکم کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے اتباع کے ذیل میں اپنی رعیت کے درمیان عدل کے مطابق حکومت کرے۔ اس کے علاوہ غالباً مسلمان ممالک کے پیشوا اور حکام نیک ہیں۔'' پیامبر و فرعون، نامی کتاب کے ص۶۲۔ اور الشیعة والحاکمون، نامی کتاب کے ص۷ پر رجوع کریں؛ا لفکر السیاسی الشیعی، کے ص۲۶۹ پر بھی رجوع کریں۔
(۳۸)متقدمین کی تاریخ کے متعلق فکر و فہم کا بہترین نمونہ ابن عربی کی العواصم من القواصم، نامی کتاب ہے اور دور حاضر کا بہترین نمونہ اسی کتاب پر محب الدین خطیب کے حاشیے ہیں۔ قابل توجہ یہ ہے حتیٰ کہ ابن عربی ابن قتیبہ، مسعودی جیسے مؤرخین حتیٰ مبرد جیسا شخص جو ابن عربی کی نظر میں ایک ایسا شخص ہے جس نے تاریخ کی ناگفتہ بہ باتوں کو بیان کیا ہے، ان پر شدت سے تنقید کرتے ہیں۔ العواصم من القواصم، کے ص۲۴۸و ۲۴۹ پر، انھوں نے شدت کے ساتھ ابن قتیبہ اور ان کی کتاب الامامة والسیاسة، پر تنقید کرتے ہیں۔ اور اس کو شیعہ شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ مسلم ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے۔ اس مدعا کی بہترین دلیل ان کی کتا ب تأویل مختلف الاحادیث، مخصوصاً، ا س کا ص۷۰۔ ۷۳ ہے۔ وہ خود اور انھیں جیسے دوسرے افراد ایک باعظمت اور کسی تضاد اور خلاف کے بغیر تاریخ کو پسند کرتے ہیں اور کسی بھی صورت مائل نہیں ہیں کہ اسے کسی دوسری طرح پیش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام مؤرخین میں صرف طبری کو پسند کرتے ہیں اور اسے موثق مانتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بات کو نہیں سننا چاہئے۔ سابق حوالہ، ص۲۴۸۔
محب الدین خطیب نے بیشتر شدت اور حدت کے ساتھ ابن عربی کے نظریات سے دفاع کرتے ہیں اور یہ نکتہ ان کے مقدمہ اور اس کے حاشیوں کے مطالعہ کے ذریعہ معلوم ہوجاتا ہے جیسے کہ الامامة والسیاسة، کو ابن قتیبہ کی کتاب نہیں مانتے اور مسعودی کو شیعہ اور مبرد کو خوارج سے نزدیک مانتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کتاب تحول و ثبات، کے ص ۱۲۱، ۲۱۴۔ کی طرف رجوع کرسکتے ہیں۔
(۳۹)اہل سنت اصولاً (اساساً) تاریخ کی بہ نسبت خوش بین زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مخصوصاً اس مقام پر جہاں تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہو۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ایسی قیمتی اور باعث افتخار میراث کا وارث سمجھتے ہیں اور ہر اس شخص کے مقابلہ میں جس کا مقصد اس کو بے اہمیت اور انھیں کم اہمیت دکھانا ہو، فوراً ردعمل ظاہر کرتے ہیں بطور نمونہ آپ مراجعہ کریں کتاب الاسلام و اصول الحکم، کی رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، خضر حسین سے لیکر ضیاء الدین الریس تک ہر ایک نے اس کے تنقیدی موقف بلکہ ان کی تعبیر کے مطابق تاریخ کے متعلق بدبینی پر سخت تنقید کی ہے، مخصوصاً اس کے واسطے آپ الاسلام والخلافة فی العصر الحدیث، نامی کتاب کے ص۲۵۰۔ ۲۹۲ پر رجوع کریںاور کتاب الاسلام و اصول الحکم، پر محمد عمارہ کے مقدمہ کے ص۷۱۔ ۹۴ کی طرف رجوع کیا جائے۔
قابل توجہ بات یہ ہے کہ تاریخ کے متعلق اس دور جدید میں اہل سنت کی خوش بینی کی فکر کی نسبت بہت زیادہ جدید روشن فکروں کے استقبال کا باعث ہوئی ہے۔ جس کے بہت زیادہ اسباب ہیں جن میں سے اہم ترین یہ ہیں کہ اپنی مستقل حقیقت سے آگاہی اور شعور، غرب کی جانب سے مدام تحقیر، خود غربیوں کی جانب سے میراث اسلامی کی عظمت اور اسے اہمیت کے حامل ہونے کا یقین دلانا، نئی دنیا میں وارد ہونے کے لئے اس مقام ( Stage ) کے ہونے کی ضرورت اور آخرکار ان مباحث کا صاحبان قدرت کے سیاسی کھیل کے ساتھ متصل ہوجانا، یہ وہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ دوبارہ اپنے گذشتہ تاریخ کی طرف پلٹ آئے۔ بطور نمونہ التاریخ الاسلامی و فکر القرن العشریں، نامی کتاب کی طرف آپ رجوع کریں۔ لیکن اس بار مانند سابق مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کو مثبت نگاہوں سے دیکھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے باعظمت اور باشکوہ دکھائیں دوسروں کو بھی اس بات کا یقین دلائیں اور خود بھی اپنے یقین کو مستحکم کرلیں۔ ان کا ہدف گذشتہ کو کشف کرنا نہیں تھا۔ اس لئے کہ یہ کشف کیا جاچکا تھا۔ اس کا مقصد اس کی عظمت کو ثابت کرنا تھا اور یہ امر متعدد فکری اور عقایدی ہرج ومرج اور نابرابری کا باعث ہوا اور بہت ساری خواہشات کو اپنے ساتھ لایا۔ اب انھیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا تھیاور اب کیا ہیں اور ان کی کیا کیا قدرتیں اور ان کی مشکلات کیا ہیں اور اب وہ کیا چاہتے ہیں اور انھیں کس چیز کی ضرورت ہے؟
گرونبام نامی شخص نے اس ذہنی اور فکری آشفتگی کو دور حاضر کے بزرگ ترین گب ( Gibb ) نامی عرب شناسوں میں سے ایک ہے اس سے اس طرح نقل کرتا ہے: ''۱۹۴۲ئ میں گب نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا: میں نے اب تک یورپ کی کسی بھی زبان میں نہیں دیکھا ہے کہ ایک عرب چاہے وہ کسی بھی گروہ کی جانب سے ہو اس نے کوئی ایک کتاب بھی لکھی ہو جو کسی ایک یورپی طالب علم کی مدد کرے جس سے وہ عربی ثقافت کی جڑوں کا پتہ لگاسکے۔ اس سے ہٹ کر بلکہ اب تک میں نے خود رعربی زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی ہے جو خود اعراب کو عربی ثقافت کے معانی کا تحلیل و تجزیہ کرکے اسے بیان کرسکے۔ '' وہ اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ''اس کلام کو غیر اعراب کی اعراب کو اپنے آپ اور مغربی لوگوں پر بھی وہ لوگ اپنی ثقافت کو پہچنوانے میں اور اس کی وضاحت اور تفسیر میں بھی ان (اعراب) کی ناکامی میں مزید وسعت دی جاسکتی ہے۔ یہ بات ابھی بھی صحیح ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سالوں تک یہ کلام ایساہی رہے... ایسے دینی، سیاسی اور ثقافتی مقاصد اور ایک ایسی تحقیق تک پہونچنے کے لئے بندھ بنائے ہوئے ہیں یا کم سے کم اس راہ میں مانع ہیں جس کا ہدف اسلامی تمدن کی تفسیر اور توضیح ہے۔ جب بھی شرق وسطیٰ کے مسلمان اپنے سوابق کے متعلق یا غرب کے متعلق بات کریں تو سب سے پہلے ان کا فیصلہ سیاسی ہوتا ہے۔ ''
G. E. Von Grunebaum, Islam, ۱۹۴۹,PP. ۱۸۵-۸۶
نیز کتاب تحول و ثبات، نامی کتاب کے ص۱۷۳۔ ۱۹۹ پر بھی آپ رجوع کریں۔
(۴۰)اصولاً شیعوں کے نزدیک اہم ترین، بلکہ جذباتی ترین اور سب سے زیادہ حمایت کرنے والا معیار شیعوں کے دور حاضر کے مذہبی ادبیات کی بنیادیں، کم سے کم ایران میں حکام پر تنقید رہی ہے۔ اس حدتک کہ آخری دہائیوں کے مصنفین اور روشن فکر حضرات تنقید کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے رہے ہیں۔
(۴۱)بطور نمونہ آخری پانچ صدیوں کے درمیان ایرانیوں اور عثمانیوں کی حکومتوں کے درمیان تاریخی تسلسل کا ایک دوسرے سے مقایسہ کریں۔
(۴۲)عصر حاضر میںسیاسی اور معاشرتی تبدیلیوں اور تغیرات سے متعلق عربوں کی فکری تبدیلیوں کو معلوم کرنے کے لئے تحول و ثبات، نامی کتاب کے ص۳۲۔ ۵۸ اور ۱۷۴ پر رجوع کریں۔ ۱۸۲، نیز مقالہ مدرنیزہ کردن اسلام و تئوری بہ عاریت گرفتن فرہنگ، کی طرف رجوع کریں جو کتاب
G. E.Von Grunebaum, Islam. ۱۹۴۹, PP. ۱۸۵-۸۶ کی طرف رجوع کریں۔
(۴۳)بائیں بازو کی پارٹی اور لادینیت کے حامیوں کی طرف سے عبدالرزاق کی کتاب کے استقبال سے متعلق آگاہی کے لئے الاسلام و الخلافة فی العصر الحدیث، نامی کتاب کے ص۹۔۲۱ کی طرف رجوع کریں۔ ان لوگوں نے اس کتاب کی اس طرح توصیف کی ہے: ''ایک ایسی کتاب ہے جس نے آگ بھڑکادی، ایک ایسی آگ جو اب تک خاموش نہیں ہوئی ہے، مصر کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اسلامی کتاب، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کتاب، عظیم بحران کا آغاز ہوتا ہے، بادشاہ کے مقابلہ میں عالم، کفر سے متہم عالم کا محاکمہ، بادشاہ ایک عالم کے خلاف تنہا بے ناصر و مددگار کھڑا ہوگیا ہے، ان تغیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں دنیائے اسلام اور عربی دنیا نے ۸۰ کی پوری دہائی میں گذارا یہ کتاب یا کم سے کم اس کتاب میں موجودہ مطالب مستقبل میں لوگوں کی توجہ اور غور و فکر کا باعث دوبارہ استقبال سے روبرو ہوگی۔ جیساکہ ان آخری سالوں میں یہ کتاب متعدد بار زیور طبع سے آراستہ ہوچکی ہے یہ واقعہ ایک کتاب کے لئے بہت بڑی بات ہے۔
(۴۴)بطور نمونہ نظام الاسلام، نامی کتاب کی طرف رجوع کریں مؤلفہ محمد المبارک کے ص۵۔۲۹ معالم الخلافة الاسلامیة، نامی کتاب کے ص ۷۱۔ ۸۳ پر بھی رجوع کریں۔
(۴۵)الاسلام واصول الحکم، ص۱۲۹۔
(۴۶)سابق حوالہ، ص۱۳۲۔
(۴۷)سابق حوالہ، ص۱۳۶۔
(۴۸)سابق حوالہ، ص۱۶۸۔
(۴۹)سابق حوالہ، ص۱۷۵۔
(۵۰)سابق حوالہ، ص۱۷۸، ابوبکر کا زکات کے معین کرنے میں ان کی جنگ کی حقانیت اس حد تک اہل سنت کے درمیان اجماعی اور اتفاقی حیثیت کی حامل ہے جس کی وجہ سے بے شمار فقہی احکام ظہور میں آئے اس کے لئے فقہ السنة، نامی کتاب مصنفہ السید سابق کی ج۱، ص۲۸۷، ۲۹۳ پر رجوع کریں۔
(۵۱)سابق حوالہ، ص۱۸۱۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو خلافت کے شرعی اور عقلی وجوب کے قائل نہیں تھے وہ بھی ضرورت کے تحت اجماع مسلمین کے توسط سے اس کے لزوم اور وجوب کے قائل ہوگئے تھے۔ النظم الاسلامیة، نا می کتاب کے ص۲۸۰۔ ۲۹۳ پر رجوع کریں۔ جس میں آرنولڈ کے نظریات پر تنقید کرتا ہے۔
(۵۲)سابق حوالہ، ص۱۳۱۔
(۵۳)العقیدة والثورة،نامی کتاب کی طرف رجوع کریں۔
(۵۴)کنزالعمال، ج۶، ص۴۔ ۸۹ پر رجوع کریں۔
(۵۵)الاسلام والخلافة فی العصر الحدیث، ص۳۱ پر رجوع کریں۔
الاسلام و اصول الحکم، نامی کتابنے ہلچل مچادینے کے باوجود خاص طور سے دینی حلقوں میں شعلہ بھڑکا دیا، لیکن پھر بھی اس کتاب کے مؤلف کے افکار اور مطالب بعض متدینین کے نزدیک مقبول اور مورد استقبال قرار پاگئے۔ ان لوگوں میں سے ایک عبدالحمید متولی تھے۔ وہ بھی عبد الرزاق کی طرح نظام خلافت کی مشروعیت کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کو باقی رکھنے سے امت کا نظام درہم برہم ہوجائے گا اور اس امت پر عسر و حرج حاکم ہوجائے گا جبکہ شریعت نے نظام کے معطل ہوجانے سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نظام کو قائم کرنا ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہنا چاہئے کہ اسلام نے کسی خاص انداز کے نظام حکومت کی سفارش نہیں کی ہے۔ وہ آخر میں نتیجہ لیتے ہیں کہ خلافت اسلام سے نہیں ہے اور اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے۔ معالم الخلافة فی الاسلام؛ الفکر السیاسی الاسلامی، کے ص۷۴ اور ۷۵ جو کتاب متولی سے منقول ہے وہاں پر رجوع کریں، مبادی نظام الحکم فی الاسلام، کے ص۵۴۸۔ ۵۵۰ پر رجوع کریں۔
(۵۶)چونکہ سیاسی اور حکومتی مفاہیم اور اصولاً (قاعدتاً) وہ تمام مسائل جو خلافت و امامت سے متعلق ہیں اہل سنت کے نزدیک صدر اسلام کے تاریخی حقائق سے وجود میں آئے ہیں بلکہ یہاں تک کہ کہا جاسکتا ہے (کہ یہ مفاہیم اور حدبندیوں اور تعریفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر یہ کہ اس دور کے حوادث کو ضابطہ مند بنانے اور اصولی شکل دینے) جس کے لئے دین و سنت کے برابراہمیت کے قائل تھے۔ اسی وجہ سے حد سے زیادہ واقع بینی اور اس کی طرفداری کا لبا دہ اڑھا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ گویا موجود واقعیت کو قبول کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا اور اس بات کے لئے بھی مائل نہیں ہے کہ موجودہ موقعیت کو اس سے بہتر موقعیت کی خاطر ختم کردیا جائے اور اس امر کے لئے اس حد تک مصر ہے کہ ایسے عمل میں ہاتھ بڑھانے کو حرام اور ناجائز شمار کیا ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ حالت اگرچہ اسوہ ( Ideal ) نہیں ہے لیکن ان کی نظر میں نہائی تحلیل اور دنیا شناسی کے مطابق کسی بھی قسم کی تبدیلی اور تغیر سے بہتر ہے اور اس کی حفاظت ہونی چاہئے کہ یہ امر ان کی نظر میں بھی لوگوں کے دین اور دنیا کی مصلحت کے لئے بھی مفید ہے۔ المواقف، نامی کتاب کے ص۳۹۶۔ ۳۹۷۔ پر اس جگہ جہاں ان لوگوں کے نظریات کی رد کرتے ہیں جو اس بات کے کوشاں ہیں کہ قاعدۂ لاضرر کی مدد سے سلطان کی موجودگی اور اس کی اطاعت کے وجوب کے بطلان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں صاحب مواقف کی رد اہل سنت کے سیاسی افکار کا بہترین اور کوتاہ ترین بیان ہے۔ اعلام الموقعین، نامی کتاب کی ج۳، ص۳۔ ۷، پر رجوع کریں اور مخصوصاً کتاب السیاسة الشرعیة، کے ص۳۔ ۱۷ پر رجوع کریں۔
اس کے درمیان بعض ایسے لوگ رہے ہیں جو اصل مذکور کی کاملاً رعایت کرتے ہوئے، معاشرتی اصلاحات کے اقدامات لئے کی سفارش کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی لگادی ہے کہ جبکہ فضا پرسکون اور بغیر کسی حادثہ کے ہو۔ ان سب میں سر فہرست ابن تیمیہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں اس مقام پر جہاں اپنی مذکورہ کتاب کے بعض حصہ میں اس کے بعد کہ وہ کہتا ہے کہ ہدف یہ ہے کہ دین کو حاکمیت کی ضرورت ہے وہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور اس امر کو آیات و روایات کے ذریعہ ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کہتا ہے: ''پس اگر ہدف یہی ہو تو پھر اقرب فالاقرب کی رعایت ضروری ہے اور یہ دیکھیں کہ حاکمیت کے ان دونوں امیدواروں میں سے کون اس ہدف کو پورا کرنے کے لئے زیادہ مناسب ہے اسے حاکم بنادیں۔ '' سابق حوالہ، ص۲۴ پر رجوع کریں۔
البتہ ایسے نظریہ کے بے شمار فوائد دیکھنے میں آئے ہیں اور اب بھی ہیں۔ جب ہدف یہ بن جائے کہ موجودہ حالات کی حفاظت کی جائے اور اس کی اصلاح اس حد تک کہ عمومی تغیر یا سیاسی تبدیلی کا باعث نہ بنے، فطری طورپر نیک و بد کو پہچاننے کے معیار اور یہ کہ کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بالکل تبدیلی اس صورت میں وجود میں آجائے گی۔ یہاں پر تشخیص کا معیار موجودہ واقعیت بن جائے گانہ کہ اس سے وسیع تر نظریات مثال کے طورپر اصل دینی نظریات سے نشأت پائے یا کم سے کم دینی افکار کو مشعل راہ بنائے۔ ابن تیمیہ کی روایت کے مطابق ابن حنبل کے اس کلام میں غور و فکر کریں: ''ابن حنبل سے ایسے لوگوں کے سلسلہ میں سوال کیا گیا۔ جن میں سے ہر دو لشکر کے سردار ہیں ان میں سے ایک قوی اور فاسق و فاجر ہے اور دوسرا شخص، ضعیف اور صالح ہے۔ تو ان دونوں میں سے کس کی ہمراہی میں جہاد کے لئے جائے؟ ابن حنبل نے اس طرح جواب دیا: لیکن یہ کہ جو شخص فاسق اور طاقتور ہے اس کی قدرت مسلمانوں کے لئے ہے اور اس کا فسق خود اسی کے لئے ہے لیکن جو شخص صالح اور کمزور ہے، اس کی خوبی خود اسی کے لئے ہے۔'' اس کا ضعف مسلمانوں کے لئے ہے۔ لہٰذا اس صورت میں قوی اور فاجر شخص کی ہمراہی میںجہاد کے لئے جانا چاہیئے اور پھر اپنے اس جواب کو آنحضرتصلىاللهعليهوآلهوسلم کی ایک حدیث کے ذریعہ اس کی توجیہ اور تکمیل کرتے ہیں: آپ نے فرمایا: ''خداوندعالم اس دین کی فاجر افراد کے ذریعہ کرتا ہے...'' ص۱۷۔
ایک دوسرے مقام پر پھر ابن تیمیہ نقل کرتا ہے: ایک بزرگ عالم دین سے سوال کیا گیا اگر قضاوت کے شغل کے لئے کسی فاسق عالم یا دیندار جاہل کے علاوہ کوئی نہ مل سکے تو ان دونوں میں سے کون مقد م ہوگا؟ تو اس عالم نے جواب دیا: اگر فساد کے غلبہ کی وجہ سے اس دیندار کی زیادہ ضرورت ہو تو وہ مقدم کیاجائے گا اور اگر حقوقی مسائل کی پیچیدگی کی وجہ سے اس عالم کی زیادہ ضرورت ہو تو پھر اسے مقدم کیا جائے گا۔ '' اس کے بعد وہ خود (ابن تیمیہ) اپنی عبارت میں کچھ اس طرح اضافہ کرتے ہیں: ''اس بات پر توجہ رکھتے ہوئے جن میں کاملاً شرائط نہیں پائے جاتے ہیں جب انھیں ولایت کا عطا کرنا صحیح ہے جب کہ افراد میں وہ دوسرے موجود افراد بہتر ہوں تو اس مقام پر واجب ہے کہ ان کا تعاون کیا جائے اور حالات میں سدھار لانے کی کوشش کرے تاکہ وہ چیز حاصل ہوجائے جس کے لئے لوگ ناچار ہوں...'' ص۲۰ اور ۲۱ پر رجوع کریں۔
ایک دوسرے مقام پر اسی نکتہ کی اس سے زیادہ واضح انداز میں بیان کرتا ہے: تعاون کی دوقسمیں ہیں۔ تقوی اور نیکی پر تعاون جیسے جہاد، اقامہ حدود، شرعی حقوق کو لے کر اس کو مستحقین کے حوالہ کرنا۔ یہ تعاون کی وہی قسم ہے جس کے لئے خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور اگر کوئی اس بات سے ڈر کرکہ کہیں ظالموں کی مدد نہ ہو، ایسے اقدام سے اپنے آپ کو روک لے تو اس نے واجب عینی یا کفائی کو ترک کیاہے اس گمان کے تحت کہ ایک فرد متقی اور پرہیزگار ہیاور بسا اوقات تقویٰ کے ساتھ ڈر اور سستی میں اشتباہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ دونوں ہی کاامساک اور اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ تعاون کی دوسری قسم گناہ و ظلم پر تعاون کرنا ہے جیسے ناحق کسی کے قتل پر مدد کرنا یاکسی شخص کے مال محترم کا غصب کرلینا یا کسی کو ناحق مارنا اور اس کے ایسے دوسرے تعاون۔ تعاون کی ایسی قسم ہے جسے خدا اور اس کے رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم نے حرام قراردیا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔'' ص۴۲۔
ایسی فکر کی بنیاد پر اس کے درک اور تفسیر کی کیفیت ایک دوسرے اعتبار سے معاشرہ میں ایک طرح کی بدعنوانی اور گڑبڑی ہے۔ وہ صرف سلطان کو فساد کا باعث نہیں سمجھتا ؛ بلکہ اس میں کچھ حصہ میں رعایا کو بھی شریک سمجھتا ہے۔ اس مسئلہ میں اس کا زاویۂ نگاہ تنہا سیاسی نہیں ہے، بلکہ معاشرتی اور ثقافتی بھی ہے۔ اس کی کتاب السیاسة الشرعیة، کی فصل سوم کا عنوان اس طرح ہے: ''والیوں اور رعایا کے ظلم کے باب میں'' ص۳۸۔ ۴۲ اور اس کے بعض دوسرے مقام پر کہتے ہیں: ''والیوں اور رعایا کی طرف سے کثرت سے ظلم سرزد ہوتا ہے یہ لوگ جو چیز حلال نہیں ہے اسے اپنالیتے ہیں اور جو امر واجب ہوتا ہے اس سے منع کردیتے ہیں۔ جیساکہ کبھی فوجی اور کسان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں میں کے بعض گروہ جہاد سے منھ پھیر لیتے ہیں اور والی لوگ مال خد اکو اکٹھا کرتے ہیں جبکہ ان کا اکٹھا کرنا حرام ہے...'' ص۳۸ اور ۳۹۔
حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طرز فکر ایک طولانی سابقہ کا حامل ہے۔ اس طرح نقل کیا جاتا ہے کہ ایک روز اہل کوفہ کا ایک گروہ عمر کے پاس آیا اور اپنے والی سعد ابن ابی وقاص کے خلاف شکایت کی اس نے کہا: ''ائے لوگو! کون ہے جو مجھے کوفیوں کے لئے شائستہ ہو اور میرے ضمیر کو سکون پہنچائے؟ اگر کسی متقی شخص کو وہاں کا والی بناؤں تو اسے یہ ناتواں بنادیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ناتواں اور ضعیف کو والی بنایا ہے اور اگر کسی قدرتمند کو ان پر حاکم بناؤں تو اسے گمراہی اور خیانت کا الزام لگاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک فاجر کو حاکم بنادیا ہے۔ '' اس مجلس میں مغیرہ بن شعبہ حاضر تھا اور اس نے ایسے کہا: ''ائے امیرالمؤمنین! ایک متقی اور ضعیف شخص کا تقویٰ خود اسی کے لئے ہے اور اس کا ضعف آپ کے لئے ہے اور ایک طاقتور فاجر انسان کی طاقت آپ کے لئے اور اس کا فسق خود اسی کے لئے ہے۔ '' عمر نے کہا: ''تم نے درست کہا۔ تو وہی قدرتمند اور فاجر انسان ہے پس ان لوگوں کی طرف جاؤ'' اور اس کو کوفہ کی حکومت عطا کردی۔ عمر ابن خطاب، مصنفہ عبدالکریم خطیب، ص۲۷۶۔ مغیرہ کی شخصیت اور اس کی خصوصیات کو معلوم کرنے کیلئے شرح ابن ابی الحدید، نامی کتاب کی ج۲۰، ص۸۔ ۱۰ پر رجوع کریں۔
ایسے نمونے خاص طور سے عمر کے زمانہ میں کثرت سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ مختلف موارد میں سے بہترین مورد معاویہ کا شام میں اور عمرو عاص کا مصر میں والی کے عنوان سے باقی رکھنا ہے کہ ان میں سے ہر دو اپنے کردار کی وجہ سے عمر کی تنقید کا نشانہ بنے بلکہ اس کے غصب کا موجب بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود آخری نکتہ کی رعایت کی بناپر انھیں امارت سے معزول نہیں کیا۔ سابق حوالہ، ص کی ترتیب کے اعتبار سے۲۷۲ اور ۲۷۷ پر رجوع کریں۔ ایسے ہی طرز فکر کے نمونوں کو حجاج کے کلام میں بھی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے آپ اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة، نامی کتاب مؤلفۂ علی ابن محمد سمرقندی کے ص۲۸۵ پر رجوع کریں۔ نیز طبقات الحنابلة، نامی کتاب کی ج۲، ص ۳۶ پر بھی رجوع کریں۔
اس آخری نکتہ کی کامل توضیح اس فکر کی فقہی، کلامی اور تاریخی بنیادوں کو ثابت کرنے، بعد میں آنے والے ادوار اور دور حاضر میں اس کے پیش آنے والے نتائج اور برے اثرات، اہل سنت کی مذہبی عمارت کو وجود دینے اور علما و عوام کے نفسیات کو جاننا طول کا باعث ہے اس کو شکل دینے میں اساسی کردار ادا کیا ہے۔ اس نکتہ کو یہاں بیان کرنے کا ہدف صرف ایک ایسے کی یاددہانی تھی جو بہت اہمیت کی حامل ہے عین اس عالم میں کہ حساس ترین اور ظریف ترین نقاط میں سے ہے کہ معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں کو شدت سے جدا کرتا ہے ان آخری دہائیوں میں اہم بنیادی تبدیلیوں کے وجود میں آنے کے باوجود ابھی بھی اس تفاوت کو وضاحت کے ساتھ ملاحظہ کیا جاسکتا ہے، اہل سنت کے درمیان آنے والے دور میں سیاسی بدلاؤ لانے والے عناصر کی کمی کے ساتھ یہ ہر صورت مستقبل میں سنیوں کے درمیان کثیر دلائل کے تحت قہراً ایسا ہوکر رہے گااور یہ فرق اور زیادہ واضح ہوجائے گا۔ نیز آپ رجوع کریں:
Gibb, Studies on The Civilization of Islam, PP.۱۴۱-۶۶
(۵۷)اہل سنت کے درمیان حکومت کی نظریہ پردازی( Theory ) کے باب میں اور حاکم کے خصوصیات اور ان دونوں کے درمیان رابطہ کے متعلق معلومات کے لئے من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، نامی کتاب کے ص۳۵۹۔ ۳۸۹پر رجوع کریں، حاکم اور حکومت میں ارتباط کو معلوم کرنے کے لئے نظام الاسلام، کے ص۱۱۔ ۵۰ پر بھی رجوع کریں۔ خصائص التشریع الاسلامی فی السیاسة والحکم، نامی کتاب مؤلفہ فتحی الدرینی کے ص۲۶۳۔ ۳۱۹ پر بھی رجوع کریں۔
(۵۸)اس نکتہ کے بارے میں کہ شیعہ زاویۂ نگاہ سے امامت اور اس کے ضمن میں امام کے کیا شرائط ہیں؟ نمونہ کے طورپر حضرت امیر المؤمنین امام علیـ کے اس باب سے متعلق خطبوں میں سے ایک خطبہ کے لئے شرح ابن ابی الحدید، نامی کتاب کی ج۸، ص۲۶۳ کی طرف رجوع کریں۔
(۵۹)بطور نمونہ الاحکام السلطانیة، نامی کتاب مصنفہ ابویعلی ص۱۹۔ ۲۵ پر رجوع کریں جس کا ایک حصہ اس طرح ہے: خلافت قہر و غلبہ کے ذریعہ منعقد ہوتی ہے اور بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ''جو شخص بھی تلوار کے زورپر غالب آجائے اور وہ امیر المؤمنین کہلوائے، پس ہر اس شخص پر جو بھی خدا پر اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس حاکم سے سرپیچی کرے اور اسے اپنا امام نہ سمجھے خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہی کیوں نہ ہو۔ '' پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ''امامت نماز جمعہ اس شخص کے ذمہ ہے جو غالب آجائے۔ '' ابن عمر سے نقل کرتا ہے کہ حرہ کے وحشت ناک واقعہ میں (جو یزید کے دور میں عوام الناس کا قتل عام کیا گیا واقع ہوا، اصحاب اورتابعین قتل کئے گئے اور ان کی ناموس پر تجاوز کیا گیا۔ ) حکام کے ساتھ نماز پڑھی اور جب لوگوں نے اعتراض کرنے والوں کے جواب میں کہا: ''ہم اس کے ساتھ ہیں جو کامیاب ہوجائے۔'' سابق حوالہ، ص۲۳۔
اس سے زیادہ بہتر اور واضح انداز میں ابن حنبل کے قول کی طرف الائمة الاربعة، نامی کتاب کی ج۴، ص۱۱۹ اور ۱۲۰ پر رجوع کریں۔
(۶۰)الامامة والسیاسة، ج۱، ص۱۲۔ ایک دوسرا نمونہ بشیر ابن سعد انصاری کا کلام ہے جب حضرت امام علیـ نے اپنے ایک بیان میں خاندان رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم کے اوصاف بیان کئے اور یہ کہ یہی خلافت کیلئے اولویت رکھتے ہیں انھیں خلافت کے لئے اولی سمجھا تو سعد نے آپ کو مخاطب کرکے کہا: ''ائے علی! اگر انصار نے ان باتوں کو ابوبکر کی بیعت سے پہلے سن لیا ہوتا تو ان میں سے کوئی ایک بھی اس امر میں تمہارے بارے میں اختلاف نہ کرتا۔ '' سابق حوالہ، ص۱۲۔ ''اگر خلیفہ فاسق ہوجائے تو اسے معزول نہیںکیا جاسکتا، حنفی فقہا سب کے سب متفق القول ہوکر ایک ہی رائے دی ہے۔ خلافت کے لئے عدالت شرط نہیںہے لہذا فاسق مرد بھی خلیفہ بن سکتا ہے، اگرچہ اس کا خلیفہ بننا مکروہ ہے۔ '' ''عبدالکریم البکاء نقل کرتا ہے: میں نے اصحاب پیغمبر میں سے دس صحابیوں کو دیکھا کہ ان سبھی لوگوں نے جائر حکام کی امامت میں نماز پڑھی۔ کتاب معالم الخلافة الاسلامیة، ص۳۰۶ اور ۳۰۷۔
(۶۱)اس کے بہترین نمونوں میں سے ایک نمونہ خود امام حسینـ کی صریح تنقید ہے جس میں ان علما کی سخت مذمت کی ہے جو ستم پرست اور بدعہد رہے ہیں۔ کتاب تحف العقول، ص۱۷۱، ۱۷۲۔
(۶۲)من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ص۴۳۸، ۴۴۴۔
(۶۳)کتاب الخلافة والامامة، مصنفہ عبدالکریم خطیب، ص۳۰۳۔
(۶۴)کتاب' 'الاسلام و اصول الحکم، بڑے ہی اچھے انداز میں اس داستان کی تحلیل اور چھان بین کی گئی ہے۔ خاص طور سے ص۱۶۸۔ ۱۸۲پر مراجعہ کریں۔
(۶۵)گولڈزیہر نے بہترین انداز میں عباسیوں کے اقدامات کے اثرات کو مسلمانوں کی فقہی و کلامی اور احادیث کے مجموعہ کی عمارت کو شکل صورت دینے اور ان کی موقعیت کے استحکام کے بارے میں بھی توضیح دیتا ہے۔
. Goldziher, Muslim Studies, Vol ۲nd, PP. ۷۵-۷۷
(۶۶)مفہوم علیت کے باب میں اور بنیادی طور سے اعراب کی عقلانی زندگی کے بارے میں فجر الاسلام، نامی کتاب کے ص۳۰۔ ۴۹ پر رجوع کریں۔
(۶۷)فجر الاسلام، ص۳۹۔
(۶۸)سابق حوالہ، ص۴۰۔ سیرۂ ابن ہشام سے منقول ہے ۔
(۶۹)السنة النبویة بین اہل العقد واہل الحدیث، ص۹۵۔ یہ کتاب ایک مشہور و معروف اور بزرگ ترین روشن فکر علما میں سے ایک شخص کی تصنیف ہے جو بہترین نمونوں میں سے ایک ہے، جس میں مصنف نے خود اپنے اور اپنے اس مؤلف اور اس کے ہم فکر اور مسلمان طرفداروں سلفی اور وہابی مسلک لوگوں کی دین اسلام سے متعلق فہم میں پائے جانے والے فرق کو بخوبی بیان کیا ہے۔ یہ کتاب اس زاویہ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اس قدر اہم نہیںہے، اس کے ضمن میں مؤلف نے سعودی عربیہ کے طالبعلموں سے ہوئے اپنے مناقشہ کو جو حلیت اور حرمت غنا کے سلسلہ میں ہے اور یہ کہ غنا کی کون سی قسم حرام ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں مشغول تدریس تھے، اپنے اسی مناقشہ اور مناظرہ کو درج کیا ہے اور اس کے بعد بازگو کرتے ہیں: ''...اس کے بعد میں نے اس سے سنجیدگی سے کہا: اسلام ایک اقلیمی دین نہیں ہے جو تمھیں سے متعلق ہو اور صرف تمھیں اس کو درک کرسکو اور صرف تمہیں اس کی تفسیر سے واقف ہو۔ تمھاری فقہ ایک بدوی، خشک اور محدود ہے اور جب تم اس فقہ اور اسلام کو ایک ردیف میں قرار دیتے ہو اور اس دور کو جدا نہ ہونے والا دور قرار دیتے ہو تو اس عمل کے ذریعہ اسلام کو سبک اور لوگوں کو نظر انداز کردیتے ہو اور یہ اسلامی فریضہ اور ہدایت کی بہ نسبت ایک بہت بڑا ظلم ہے...۔ ص۷۵۔ ۷۶۔
(۷۰)فجر الاسلام، ص۴۱، ۴۲۔
(۷۱)سابق حوالہ، ص۴۳ جو کتاب الملل والنحل، شہرستانی سے منقول ہے۔
(۷۲)عیسائی اور یہودی علما مخصوصاً وہ علما جو مسلمان ہوگئے ہیں مسلمانوں کے افکار اور عقائد میں ان کی تاثیر کو معلوم کرنے کے لئے الملل والنحل، نامی کتاب مؤلفہ استاد سبحانی کے ص۷۱۔ ۹۶ معاویہ کی دوستی کے افسانہ اور اس کی ترویج کے سلسلہ میں معلومات کے لئے آپ مروج الذہب، نامی کتاب کی ج۳، ص۳۹ پر رجوع کریں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ صدر اول کے عربوں کی ابتدائی بسیط ذہنیت اور ان کی ثقافت اور بہت سارے سوالات جو اسلام کے آنے سے اور ان لوگوں کا دوسری اقوام و ملل سے میل جول کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں (بے شمار سوالات) اٹھے تھے اور ان کی حساس و تجسس پسند طبیعت اس احترام کے ساتھ جس کے لئے اپنے واسطے دوران جاہلیت سے قائل تھے، یہ خود علما اہل کتاب کا مسلمانوں میں نفوذ کے لئے حالات کی فراہمی کی بہترین دلیل ہے۔ ابن خلدون اس مقام پر جہاں وہ قرآن کی تفسیروں کے سلسلہ میں بحث کرتے ہیں بڑی ہی ہوشیاری اور کیاست کے ساتھ اس نکتہ کی طرف اشارہ اور تاکید کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے لحاظ سے، ہم اس نکتہ کو کامل ذکر کررہے ہیں: ''ایک تفسیر روایتی جو سلف کے ذریعہ نقل ہوئی احادیث اور آثار کی طرف مستند ہے جو ناسخ و منسوخ کو پہچاننا، نزول آیات کو جاننااور ان کے مقاصد کو سمجھنا ہے اور ان تمام مسائل کو جاننے کے لئے صرف ایک راستہ رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ اور تابعین سے (روایات کو) نقل کریں اور متقدمین نے اس راہ میں ایک کامل مجموعہ آمادہ کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کی کتب اور منقولات صحیح اور سقیم اور قابل قبول اور مردود روایات پر مشتمل ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ عرب قوم اہل کتاب اور دانشور نہیں تھے، بلکہ ان کی طبیعت پر بادیہ نشینی اور جاہلیت کی عادت غالب آگئی تھی اور ہمیشہ ایسے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور جب بھی مسائل کو سیکھنے کا ارادہ کرتے تھے کہ انسانی نفوس اس کی شناخت کے لئے کمر ہمت باندھتا ہے، جیسے تکوینی اعتبار سے مودر چیزوں کا وجود میں آنا اور آغاز خلقت اور جہان ہستی کے اسرار جیسے مسائل کے بارے میں ان لوگوں سے سوال کرتے تھے جو ان سے پہلے اہل کتاب تھیاور وہ لوگ اہل توریت یہودی اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ تھے جو ان کی روش کے اعتبار سے زندگی کرتے تھے۔ اور اس زمانہ میں توریت کی پیروی کرنے والے، اعراب کے درمیان زندگی کررہے تھے اور خود انھیں لوگوں کی طرح بادیہ نشین تھیاور اس طرح کے مسائل کو جس قدر اہل کتاب کے عوام آگاہ تھے یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے تھے اکثر توریت کی پیروی کرنے والے لوگ حمیرانی تھے اور دین یہود کو اختیار کئے ہوئے تھے اور جب یہی لوگ اسلام پر ایمان لائے تو انھیں معلومات پر ان لوگوں نے اکتفا کی جس پر اب تک عمل کرتے آئے تھے اور ان کی احکام شرعی سے وابستگی جن موارد میں احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ویسے ہی باقی تھے جیسے آغاز خلقت کی خبریں، پیشین گوئیاں اور جو چیزیں ملاحم کو شامل ہیں، انھیں کے ایسی دوسری چیزوں میں انھیں معلومات پر باقی رہے۔ وہ گروہ کعب الاحبار، وہب بن منبہ اور عبداللہ ابن سلام پر مشتمل تھا اور انھیں جیسے دوسرے افراد ہیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے مقاصد کی تفسیریں روایات اور منقولات جو ان پر موقوف ہوئی تھیں وہ انبار ہوگئیں اور وہ ان مسائل میں شمار نہیں ہوتی تھیں کہ جن کی بازگشت شرعی احکام کی طرف ہوتی ہیں کہ وہ صحت جو عمل کا موجب ہے اس کے سلسلہ میں تأمل اور بیان کیا جاسکے۔
اور مفسرین نے بھی ان کے سلسلہ میں تساہلی سے کام لیا اور اپنی تفسیری ایسی کو کتابوں حکایتوں سے بھر دیا اور ان لوگوں کی جڑیں اور بنیادیں جیساکہ ذکر کرچکے ہیں کہ توریت کی پیروی کرنے والے بادیہ نشین ہیں اور جو کچھ بھی نقل کیا ہے وہ غور و خوض اور و تحقیق و آگاہی کی رو سے صحیح نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ گروہ معروف ہوگیا اور انھیں ایک عظیم مقام ملا، یہی چاہے دینی اعتبار سے امت مسلمہ میں خاص اہمیت اور فضیلت کے حامل ہوگئے اور اسی سبب سے ان کی منقولات اسی زمانہ سے مقبولیت پاگئیں...'' مقدمة ابن خلدون، ترجمہ فارسی کی ج۲، ص۸۹۱۔ ۸۹۲ پر رجوع کریں۔ مخصوصاً رجوع کریں کتاب:
Goldziher, Muslim Studies, Vol ۲nd, PP. ۱۵۲-۵۹
(۷۳) مثال کے طور پر جب بعض اصحاب پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم سے سوال کیا گیا کہ جب آپ لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو کس چیز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا: ''ہم شعر پڑھتے ہیں اور جاہلیت کے دور کے واقعات ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔'' فجر الاسلام، ص۹۵، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدر اول کے مسلمان کس قدر میراث جاہلی سے وابستہ تھے ایسے بے شمار نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔
(۷۴)اس موضوع کے تحت نمونہ کے لئے السنة، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن حنبل کی طرف رجوع کریں۔ اس کے ایک نمونہ کو نقل کررہے ہیں: ''عمرو ابن محمد روایت کرتے ہیں کہ میں سالم بن عبداللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کیا زنا کا مرتکب ہونا قضاء و قدر کی وجہ سے ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: ہاں، کیا میرے لئے لکھا جاتا ہے؟ تو کہا: ہاں، کیا میں اس پر عذاب کیا جاؤں گا؟ اس کی طرف پتھر کا ایک ٹکڑا مارا۔'' السنة، ص۱۴۳۔
(۷۵)امیر المومنین حضرت علی ـزمانہ جاہلیت میں عربوں کی طاقت فرسا حالات اور سخت زندگی اور شدید تنگی معاش کی طرف اپنے متعدد خطبوں میں اشارہ کیا ہے۔ بطور نمونہ آپ کے اس خطبہ کی طرف جسے آپ نے عثمان کا مسند خلافت پر آنے کے بعد بیان کیا، کنزالعمال، کی ج۵، ص۷۱۸، پر رجوع کریں۔ اس کے مطابق اس خطبہ میں امامـ نے عربوں کو معیشت کے اعتبار سے فقیرترین افراد اور لباس کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرانا لباس پہننے والوں کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ آپ آنحضرت کے دوسرے خطبہ میں اس مطلب کی طرف جس میں آپ نے اشارے فرمائے ہیں، الغارات نامی کتاب کی ج۱، ص۳۰۲ پر رجوع کریں۔
(۷۶)لیکن مذہب مجبّرہ (جبر کی طرف میلان رکھنے والے) کا سلسلہ معاویہ اور خلفاے بنی مروان کے زمانہ میں شروع ہوا۔ باب ذکر المعتزلہ، خود امویوں کا جبر کی طرف مائل ہونے اور ان کے اشعار سے آگاہی کے لئے آپ الامویون و الخلافة، نامی کتاب کے ص۲۷۔ ۴۷ پر رجوع کریں۔
(۷۷)بہترین لوگوں میں سے ایک شخص جس نے اس واقعہ کی تشریح کی ہے، وہ عبدالرزاق ہیں: ''تمام مسلمین اور عموم علماے اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ حکومت اور قدرت کو خدا سے حاصل کرتا ہے۔ جس عبارت کو ہم ذیل میں بیان کریں گے اس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ یہ لوگ خلیفہ کو زمین پرخدا کا سایہ (ظل اللہ) سمجھتے ہیں اور منصور کا گمان تو یہ تھا کہ وہ زمین پر خدا کا سلطان ہے۔ اس نظریہ کو ابتدائی صدیوں سے ہی علما اور شعرا اپنے اشعار میں اظہار کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خلیفہ کو ہمیشہ خدا انتخاب کرتا ہے اور خلافت کو اس کے سپرد کرتا ہے... یہاں تک کہ کبھی خلیفہ کو خدا کے مقابلہ میں لاکر کھڑا کردیتے ہیں یا اس سے نزدیک قرار دیتے تھے شاعر کے اس شعر کی طرح: جو تم چاہتے ہو وہی ہوکر رہے گا نہ کہ وہ چیز جو مقدر ہوچکی ہے۔ حکمرانی کر کہ تو ہی واحد قہار ہے...۔'' الاسلام واصول الحکم، ص۱۱۷۔ ۱۱۸ا ور اسی طرح ص۱۱۳۔ ۱۲۰ پر بھی رجوع کریں۔ خاص طور سے اسی سلسلہ میں حسن حنفی کے بہت اچھے بیان کا مطالعہ کریں من العقیدة الی الثورة، نامی کتاب کی ج۱، ص۲۱۔ ۲۹ پر رجوع کریں۔
(۷۸)عیون الاخبار، نامی کتاب کی ج۲، ص۲۴۷ پر رجوع کریں۔
(۷۹)اغراض السیاسةفی اعراض الریاسة، ص۲۷۱۔
(۸۰)نظریة الامامة، ص۳۳۴۔
(۸۱)اس مسئلہ میں معتزلی لوگ حسن بصری کو اپنے گروہ میں سے جانتے ہیں باب ذکر المعتزلہ، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن یحی ابن مرتضی، کے ص۱۲۔ ۱۵ پر رجوع کریں۔ حسن بصری نے عبد الملک اور حجاج کو جو خطوط لکھے ہیں ان کے بارے میں آپ سابق حوالہ، کے ص۱۲۔ ۱۴ پر رجوع کریں۔ اور الامویون و الخلافة، نامی کتاب کے ص۳۶ پر بھی رجوع کریں۔
(۸۲)معاویہ کے متعلق حسن بصری نے جو تنقیدیں کی ہیں ان سے اطلاع کے لئے طبقات ابن سعد، نامی کتاب کی ج۱، ص۱۱۹ پر رجوع کریں۔
(۸۳)حسن بصری نے حجاج سے مقابلہ کے لئے لوگوں کو منع کیا تھا اس کے استدلال کی کیفیت معلوم کرنے کے سلسلہ میں الشیعة والحاکمون، نامی کتاب کے ص۲۶ پر رجوع کریں۔
(۸۴)حجاج کی توصیف میں اس نے جو کچھ کہا ہے اس کے لئے آپ الائمة الاربعة، نامی کتاب کی ج۱، ص۲۵۷ پر رجوع کریں۔
(۸۵)اس کے تفصیلی واقعہ کو مقتل الحسین، نامی کتاب مؤلفہ عبدالرزاق مقرم کے ص۴۲۲ و ۴۲۳ پر ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح منتہٰی الآمال، سنگی طبع، ج۱، ص۳۶۲ پر بھی رجوع کریں۔
(۸۶)مفصل واقعہ کو مقتل الحسین، نامی کتاب کے ص۴۵۲اور منتہٰی الآمال، ج۱، ص۳۵۷ پر ملاحظہ کریں۔
(۸۷)الامامة والسیاسة، ج۱، ص۲۰۳۔
(۸۸)سابق حوالہ، ج۱، ص۱۹۱۔
(۸۹)تاریخ طبری، ج۵، ص۲۲۰۔
(۹۰)الامویون والخلافة، ص۲۶۔ ۲۸۔
(۹۱)کنزالعمال، ج۶، ص۴۔ ۸۹۔
(۹۲)سابق حوالہ، ص۳۹۔ ۴۷۔
(۹۳)امویوں کے دور میں ائمہ طاہرین (ع) اور ان کے شیعوں کے علاوہ بہت کم ان کی اندھے اور شل کردینے والے جبر کی مسموم تبلیغات کے مقابلہ میں چھٹ پٹ مخالفت کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ لوگ عموماً آزاد مستقل فکر کے حامل تھے جو فکری، سیاسی اور دینی وجوہات کی بناپر حاکم کے مقابلہ قرار پائے اور ان کے مقابلہ میں عقائدی جنگ کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے جن میں سر فہرست غیلان دمشقی ہیں جو بعد میں اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ہشام کے ہاتھوں قتل کردئے گئے، ان کا شمار انھیں لوگوںمیں سے ہوتا ہے۔ دوسرے نمونہ کے لئے باب ذکر المعتزلة، نامی کتاب کے ص۵۔ ۲۳ پر رجوع کریں۔
''غیلان دمشقی امویوں پر بہت زیادہ تنقیدکرتے تھے۔ اس لئے کہ خلافت کے متعلق ان کے نظریات ان (غیلان دمشقی) کے نزدیک قابل قبول نہیں تھے۔ ان کے ظلم و استبداد کے مقابلہ میں اُٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور علانیہ طورپر امویوں کی کتاب و سنت کی مخالفت کی وجہ سے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ چونکہ امویوں نے حکومت میں فاسق و فاجر افراد کو جمع کرکے کلیدی عہدے عطا کردیئے تھے اور ان کے کارندے لوگوں پر ستم کرتے تھے، وہ ان سے مقابلہ کرتے اور ان کی کرتوتوں کو فاش کردیتے تھے، معروف ہے کہ ہشام نے انھیں قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جس کے نتیجہ میں انھیں ٹکڑے ٹکڑے کردیا گیا۔ اس لئے کہ انھوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا کہ وہ خد اکا خلیفہ ہے، مسلمانوں کے اموال میں بے جا تصرفات کی وجہ سے سینہ سپر ہوجاتے تھے اور ارمنستان کے لوگوں کو اس (ہشام) کے خلاف انقلاب اور قیام کی دعوت دی تھی، الامویون والخلافة، ص۱۷۶۔
غیلان اور ان کی شخصیت، افکار اور ان کے انجام کار کے متعلق معلومات کے لئے ملل ونحل، نامی کتاب کے ص۱۲۷ پر رجوع کریں۔ خصوصاً باب ذکر المعتزلة، نامی کتاب کے ص۱۵۔ ۱۷ پر رجوع کریں؛ جس میں انھوں نے امویوں کے اسراف کے مقابلہ میں شجاعانہ اعتراض کیا ہے، ''اس نے عمرابن عبدالعزیز سے چاہا تاکہ وہ اسے خزانہ اور ردمظالم کو بیچنے پر مامور کردے اور اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ انھوں نے تمام اموال کو تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا اس سامان میں سے ایک (جوراب) موزہ تھا جس کی قیمت تیش ہزار درہم تھی۔ وہ آوازیں لگارہے تھے: ''کون ہے جو یہ کہے کہ یہ لوگ ہدایت کے امام ہیں حالانکہ لوگ اتنے اموال کے ہوتے ہوئے بھوکے مرے جارہے ہیں؟ سابق حوالہ، ص۱۶، قابل توجہ تو یہ ہے کہ غیلان خود اپنے زمانہ میں بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ انھیں کے سلسلہ میں یہ مشہور ہے کہ جب حسن بصری نے ان کو ارکان حج بجالاتے ہوئے دیکھا تو کہا: ''کیا اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ خدا کی قسم وہ شام کے لوگوں پر خدا کی حجت ہے۔ '' باب ذکر المعتزلة، ص۱۵۔
(۹۴)بطور نمونہ اس سلسلہ میں احمد ابن حنبل کے عقائد کی کتاب الائمة الاربعة، نامی کتاب کی ج۴، ص۱۱۹ و ۱۳۰ کی طرف رجوع کریں۔ نیز مناقب الامام احمد ابن حنبل، نامی کتاب مؤلفہ ابن جوزی کے ص۴۲۹۔ ۴۶۲ کی طرف رجوع کریں۔
(۹۵)مرجئہ کہتے ہیں: ''اگر کوئی شخص باایمان ہو تو اسے اس کے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، جیساکہ اگر کوئی شخص کفر اختیار کرے تو اس کی اطاعت کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ان میں سے بعض فرقوںکا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان یعنی خدا کی معرفت اور اس کی بارگاہ میں خضوع ہے۔ قلب سے محبت رکھنا ہے اور جس شخص میں یہ اوصاف جمع ہوجائیں وہ مومن ہے گناہوں پر ارتکاباور اس کی اطاعت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتی اور گناہوں کے مقابلہ میں اسے معذب نہیں کیا جائے گا۔'' الفکر السیاسی الشیعی، نامی کتاب کے ص۶۱ جو شرح مواقف کے آٹھویں جزء سے منقول ہے اس پر رجوع کریں۔
(۹۶)زندقہ اور مرجئہ کی اباحی گری کے سلسلہ میں الزندقة والشعوبیة فی العصر العباسی الاول، نامی کتاب مؤلفہ حسین عطوان پر رجوع کریں۔
(۹۷)مرجئہ کے بارے میں زیادہ جاننے کے لئے حالات اور پیدائش کے سلسلہ میں ان ثقافتی اور معاشرتی حالات کے معلومات کیلئے النظم الاسلامیة، نامی کتاب کے ص۱۳۴۔ ۱۴۹ پر رجوع کریں۔ اور فجر الاسلام، نامی کتاب کے ص۲۷۹۔ ۲۸۲ پر رجوع کریںمرجئہ اور قدریہ کی مذمت میں احادیث سے اطلاع کے لئے السنة، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن حنبل پر رجوع کریں۔
(۹۸)جاہلیت کی ثقافت کی خصوصیات کو معلوم کرنے کیلئے فجر الاسلام، نامی کتاب کے ص۱۔ ۶۶ پر رجوع کریں۔
(۹۹)مہاجرین میں سے ایک شخص نے اس طرح کہا: ''عجمیوں کے بچوں نے بہشت میں گویا نقب لگاکر اس سے باہر آگئے ہیں اور ہمارے بچے تنور میں کالے ہوجانے والے ایندھن کی طرح ہیں۔'' عیون الاخبار، ج۴، ص۴۰۔
(۱۰۰)مثلاً کتاب الاغانی، کے علاوہ آپ دیوان ابونواس کی طرف رجوع کریں، عجیب تو یہ ہے کہ مدینہ میں غنا کا اس حد تک رواج تھا کہ کوفی طعنہ کستے ہوئے کہتے تھے: مدینہ موسیقی اور غنا کا شہر ہے۔ اور معتقد تھے کہ فقہ حنفیوں سے کوفہ میں سیکھنا چاہیئے۔ بطور نمونہ کوفیوں کے اشعار کی طرف جسے انھوں نے ہجو میں کہے ہیں، الائمة الاربعة، کی ج۲، ص۹ اور ۱۰ پر رجوع کریں، البتہ یہ حقیقت ہے کہ یزید کے دور میں مکہ اور مدینہ میں غنا کا دور دورہ تھا۔ فجر الاسلام، نامی کتاب کے ص۸۱ پر رجوع کریں۔ لیکن مقام توجہ تو یہ ہے کہ بربہاری کے جیسا شخص جو بزرگان حنابلہ میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے مدینہ سے ایک خاص قلبی لگاؤ اور ارادت رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سے اس طرح نقل کرتا ہے اور اس کی دوسروں کو بھی وصیت کرتا ہے: ''کوفیوں سے رفض کے علاوہ کوئی چیز، شامیوں سے (منھ زوری) خودسری کے علاوہ کچھ، بصریوں سے قدر کے علاوہ کوئی چیز، خراسانیوں سے ارجاء کے علاوہ کوئی چیز، مکیوں سے صرافی کے علاوہ کوئی اور چیز اور مدینہ میں رہنے والوں سے غنا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ لینا۔ '' اس کے بعد وہ خود اضافہ کرتے ہیں: ان لوگوں سے یہ چیزیں نہ لینا۔ طبقات الحنابلة، ص۷۔
(۱۰۱)حقیقت تو یہ ہے کہ امویوں اور ان کے سرداروں کا فسق و فجور اس حدتک بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنی حاکمیت کو باقی رکھنے کے لئے ایسے راستہ کی تلاش میں تھے جو قابل قبول طریقہ پر ان کو بری کرسکے اور ان کے اعمال کی توجیہ کرسکے (مرجئہ کی فکر کی طرح) اپنی حاکمیت کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہم یہاں پر ان میں سے دو نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
یزید ابن عبد الملک جو یزید ابن معاویہ کا نواسہ تھا اور عمر ابن عبدالعزیز کا جانشین تھا، عیاش اور ہوسران شخص تھا، اس کے پاس حبابہ اور سلامة نامی دو کنیزیں تھیں، جن سے وہ بہت زیادہ عشق کرتا تھا۔ اتفاق سے پہلے سلامہ اور اس کے کچھ دن گذرنے کے بعد بعض لوگوں کے مطابق سترہ دن بعد حبابہ مرگئی۔ لیکن یزید نے حبابہ کو چند دنوں تک دفن نہیں ہونے دیا اور اپنے پاس رکھے رہا۔ اس کے مصاحبین نے اس کی ملامت کرنا شروع کردی تو آخرکار اس نے اس کو دفن کردیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ اس کی قبر کھود ڈالی تاکہ دوبارہ اس کو دیکھ لے اس کے لئے ۔ مآثر الاناقة فی معالم الخلافة، کی ج۱، ص۱۴۵اور ۱۴۶ پر رجوع کریں۔
صاحب اغانی نقل کرتا ہے کہ عبداللہ ابن مروان نے حارث ابن خالد مخزومی کو مکہ کا والی بنادیا حارث طلحہ کی بیٹی عائشہ کا عاشق ہوجاتا ہے۔ عائشہ نے حارث کو پیغام کہلوایا کہ وہ نماز میں دیر کردے یہاں تک کہ میں اپنے طواف کو تمام کرلوں۔ حارث نے بھی مؤذنوں کو دستور دے دیا کہ وہ نماز میں دیر کریں یہاں تک کہ عائشہ اپنے طواف کو انجام دے لیں حاجیوں کو یہ بات بہت بری لگی اور بہت گراں گذری۔ یہاں تک کہ عبداللہ نے اس کو معزول کردیا۔ فجر الاسلام، ص۸۲ منقول از الاغانی، ج۳، ص۱۰۳۔ اور ابو حمزہ خارجی کی زندہ توصیف کو بھی جسے اس نے عبدالملک کے لئے اپنے خطبہ کے ضمن میں مکہ میں تقریر کی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ اس کا اخلاقی فساد، شہوترانی، صرف بیجا اور حبابہ اور سلامہ کی داستان کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ البیان والتبیین، کی ج۲، ص۱۰۱ پر رجوع کریں۔
اغانی کی یہ فسق و فجور سے بھری ہوئی گذارش ( Report ) جو اس نے اموی اور عباسی خلفا کے بارے میں بیان کی ہے اتنی زیادہ ذلیل کرنے والی ہے کہ اہل سنت کے پختہ لوگ مؤلف اور کتاب دونوں ہی کو غلط کہنے پر لگ گئے ہیں۔ قدما میں آپ العواصم من القواصم، نامی کتاب کے ص۴۹۔ ۲۵۱ پر رجوع کیجئے۔ اور دور حاضر میں آپ مؤلفات فی المیزان، نامی کتاب کے ص۱۰۰۔ ۱۰۳ کی طرف رجوع کریں۔
چوتھی فصل
قدرت اور عدالت
ہم نے گذشتہ بحثوں میں اہل تسنن اور اہل تشیع کے سیاسی اصول میں سے دو اہم اصلول کے سلسلہ میں بحث کی اور یہ کہ ان دونوں میں نظریاتی اعتبار سے کیا فرق ہے اور عملی طور پر تاریخ اور روحی اور معاشرتی عمارت کے لحاظ سے ان لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو کس طرح ان کی پرورش کی ہے؟ ہم اس فصل میں تیسری اصل کے سلسلہ میں بحث اور چھان بین کریں گے اور پھر اصلی بحث یعنی تشیع و تسنن کے معیار تاریخ کو معاصر میں بیان کرکے ان دونوں کے درمیان فرق کو بیان کریں گے۔
جیساکہ گذشتہ فصل میں اس مطلب کو واضح کیا گیا ہے کہ اہل سنت کے سیاسی فکر کے جنم لینے میں جو عامل بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ قدرت کے تحفظ اور ایسی طاقت جو امنیت اور تحفظ کے ایجاد کرنے پر قادر ہے اس کے بارے میں حساس ہیں۔ حالنکہ اہل تشیع عدالت اور پیغمبر کی سنت کو ہو بہ ہو اسی انداز میں لاگو کرنے میں جس طرح آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کے دور حیات میں جاری و ساری تھی نہ وہ عدالت جس کی بعد میں تفسیر یا تعبیر کردی گئی ہے، اس سلسلہ میں اپنی احساسی ت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو چیز اہمیت بلکہ لازم اور قابل احترام اور تقدس کی حامل ہے ایک طرح سے محض ایک شجاع قوی، باعظمت ہونے اور شان و شوکت کے حامل ہونے سے تعبیر کی گئی ہے جس کے سایہ میں امنیت اور تحفظ حاصل ہوتا ہے خواہ وہ امنیت اندرونی سرکشوں، باغیوں اور اشرار کے مقابل اورہو خواہ خارجی حملہ آورں اور تجاوز گروں کے مقابل ہو وہ پوری ہو جاتی ہے اگرچہ یہ بات ایک حدتک شیعوں کے نزدیک تائید شدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمامی اقدار اور عظمت کو اسے دے دے اور اسے بلا قید و شرط درست مان لیا جائے۔ اس لئے کہ مطلق قدرت نہ تو شیعوں کے کلامی اور فقہی اصول اور معیار کے مطابق ہے اور نہ ہی ائمہ اطہار (ع) کی سیرت اور روش اس کی تائید کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اصل اہل تسنن کے درمیان کیوں اور کیسے وجود میں آئی اور کن اسباب و عوامل سے اثر انداز ہوئی ہے۔
مختصر طورپر ہمیں یہ کہنا چاہئے کہ اس دوران تین اہم عامل اس میں دخیل رہے ہیں پہلا عامل مفہوم عدالت ہے، یہ مفہوم ان لوگوں کے درمیان شیعوں کے نزدیک پائے جانے والے عدالت کے فقہی و کلامی اور فلسفی مفہوم سے متفاوت ہے۔ دوسرا عامل قدیم زمانہ میں حکومتوں کے فرائض ہیں اور آخرکار تیسرا عامل تاریخی واقعیتوں اور ضرورتوں سے متعلق ہے کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے سلسلہ میں مفصل بحث کریں گے۔
مفہوم عدالت
شیعوں اور سنیوںکے نزدیک اس کی وضاحت کرنے سے کہیں زیادہ عدالت کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ واضح و روشن ہے اگرچہ معتزلی، مفہوم۔ عدالت کو درک کرنے کے لحاظ سے شیعوں سے نزدیک ہیں اور بعض موارد میں ایک ہی جیسے تھے، لیکن اشاعرہ نے جس مفہوم کو اخذ کیا ہے اس میں شیعوں سے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے اور بعد میں یہی مکتب رائج ہوگیا اور اہل سنت کے اعتقادی اور فقہی مسائل اس کے زیراثر پھولے پھلے اور پروان چڑھے ۔
لیکن اس درمیان اہمیت کا حامل یہ تھا کہ عدالت کی جس تفسیر کو اشاعرہ نے پیش کیا وہ اصولاً اس طرح سے تھی کہ مفہوم عدالت کی قدروقیمت گھٹارہی تھی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اسے اہم اور حائز اہمیت سمجھتے تھے لیکن اس کی دوسری تفسیر کر رہی تھے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اول ہی سے مفہوم عدالت کی اس طرح تفسیر کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اپنی اہمیت کوختم کردیاتھا اور شاید ان کا مقصود بھی یہی رہا ہو۔انھوں نے جب حُسن و قُبح عقلی کا انکار کردیا در حقیقت انھوں نے عدالت کے مفہوم کو اس حدتک گرادیا کہ وہ ہر ظالمانہ اور جبارانہ عمل سے تطبیق دینے کے لائق ہو گا۔ بعبارت دیگر عدالت کی فکر اور آرزو جو بھی رہی ہے اپنی واقعیت کی حد سے نیچے آگئی اور قضاوت کا معیار، موجودہ حقیقت بن گیا نہ کہ اس بلند و بر تر اور وسیع مفہوم اور اس کے بارے میں قضاوت اور فیصلہ کیا جائے اور جب ایسا ہو ہی گیا تو اب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اسے اس کے برترمفہوم سے مطابقت دی جائے یا مطابقت نہ دی جائے، جب حُسن و قُبح عقلی کو نظر انداز کردیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً عدالت کے مفہوم اور اس کی ماہیت سے چشم پوشی کرلی گئی ہے اور نہ یہ کہ اس نفی کی بنیاد پر اس کے لئے کوئی دوسری نئی تعریف پیش کی گئی ہے۔(۱)
عدالت کی ایسی تفسیر موجودہ واقعیت سے بالاتر ہر قسم کی آرزو کو رد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے عملی طور پر ایسا وقوع پذیر بھی ہوچکا ہے۔ اس مقام پر ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ عدالت کیا ہے یا اس کی رعایت ہوتی ہے یا نہیں؟ اصولی طورپر موجودہ صورت حال سے بہتر کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی ہے تاکہ اس کی بنیاد پر عدالت کی تعریف اور موجودہ صورت حال کی چھان بین کی جاسکے۔(۲)
کتاب المواقف کے مشہور مؤلف جو اشعری مذہب کے ایک عظیم عقلی رجحان کے مالک اور با ہوش متکلم ہیں وہ حسن و قبح عقلی کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ہر وہ شیٔ قبیح ہے جسے شریعت اسلامی قبیح قرار دے اور حسن اس کے بر خلاف ہے۔ عقل کے پاس اختیار حسن و قبح کو پہچاننے کے لئے کوئی معیار نہیں ہے اور یہ دونوں کسی دوسرے واقعی اور حقیقی امر انسان کے فعل کی طرف نہیںپلٹ تے ہیں تا کہ شریعت اس سے پردہ ہٹائے بلکہ یہ شریعت اسلامی ہے جو حسن و قبح کو وجود میں لاتی اور اس کی تعریف و توضیح کرتی ہے اور اگر مسئلہ برعکس ہو جائے یعنی جو چیز قبیح اور بری ہے اسے حسن اور خوباور خوب اور حسن کو قبیح اور زشت شمار کرے تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے اور نتیجہ بھی برعکس ہوجائے گا۔
لیکن معتزلیوں کا کہنا ہے کہ حسن و قبح کی تشخیص کا معیار عقل ہے اور ایک انسان کا عمل بذاتہ یا اچھا ہے یا برا اور شریعت انھیں واقعیات کو کشف اور آشکارکرتی ہے، اب اس صورت میں نا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ مسئلہ برعکس ہو جائے۔ اس لئے کہ خوبی و بدی ہمیشہ واقعی اور حقیقی امر کی طرف پلٹتی ہے نہ کہ فرضی اور اعتباری امور میں۔(۳)
جیسا کہ ہم نے بیان کیا خوب و بد کی ایسی تفسیر اور اس کے معیارمفہوم عدالت کے لئے کوئی گنجائش اور بنیادی طور پر عقل کا بھی کوئی مقام باقی نہیں رہ جا ئے گا اور سب سے زیادہ حائز احادیث اور دینی نصوص کے صحت و سقم کو تشخیص دینے والے عقلانی معیاروں اور موازین، خاص طور سے احادیث کے عقلی معیار کی نابودی کا باعث بھی ہوگا اور اس طرح کسی بھی ظلم وستم کو قبول کرنے کے لئے فکری، دینی، اعتقادی اہمیت اور نفسیاتی راہ ہموار کرنے کا باعث ہے وہ بھی دینی اور شرعی قبولیت کا باعث ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ظالمانہ اور فاسقانہ عمل کے لئے حالت فراہم کردے گا۔ اس طرح سے حکام اور علمائے سوء کو قانونی حیثیت حاصل ہوجائے گی اور انہیں بہترین پشت پناہ مل جائے گا تاکہ وہ اپنی خلاف و رزیوں اور مظالم کو دینی رنگ دیکر اپنی من مانی کریں اور جو چیز چاہیں اسے حاصل کرلیں گے اور زیاد اہمیت کا حامل یہ کہ دین بھی اس قابلیت کو پالے گا تاکہ وہ اس طرح اس سے سوئے استفادہ کرسکیں۔(۴)
معاشرہ کے قوی اور مقتدر افراد کا دین کے نام پر ناجائز استفادہ کرنا یہ بہانہ بناتے ہوئے کہ عقل خطا کرسکتی ہے، ان کے ہمراہ رہا ہے۔ جب عقل اپنی تمامتوانائیوں اور حدو داربعہ سے گریزاں ہو کر میدان چھوڑ دے، خصوصاً دینی مفاہیم میں تو ظلم و بربریت اور خرافات اس کی جگہ حاکم ہوجائیں گی اور ایسے واقعات دین سے سوئے استفادہ کرنے والوں کا ہمیشہ سے مطلوب رہے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے جب حساس ترین اور سب سے زیادہ اہمیت کے حامل دینی مباحث میں سے ایک، مسئلہ عدالت، اگر غلط قرار دے دیا جائے تو خوا مخواہ ایسے نتایئج حاصل ہونگے۔
دو مختلف تفسیروں کے نتائج
اس مقام پر اس نکتہ کو اضافہ کرنا بھی ضروری ہے کہ عدالت کے مسئلہ میں معتزلہ، شیعہ اور اشاعرہ کا مفہوم عدالت میں اختلاف موجب نہیں بنا کہ وہ پوری تاریخ میں اپنے معاشرتی اور سیاسی نظام کی اساسی بنیاد ڈالیں بلکہ یہ دونوں گروہ کم و بیش عمل میں یکساں رہے ہیں اور اصل عدالت کا عقیدہ رکھنا سیاسی اور معاشرتی عدالت کو اپنے ہمراہ نہیں لایا۔ مامون و معتصم اور واثق کے دربار میں موجود معتزلیوں اور قبل و بعد کے اشعریوں اور اشعری رجحان رکھنے والوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں تھا، اگرچہ مذکورہ خلفا اور خصوصاً مامون، کہ اس کے قبل و بعد کے دوسرے خلفا کے مقابلہ میں اس کی روش میں محسوس فرق پایا جاتا تھا اور اس کا ایسا ہونا اس کی فکری آزادی اور علمی شخصیت ہونے کی وجہ سے تھا نہ یہ کہ اس قریبی معتزلی مصاحیین کی یاد آوری اور توجہات اس بات کی باعث ہو ئی ہیں۔(۵)
شیعہ بھی کافی حد تک اس حکم میں شامل ہیں اور اس واقعیت کو بمشکل قبول کیا جا سکتا ہے کہ طول تاریخ میں شیعہ سلاطین سنی سلاطین کے مقابلہ میں بیشتر عدالت کے حامل رہے ہیں۔(۶) اسلامی شرق میں سلاطین کی عدالت دوستی اور عدالت کا وسیع کرنا جہاں سماجی امور کو ادارہ کرنے کے لئے سیاسی اور معاشرتی کمیٹیوں کا مصالح اور اقتضاکی بنا پر فقدان تھا اور ان کے ذاتی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور تمام چیزوں سے زیادہ جہاں وہ حکومت کرتے تھے اس میں اندرونی خواہشات اور ذاتی رجحان کو عمل دخل تھا۔
لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ دونوں یعنی معتزلی اور بالخصوص اشاعرہ اور شیعہ اپنے معاشرتی اقدام کے مرحلہ میں ایک نظام حاکم کو درست کرنے کے لئے یا اس کو ختم کرکے ایک عادلانہ نظام کی بنیاد ڈالنا دو قسم کا تھا اور دو طرح سے عمل کیا ہے۔ بعبارت دیگر جس طرح سے ان دونوں نے تفسیر کی بھی اس کے مطابق عدالت کے عقیدہ رکھنے کا نتیجہ حاکم کے سامنے استقامت اور پائیداری سے معلوم ہوجائے گا۔ سب سے اہم ترین عوامل میں سے ایک عامل جو شیعوں اور معتزلیوں کو جبردوست، جبر کی ترویج کرنے والے جباروں کے مقابل استقامت اور پائیداری کی دعوت دیتا ہے وہ ان لوگوں کا مسئلہ عدالت کا درک کرنا ہے۔(۷) اور چونکہ ایسی تفسیر سرے سے ہی اشعریوں کی توجہ اور اعتقاد کا مرکز نہیں تھی لہٰذا معنیٰ ہی نہیں رکھتا کہ اس کے سہارے سلطان کے سامنے وہ قیام کرتے۔ وہ لوگ حسن و قبح عقلی کا انکار کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک موجودہ واقعیت سے بالاتر تشخیص دینے کے لئے جو معیار ہونا چاہیئے تھا وہ معیار بھی موجود نہیں تھا۔
اسی وجہ سے معتزلیوں اور خاص طور سے شیعوں کے نزدیک بہت زیادہ عدالت طلب تحریکوں کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے مشابہ نمونے اشعریوں، اہل حدیث اور سلفیوں کی تاریخ میں مشاہدہ نہیں ہوتا۔ جو چیز عملی طور سے ان لوگوں کے درمیان موجود رہا ہے اور اب بھی ہے ان کے بقول وہ ایسی تحریکیں تھیں جو بدعتوں کو ختم کرنے اور سنت کو باقی رکھنے اور اس کے دفاع کے عنوان سے رہی ہیں۔(۸)
البتہ ان دونوں کا مفہوم عدالت کے بارے میں مختلف تفسیر یا ادراک تنہا عامل موجب نہیں ہوا ہے۔ بلکہ اس عامل کے علاوہ دوسرے عوامل بھی موجود تھے لیکن بلا شک و شبہہ فہم بہت ہی اہم حصہ کا حامل ہے اور اسی اہمیت کا حامل رہے گا۔ بعبارت دیگر اگرچہ اصل عدالت کا عقیدہ عملی طور پر سیاسی اور معاشرتی عدالت کا تحفہ نہ لاپایا لیکن تنہا اسے قبول کر لینا عدالت خواہی کو وجود میں لانے کے لئے بہترین سبب تھا۔
اسلام کی پوری تاریخ میں عدالت اور آزادی خواہی کی تحریکوں کی داستان خود اس نکتہ کی بہترین مؤید ہے۔ اور ایسے قیام کااہل حدیث اور اشعری مسلک میں نام و نشان بھی نہیں ملتاجبکہ تشیع اور معتزلہ کے یہاں ایسی تحریکوں کے بے شمار شواہد پائے جاتے ہیں۔ اور یہ رابطے اس قدر اطمینان بخش اور قوی تھے کہ ایسے زمانوں میں جب بعض اسباب کے تحت ایسے رجحانات وجود میں آئے تو معتزلہ کی فکر کے استقبال اور خاص طور سے شیعی افکار کے حالات فراہم ہوگئے۔ اگرچہ شیعی افکار اور عقائد بعض مختلف دلائل کے سبب عدالت کے اصل اعتقاد سے کہیں زیادہ قابل قبول ہوا، لیکن ہر صورت میں اس اصل پر عقیدہ رکھنا اساسی اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔
اور یہی وہ تنہا عامل تھا کہ جس کی وجہ سے معتزلہ اور مخصوصا شیعہ حکام اور صاحبان اقتدار اور وہ علما اور جو مبلغین ان سے وابستہ تھے ان کی جانب سے ہونے والے حملوں کا شکار رہے ہیں۔ ایک سماج میں حاکم استبداد خود ہی عدالت خواہی اور حریت طلبی کو فروغ دینے کا اصلی موجب تھا۔ لیکن چونکہ یہ اسلامی فکر، حاکم وقت کے ہاتھوں رواج پارہی تھی اور چہ بسا پروان چڑھ رہی تھی اصل مفہوم عدالت پر عقیدہ نہ رکھنے کی بناپر اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں قاصر تھے، لہٰذا انقلابی لوگ اس بات پر مجبور تھے کہ ان مذاہب کی پناہ لیں جو عدالت خواہی کے حامی اور اس کی تشویق کرتے تھے(۹) اور چونکہ معتزلہ اور شیعہ ایسے تھے لہٰذا ان کے بدنام کرنے کے لئے بہت زیادہ کوشش کی گئی اور ان سے منحرف کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ البتہ ان کی یہ کوششیں بے نتیجہ بھی نہیں تھی، اس لئے کہ آج معتزلہ اور شیعیت کی نسبت جو بھی بدگمانیاں اہل سنت کے نزدیک ہیں وہ سب اسی غلط پروپیگنڈوں اور سوئے تبلیغات کا نتیجہ تھیں۔(۱۰)
ابھی تک جو بحث کی گئی ہے عدالت کے کلامی مفہوم کے بارے میں تھی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا فقہی مفہوم کیا تھا؟ اور اس کے کیا آثار رونما ہوئے؟ اس مقام پر اس کے پہلے مورد کے برخلاف، معتزلی بھی غیر معتزلی کی طرح ہیں اختلاف صرف شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان ہے۔
عدالت کا فقہی مفہوم
واقعیت تو یہ ہے کہ عدالت کا یہ مفہوم اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک فقہی لحاظ سے زیادہ فرق نہیں ہے صرف بنیادی اختلاف ان موارد میںہے کہ جہاں عدالت کو اساسی شرط مانا گیا ہے کہ اس میں سب سے اہم اور فیصلہ کن امام جماعت، امام جمعہ اور حاکم میں ہے۔ شیعوں کے نزدیک ان تمام موارد میں عدالت کو شرط مانا گیا ہے لیکن اہل سنت امام جمعہ و جماعت کے بارے میں اس شرط کے قائل نہیں ہیں اور صرف ان میں سے بعض افراد فاسق اور بدعت گذار کی امامت کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔(۱۱) جیساکہ ان میں سے اکثر حاکم میں بھی عدالت کو شرط نہیں مانتے ہیں۔
وہ چیز جو اس بحث میں قابل اہمیت ہے، امام جمعہ اور جماعت کا عادل ہونا ہے۔ اس لئے کہ حاکم کے عادل ہونے کا مسئلہ خود ان لوگوں کے نزدیک ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ اختلاف کن نتائج کو اپنے ہمراہ لئے ہے؟
اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ایک نکتہ کے سلسلہ میں یاد دہانی نہایت ضروری ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ صدر اسلام میں نماز جماعت اور نماز جمعہ کو کیا حیثیت اور مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ اس دور میں سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے نماز جمعہ و جماعت آج سے کہیں زیادہ قابل اہمیت تھی۔ یہ دونوں اور مخصوصاً نماز جمعہ اسلامی ہونے کا راز، اس کے اتحاد اور آخرکار معاشرہ میں ثبات و امنیت کی علامت تھی۔ اس میں شریک ہونے والوں کے افکار و عقیدہ کی سلامتی اور تمام مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کی بناپر عدم انحراف کی پہچان تھی۔(۱۲) یعنی اس بات کی علامت تھا کہ سماج اور معاشرہ حاکم وقت کے فرمان کو قبول کرتا ہے اور اس کے سامنے تسلیم ہے۔ اسی نماز کے ذریعہ حکام، سلاطین اور خلفا کو قانونی حیثیت کو حاصل کرلیتے تھے اور ان کی قدرت اور حیثیت کو استحکام اور پختگی حاصل ہوتی تھی۔
اس دور میں شہروں کی وسعتیں آج کی طرح نہ تھیں، بلکہ ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا اور اس میں مختصر سی آبادی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس شہر کے رہنے والے تمام لوگ خاص طور سے مرد حضرات نماز جماعت میں شرکت کو ضروری سمجھتے تھے۔ بعض مواقع پر نماز میں شرکت کو واجب امر کی حیثیت رکھتی تھی۔(۱۳) نماز جماعت کو اہل سنت کے بعض فقہا اور نماز جمعہ کو تمام فقہا واجب سمجھتے ہیں۔ مذہب امامیہ کے فقہا کے نزدیک بھی جبکہ امامـ موجود ہوں، نماز جمعہ میں شرکت واجب ہے۔ بلکہ بعض فقہائے امامیہ امام معصوم کی غیبت میں بھی اگر اس کے تمام شرائط پورے ہورہے ہوں تو اس کے قائم کو واجب قرار دیتے ہیں، یہی وہ اسباب ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں نمازیں فطری طورپر حددرجہ سیاسی اہمیت کی حامل ہوگئیں اس حدتک کہ یہ اسلام کی پہچان اور سماجی اتحاد کا باعث ہوگئیں۔(۱۴)
مذکورہ بالا نکات اور اس کی حساسیت پر توجہ دیتے ہوئے ایسی صورت میں معاشرہ کے برجستہ ترین افراد کے علاوہ خواہ ظاہری اعتبار سے افضل کیوں نہ ہوں، ایسی نماز کی امامت کو کس فرد کے سپرد کیا جاسکتا ہے۔ ایسی نماز کی امامت کو جو مؤمنین کی جماعت کا آئینہ دار اور معاشرہ کی وحدت کا رمز نیز اس کے ثبات کا موجب ہے، ایسے فرد کے علاوہ ان امور کو کسی اور کے حوالہ کرنا معنی نہیں رکھتا تھا عوام بھی اس کے علاوہ کوئی اور توقع نہیں رکھتے تھے۔ اس سے قطع نظر فقہی معیار بھی اسی مطلب کی تائید اور حمایت کرتے تھے۔ بلکہ اس مقام پر یہ کہنا بہتر ہے کہ عوام الناس نماز جمعہ و جماعت اور اس کی امامت ظواہر شریعت کے موافق اور مطابق جانتی ہے۔(۱۵) شارع برجستہ ترین افراد کو اس عہدہ کو دینے کا خواہاں تھا اگرچہ بعد میں سیاسی اور اجتماعی مجبوریوں اور ناجائز دباؤ کی وجہ سے برجستگی اور ممتاز ہونے کا مفہوم اور مصداق بدل دیا گیا۔
آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کے دور میں ان دو (جمعہ و جماعت) نمازوں کی امامت خود مدینہ میں اور دوسرے علاقو میاا جہاں پر آپ موجود رہے تھے میں آپ کے ذمہ تھی اور آپ کی غیبت میں وہ فرد ان دو نمازوں کی جماعت کا عہدہ دار ہوتا تھا جسے آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت نے نمائندہ، جانشین، امیر اور حاکم کے عنوان سے معین فرمایا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوگئی تو ان دو نمازوں کی امامت خلیفہ اول کے ذمہ تھی نیز اس خلافت کے ابتدائی ایام میں ان دونمازوں نے اس خلافت کو مستحکم اور قبولیت اور ثبات بخشنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔(۱۶) یہ روش خلفائے راشدین کی خلافت کے آخر تک بر قرار رہی اور جب امویوں کا دور آیا تو بھی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔(۱۷)
مثال کے طورپر محقق کرکی نماز جمعہ قائم کرنے یا امام جمعہ کے نصب ہونے کے لئے امام معصوم یا نائب خاص یا نائب عام کی اجازت کو لازم قرار دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں:... اس مسئلہ میں اجماع سے پہلے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم اپنے دور میں ائمہ جماعت اور قضات کو معین فرماتے تھے۔ اسی روش کو آپصلىاللهعليهوآلهوسلم کے بعد خلفا نے جاری رکھا لہٰذا کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ امام یا نائب امام کی اجازت کے بغیر قاضی بن جائے اور اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو امام جمعہ قرار دے لے۔ اور یہ قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دائمی استدلال ہے اور اس کی مخالفت اجماع کی خلاف ورزی ہے۔(۱۸)
اور پدرسن کچھ اس طرح نقل کرتا ہے:
''اسلام کی ابتدا ہی سے نماز کی امامت حاکم کے ہی ہاتھ میں تھی۔ وہی جنگ میں سپہ سالار حکومت کا رئیس ، تمام نمازوں میں امام جماعت ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں منصوب والیوں کی روش تھی کہ وہ خود نمازوں کی امامت اور خراج لیا کرتے تھے۔ نماز کی امامت اور مخصوصا نماز جمعہ کی امامت اور اسکے خطبہ دنیا حاکم کے ذمہ ہوتا تھا۔ اس کے نہ ہونے کی صورت میں فوج کا کمانڈر اس کے کاموں کا عہدہ دار ہوا کرتا تھا ۔لیکن یہ روش عباسیوں کے دور میں بدل گئی اور اس کے بعد نمازوں کی سلسلہ وار امامت حاکم کے ہاتھ میں نہیں رہی۔''(۱۹)
جو روش خلفا راشدین کے دور میں تھی وہ بہت زیادہ مشکل ساز نہیں تھی۔ پہلے والے دوخلیفہ اور ان کے منصوبین شرع کے ظاہری احکام کی رعایت کرتے تھے۔ اگرچہ عثمان کے دور میں مخصوصا نصف دوم میں، حالت بد ل گئی اور ولید بن عقبہ جیسے افراد والی بنادئے گئے، کوفہ میں منصوب والی شراب کے نشہ میں نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور نماز صبح کو دو رکعت کے بدلے چار رکعت پڑھ دیا اور شراب نوشی میں افراط کی وجہ سے وہیں مسجد کے محراب میںقے کر کے آلودہ کردیا(۲۰) لیکن یہ موارد (حوادث) بہت زیادہ ایسے نہیں تھے کہ جنھیں نظر انداز کیا جاسکے اس دور کے بعد امام علی ـ کا دور تو مکمل آشکار ہے اور اساسی طور پر اس لحاظ سے اس دور میں کوئی مشکل نہیں تھی اور آپ کے زمانے میں ایسی مشکلات ہو بھی نہیں سکتی تھیں۔
بلکہ یہ مشکلات امویوں کے دور سے شروع ہوئیں اور روز بروز سنجیدہ ہو تی گئیںاور ایک لا ینحل مشکل کی صورت اختیار کرلی اور انہیں واقعات کے ساتھ ساتھ عدالت ِامام جمعہ و جماعت واقعیت اور ضرورت کے زیر اثر قرار پاگئی اور۔ وقت کی مصلحتوںکا شکار ہوگئی اور اس بعد اس کی مختلف تفسرین اور عذر اشیاں ہونے لگتیںاور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اآہستہ آہستہ تنزلی پر گامزن ہو گئی کہ اصولاً عدالت کے بارے میں غفلت برتی گئی اور بعد میںسے پوری طرح بھلادیا گیا۔
آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت :اور خلفائے راشدین کے دور کی میراث کا تقاضا یہ تھا کہ آنے والے خلفا اور ان کے حکام ان والی لوگ، ان کے نمایندے اور اس کے نماز جمعہ و جماعت کی امامت کو خود انجام دیتے رہے ہیں۔اموی خلفا اس سے کم پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ انجام دیا وہ اس وجہ سے انجام نہیں دیاکہ وہ پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی سنت اور خلفا راشدین کے طور و طریقہ کو لا گو کر رہے تھے بلکہ وہ تو تنہا اس واسطے تھا کہ اس کو چھوڑ دینا حکومت اور ان کی مشروعیت اور قانونی حیژیت پانے کے مغایر اور مخالف تھا وہ لوگ قدرت اور حکومت چاہتے تھے اور یہ اسی اور یہ چیزیں اسی وقت مل سکتی تھیں جب حاکم اور صاحب قدر نماز جمعہ و جماعت کو برپا کریں اور اسکی امامت کو انجام دیں، چونکہ ایسا تھا لہٰذا وہ (اموی حکام ) ان دو نمازوں کی امامت کے فرائض کو خدہی انجام دیتے تھے۔
اس دور میں یہ ایک ضرورت بھی تھی اگر ہم اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اموی نماز و جماعت کی امامت اور خاص طور سے جمعہ کی امامت کے فرائض کو انجام دینے کی طرف بہت مائل نہیں تھے۔ اس لئے کہ امام جمعہ اس بات کے لئے مجبور تھا کہ وہ خود نماز جمعہ کا خطبہ دے اور یہ بات ان کے لئے دشوار تھی۔اس سلسلہ میں گلڈ زیہراس نکتہ کے ضمن میں کہتا ہے:'' اموی خلفا کے لئے خطبہ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن وہ خطبہ دینے کے لئے مجبور تھے تاکہ وہ اس طرح سے لوگو کواپنی ریاست اور امور داری کی تلقین اور یاد دہانی کراسکیں۔ عبدالملک سے جب سوال کیا گیا کہ کیوں اتنی جلدی تمھاری داڑھی سفید ہوگئی ہے ؟تو اس نے جواب میں کہا:'' میری داڑھی سفید کیوں نہ ہو جائے حالا نکہ ہفتہ میں ایک بار خطبہ دینے اور اپنی فکر کو دوسروں کی قضاوت کے لئے پیش کرنے پر مجبور ہوں...۔(۲۱)
خطبہ دینا تنہا اموی خلفا کے لئے سخت نہیں تھا۔ بلکہ ان کی طرف سے منصوب والیوں کے لئے بھی محبوب نہیں تھا۔ یہاں تک کہ خطابت میں مشہور، عبید اللہ ابن زیاد اسے اپنی امارت کی نعمت کے لئے منحوس مانتا تھا۔(۲۲) ایک دوسرا والی لوگوں کے سامنے اس طرح اقرار کرتا ہے:'' امامت سے پہلے جمعہ میرے لئے دنوں میں بہترین دن تھا لیکن یہی اب میرے نزدیک بدترین دنوں میں سے ایک دن ہے اس لئے کہ اس میںخطبہ دینے کے لئے مجبور ہوتا ہوں۔''(۲۳)
دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ خود مسلمین جماعتوں اور جمعہ میں شریک ہونے پر مجبور تھے۔ گذشتہ بزرگوں کی سیرت بھی اس بات کی مقتضی تھی اور دینی نصوص بھی اس کی سفارش کررہی تھیں۔ بلکہ یہ شرعی فرائض میں سے ایک فریضہ تھا۔ لیکن اس مقام پر اس مطلب کااضافہ کرنا ضروری ہے کے اسلام کے آغاز میں حتیٰ رسول اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی حیات میں ،لوگوں سے نمازجمعہ و جماعت میں شرکت کا مطالبہ کیا جاتا تھا تاکہ جماعتوں اور جمعے میں شرکت کریں اور اس امر سے گریز کرنے والوں کو سخت سزا دی جاتی تھی۔(۲۴) یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک فرد نماز جماعت اور جمعہ مخصوصا نماز جمعہ میں شریک نہ ہو نا ایک واجب کا چھوڑ دیناہے بلکہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان نماز وں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو ان نمازوں میں شریک ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا، اس لئے اس کا نماز میں شریک نہ ہونا لوگوں کی طرف سے بعض یا تمام موا رد میں دین کو چھوڑ دینے کے معنی میں تھا، یا موجودہ حاکمیت کے انکار یا کم از کم اس کو قانونی اور جائز نہ سمجھنے اور واجب الاطاعة نہ ماننے کے مترادف تھا۔ اور کوئی بھی اموی حاکم مخصوصا اموی ظالم حکام کے لئے قابل تحمل نہیں تھا۔(۲۵)
شرط عدالت کا انکار
ان حالات اور مجبوریوں کے ہوتے ہوئے ان کے پاس اس کے، علاوہ کوئی اور چارۂ کارہی نہیں تھا کہ وہ (اموی حکام)نماز جمعہ و جماعت میں امام کی عدالت کا انکار کردیں۔ امویوں خاندان کی سب سے زیادہ پابند فردعمر بن عبد العزیز کے علاوہ کہ وہ کاملاً ایک استثنائی انسان تھا، ایک عنوان سے خود معاویہ تھا۔ اس کی رفتار اس چیز سے جس کی رعایت شرع کی نظر اور گذشتہ خلفا کی روش میں کم سے کم ضروری اور قابل عمل تھی ،دونوں میں بڑا فرق تھا (کہیں سے دیندار نہیں لگ رہے تھے۔) اس نے آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت اور خلفا راشدین کے دور میں رائج نماز جمعہ کو ایک دوسرے انداز میں ادا کی۔( وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے نماز جمعہ کے خطبہ کو بیٹھ کر پڑھا۔)(۲۶) اس کے بعد خلفا اور حکمرانوں کی حالت اس سے کہیںبد تر ہوگئی گویا وہ پوری طرح دین سے بیگانہ ہوچکے ہیں۔ ان کی فکریں شہوت رانی اور ریاست کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتی تھیں۔ قدرت انھیں لوگوں کے ہاتھ میں تھی اور نماز جماعت اور جمعہ کی امامت بھی خود وہی لوگ کیا کرتے تھے اور عوام لوگ بھی نماز میں ان کی اقتدا کرنے پر مجبور تھے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کی اقتدا میں پڑھی جانے والی نمازیں کفایت کریں گی یا نہیں؟ اور یہ خود مسئلہ اس کی فرع بھی کہ ان نمازوں کی امامت کرنے والا انسان جامع الشرائط بھی ہے یا نہیں ؟اور اصولی طورپر وہ شرائط کیا ہیں ؟ عدالت اور گناہوں سے پرہیز یا لااقل عدم تکرار اس کی شرائط میں سے ہے یا نہیں؟ کیا اس بات کا امکان پایاجاتا ہے کہ اس فاسق و فاجر اور جائر فرد کو امام جماعت بنا دیا جائے؟ جو کسی بھی ظلم کے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، یا ایسے فرد کو امام جماعت نہیں بنایا جاسکتا؟ اس کی پہلی صورت میں کیا اس امام کی اقتدا کرنے والوں کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟
لہٰذا ان سب کا اصلی راہ حل یہ تھا کہ اس میں امام کی عدالت کا ہی سرِے سے انکار کردیا جائے۔ البتہ اگرامویوں کے آتے ہی یہ تغیر آجاتا تو پھر حاکمیت اور حاکم کی مشروعیت اور امام جمعہ و جماعت میں کوئی تلازم باقی نہ رہ جاتا اور قوی احتمال کی بناپر اس مقام پر بھی عدالت دوسرے مواردکی طرح جیسے قاضی اور گواہ وغیرہ کے لئے بھی قابل انکار نہ ہوتی۔ لیکن ایسا نہ ہوسکا لہٰذا ان لوگوں نے امام جمعہ و جماعت کے منصوص شرائط میں اس حدتک توجیہ و تفسیر کی کہ عملی طورپر شرط عدالت کی شرط کا انکار کردیا جائے یا فاسق و فاجر کی اقتدا فقط کراہت کی حدتک پہنچ جائے۔(۲۷)
البتہ شیعوںکو ایسی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ امویوں کو بالکل غاصب اور ناجائز سمجھتے تھے۔ لہٰذا اس وقت پیش آنے والے واقعات اور حالات کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں کسی مشکل سے روبرو نہیں ہوئے اور بالتبع کسی توجیہ و تفسیر کو قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں تھے۔ اس نصوص کے علاوہ ائمہ معصومین (ع) کی جانب سے جو احادیث ان تک پہونچی تھیں، ان میں واضح طورپر امام جمعہ اور جماعت کی شرائط میں سے ایک شرط خود عدالت تھی۔(۲۸) البتہ اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ گذشتہ ادوار میں شیعہ حضرات بالکل نماز جمعہ و جماعت میں شرکت نہیں کرتے تھے ۔ وہ بھی ان نمازوں میں شرکت کرتے تھے اور عمومی طورپر اسے کافی بھی سمجھتے تھے ۔ یہاں تک کہ ایسے حالات میں ایسی نمازوں میں شرکت کرنا نہ صرف یہ کہ قابل قبول بھی بلکہ عظیم ثواب کی حامل تھی۔(۲۹) لیکن ان ثواب و جزا کے اپنے خاص دلائل اور براہین تھے اور اس کا سبب یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ عدالت کی شرط کو امام جمعہ و جماعت کے لئے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ سنیوںکی طرف سے شرط عدالت کو قبول نہ کرنے اور شیعوں کی طرف سے اس شرط کو قبول کرنے میں ان سب سے زیادہ جو پہلے ظاہری طور سے فرق نظر آتا ہے اس سے کہیں گہرا فرق ان کے کلامی و فقہی اور اسی طرح ان کے شرعی و اعتقادی حساسیت کی ساخت میں دخیل ہے۔ اس لئے کہ اس شرط کا قبول نہ کرنا موجودہ صورت کو کسی بھی حال میں قبول کر لینے کے مترادف تھا ۔اگرچہ اس درمیان کچھ دوسرے عوامل بھی موجود رہے ہیں لیکن یہ عامل ان تمام عوامل میں مؤثر ترین اور اہم ترین اور بہت ہی زیادہ فیصلہ کن عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔
اگرچہ اہل سنت کی فقہی ا ور کلامی بنا کچھ اس طرح ہے کہ وہ حاکم کو اولواالامر کے مصادیق میں سے جانتی ہے اور اسے واجب الاطاعت سمجھتی ہے(۳۰) آیا طول تاریخ میں اہل سنت نے تمام حکام کی مشروعیت اور ولایت کو اسی علت کی وجہ سے قبول کیا ہے؟ عوام کی درمیانی فکری اور ثقافتی سطح سے بالاتر مباحث کلامی اور فقہی مسائل کہیں زیادہ پیچیدہ تھے اور ہیں ان مباحث سے آشنائی کے ذریعہ ان لوگوں نے حاکموں کے سامنے سر نہیں جھکائے۔ اصولا ایسے مباحث ان کے دین و فہم میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا ان کا فہم و ادراک اس سے آسان اور محدودتر تھا کہ وہ اسے اپنے اندر جگہ دے سکے۔
شرطِ عدالت کے انکار کی اہمیت
یا ایک دوسری تعبیرکے مطابق تنہا مشکل یہ نہیںہے کہ اہل سنت کی فقہ و کلام کی فطری اور منطقی بنا کی اقتضا صرف یہ نہیں ہے اور اصولی طورپر ہر دین و مذہب کے پابند لوگوں تقاضا کیا ہے؟ زیادہ اہمیت کا حامل مسئلہ یہ ہے کہ اس وسیع مجموعہ میں سے کون سا حصہ ان کے ذہن و فکر اور ایمان و اعتقاد میں پایا جارہا ہے یعنی عوام لوگوں کا اس مجموعہ سے متعلق ا دراک کیا ہے؟ اور اس کی حدیں کیا ہیں؟ اور ان میں مختلف اجزا کا ایک دوسرے سے رابطہ کیسا ہے؟ اس مرحلہ میں جو چیز پایدار اور مؤثر ہے وہ یہی ا دراک و فہم ہے، یہی چیز ہے جو تاریخی میدان اور معاشرہ میں کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ یہ دینی شعور و ادراک ہر زمان و مکان میں موجودہ حالات کے تحت بدلتے رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور سے تبدیلیوں میں،ایک ثابت عوامل پائے جاتے ہیں جو دین کی استوار بنیادوں اور اصول سے متأثر ہوتے ہیں۔
ایک مسلمان کے نزدیک محسوس ترین اور زیادہ سے زیادہ قابل فہم ایمان کا نمونہ نماز رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اس واقعیت کے پیش نظر کہ صدر اسلام میں مسلمان ہمیشہ نماز جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے اور نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے اور یہ نکتہ بھی کہ نماز ہمیشہ خلفا، حاکموں اور ان کے نمایندوںکی امامت میں ہوا کرتی تھی اور لوگوں کی نظر میں یہ امامت حاکمیت اور خلیفہ کی مشروعیت کی علامت تھی۔ کیا واقعیت یہ نہیں ہے کہ شرط عدالت کو قبول نہ کرنا، موجودہ صورت اور اس کی مشروعیت کو قبول کرنے میں ہر عامل سے زیادہ مؤثر رہی ہے۔
یہ نکتہ بالخصوص ابتدائی صدیوںکے لئے زیادہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ اس دور میں خود مسلمان نماز جمعہ و جماعت میں شریک ہونا اپنا لازمی فریضہ سمجھتے تھے اور خود حکام اس کی بہ نسبت نہایت حساس تھے اور حتی لوگ معاشرہ کے تمامی لوگوں کے ساتھ زور و شور سے نماز جمعہ اور دوسری جماعتوں میں شرکت کرتے تھیاور ان دو نمازوں مخصوصا نماز جمعہ کی امامت، حکام کے سپرد تھی۔ لیکن زمانے کے ھذرنے کے ساتھ ساتھ یہ حساسیت بعض وجودہات کی بنیاد پر شدت سے کم ہوتی گئی اور وہ نمازیں حکام کے علاوہ دوسروں کے ذریعہ ادا ہونے لگی، البتہ عموماً بلکہ مکمل طور سے جو بلا واسطہ یا بالواسطہ، انھیں کی طرف سے منصوب ہوتے تھے، قائم کی جارہی تھی ۔(۳۱) لیکن بہر صورت اس واقعہ سے پیدا ہونے والے اثرات، خاص طور سے اس کمی کے وجود میں آنے سے پہلے ہی، مسلمانوں کی ، فقہی اور کلامی بنیاد اور ان کی دینی اور نفسیاتی بناوٹ کو متأثر کر دیا۔
یہاں اہم مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حاکم کی امامت کو قبول کرلینے سے، اس کی حاکمیت کو قبول کرلیا جاتا تھا۔ بلکہ یہاں پر زیادہ اہمیت کی حامل یہ فکر تھی کہ جس کی بنیاد پر، ظالم و جابر اور فاسق و فاجر کی امامت کو جائز قرار دے رہی تھی جو زندگی کے مختلف امور میں سرایت کر گئی اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے حاکموں کی اقتدا میں نماز ادا کرنا نہ تنہا صحیح تھی بلکہ ان کو صدقات اور زکات اور ان کے ہمراہ جہاد اور حج بھی درست ہے۔ اس حدتک کہ ابن حنبل جیسا زاہد اور محتاطانسان یہ کہنے پر مجبور ہوگیا:'' جہاد حاکموں کے ساتھ تا روز قیامت خواہ وہ عادل ہوں یا فاسق صحیح ہے اور اسی طرح سے غنائم کی تقسیم اور حدود الٰہی کو جاری کرنا بھی ان کی طرف سے صحیح ہے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انھیں طعنہ دے اور ان (حکام) مقابلہ میں کھڑا ہوجائے۔ انھیں صدقات دینا جائز اور نافذ ہے لہٰذا جو شخص انھیں صدقے دے خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، وہ بری الذمہ ہوجائے گا۔ ان کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے اور جو ان کی اقتدا میں پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کرے تو وہ سلف صالح اور پیغمبر اکرمصلىاللهعليهوآلهوسلم کی سیرت کا تارک اور بدعت گذار ہوگا۔ اگر کوئی امیروں کی اقتدا میں نماز پڑھنے اور اس کی صحت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو خواہ وہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں مجزی ہے گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے نماز جمعہ کی فضیلت کو بالکل درک نہیں کیا ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ ان کی اقتدا میں دو رکعت نماز بجا لائی جائے اور اس پر ایمان رکھے کہ یہ نماز تام و تمام ہوگی اور اس سلسلہ میں معمولی سا بھی روا نہیں ہے۔(۳۲)
اب اس نکتہ کی بررسی کرنا ہے کہ یہ فکر کیا تھی اور کہاں سے پیدا ہوئی۔ اس فکر کی جڑ کہاں سے ہے: جس کے سہارے مذکورہ امور پر صحت کی مہر لگائی جاتی تھی، اس نکتہ میں پوشیدہ ہے کہ بعض امور جیسے نماز، جہاد اور زکواة جو خود مطلوب ہیں اور انھیں انجام دینے کے لئے شارع نے حکم دیا ہے۔ اس مقام پر ان کا بجالانا اہم ہے نہ یہ کہ انھیں کیسے انجام دیا جائے۔ اہم تو یہ ہے کہ مکلف ان امور کو انھیں ضوابط کے مطابق انجام دے جنھیں شارع نے مقرر کیا ہے۔ لیکن یہ اعمال کس کی ہمراہی میں انجام پذیر ہوں، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔
اہم تو یہ ہے کہ نماز جمعہ و جماعت قائم ہو اور مسلمان لوگ اس میں شرکت کریں، اہم یہ نہیں ہے کہ اس کی امامت کون کر رہاہے۔ اہم تو یہ ہے کہ جہاد کا فریضہ ترک نہ ہو۔ لیکن یہ جہاد کس شخص کی سپہ سالاری میں کیا جائے یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے اہم تو یہ ہے کہ صدقات و زکوة ایک شرعی فریضہ ہونے کی وجہ سے ادا کیا جائے ،لیکن یہ کہ اسے کس کے حوالہ کیا جائے اور کہاں مصرف کیا جائے یہ مورد توجہ نہیں ہے۔ رقوم شرعیہ کے لینے والے خواہ عادل ہوں یا عادل نہ ہوں، بلکہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں انہیں ادا کیا جائے!۔
اسی نکتہ کو حسن بصری اس مقام پر بیان کرتے ہیں، جہاں کوئی شخص کسی منافق کی امامت میں نماز پڑھ لے، اس طرح وضاحت کرتے ہیں: ''کسی مومن شخص کے کسی منافق کی امامت میں نماز پڑھنے سے اس کی نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور مومن کی اقتدا میں کسی منافق کا نماز ادا کرنا اسے کوئی فائدہ نہیں پہونچائے گا۔(۳۳) لیکن اس سے کہیں زیادہ صریح انداز میں عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں: ''نماز ایک حسنہ ہے۔ لہٰذا میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری نماز میں کون شریک ہو۔(۳۴)
اس سلسلہ میں ابن حزم فرماتے ہیں:'' میں اصحاب رسول میں کسی صحابی کو نہیں پہچانتا کہ جو اپنی نماز کو مختار، عبیدا للہ ابن زیاد، حجاج اور نہ اس سے زیادہ کسی فاسق کی امامت میں پڑھنے سے انکار کیا ہو''۔ خدا وند عالم فرماتا ہے:'' نیکیوں اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور معصیت اور دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو''۔ اوریہ مسلم ہے کہ مساجد میں نماز اور اس کے اقامہ سے بہتر کوئی خوبی نہیں ہے، پس جو بھی اس کی نیکی کی طرف دعوت دے تو اس نیک امر میں اس کی اجابت کرنا واجب ہے۔ نماز کو ترک کرنے اور مساجد کو بند کردینے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پس ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم اس میں کسی کی مدد کریں اور یہی حکم روزہ، جہاد اور حج کا ہے۔ پس اگر کوئی ان کی طرف ہمیں دعوت دے تو ہم اس نیک امر میں اس کے ساتھ ہوں گے اور اجر کوئی ہمیں برائیوں کی طرف دعوت دے تو اس کی اجابت نہ کرتے ہوئے اس کی مدد نہ کریں گے۔ یہ نظریہ ابوحنیفہ، شافعی اور ابو سلیمان کا ہے۔(۳۵)
اور ابن قدامہ جو حنبلی فقہ کے بزرگ فقہا میں سے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں:'' ایک مسلمان شخص پر واجب ہے کہ وہ نماز جمعہ اور عیدین میں شریک ہو اگرچہ ان نمازوں کا امام فاسق و فاجر اور بدعت گذار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ یہ ا سلام کے ظاہری شعائر میں سے ہیں کہ جسے اولیائے مسلمین قائم کئے ہوئے ہیں۔ پس ان کی امامت میں ان نمازوں کانہ پڑھنا ان کی تعطیل اور ختم کردینے کا پیش خیمہ ہے۔(۳۶)
عمل اور اس کے شرائط
مذکورہ بالا نظریات میں جو نکتہ اہمیت کا حامل ہے وہ خود عمل ہے اور ان کے شرائط کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ حالانکہ کسی بھی عمل کا شرائط اس عمل کے جزء ہوتے ہیں لہٰذا ان کا خود عمل سے جدا ہونا نا ممکن ہے۔ ان کی نظر میں نماز جماعت و جمعہ تنہا ایک عبادی عمل کی حیثیت رکھتا ہے لہٰذا ان کا عمل خیر اور مطلوب ہونا( ان کے شرائط سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ کسی بھی شخص کی امامت میں انجام پائے ) اس کی سفارش اور اس پر زور دیا گیا ہے اور اسے مجزی اور تام بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ بات اپنی جگہ پر درست ہو، یہ ان عبادتوں میں ہے کہ جہاں یہ عمل انفرادی حیثیت رکھتا ہے لیکن نماز جماعت و جمعہ یا جہاد میں ،یہ کہنا درست نہیں ہو سکتا۔
اگر اس بات کو قبول کرلیا ہے کہ نماز جمعہ و جماعت ، جیسا کہ اخبار و احایث اور سیرہ نبوی سے سمجھ میں آتا ہے ، ''یہ اہم اور حساس ترین اسلامی شعائر میں سے ہے ا ور یہ مسلم اور طے شدہ ہے کہ اخلاص و توحید و اسلام اور اسلامی عبادتیں نمایاں ظاہر اور دکھائی دینے والی ہیں۔ اس لئے کہ ان کے نمایاں ہونے میں اہل شرق و غرب یعنی سبھی لوگوں کے لئے حجت و دلیل ہے۔''(۳۷)
اور عملی طورپر پوری تاریخ میں یہ اہم شعائر میں سے رہے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں جبکہ وہ خود اس قدر اہم ہیں تو ان کی امامت کے سلسلہ میں یہ کہہ کر کہ نماز ایک مطلوب اور قابل توصیف امر ہے اس کے بارے میں سستی برتیں یا انھیں بے اہمیت بتا یا جائے۔ پس یہ بات قابل قبول نہیںہے کہ وہ اسلامی شعائر جس کے ذریعہ اسلام اپنی واقعیت اور معاشرتی صورت نمایاں کرتا ہے، ایک ایسے شخص کے ذمہ ہوں جو کم سے کم دینی ا ور اخلاقی صلاحیت بھی حامل نہ ہو اسلامی شعائر جو خود دین ایک حصہ ہیں اور بلکہ دین کے اہم ترین رکن کی حیثیت رکھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو خود دینی اقدار کی مخالفت کا مظہر ہے کم سے کم اس سے بیگانہ ہے، اس کی امامت کا ذمہ دار بن جائے(۳۸) یہ موضوع اس سے کا بہت واضح ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا بھی مناقشہ کیا جائے ۔
اس سے ہٹ کر صدر اسلام میں کسی بھی امام کی امامت میں نمازوں کی ادائیگی صرف اس معنی میں نہیں تھا خواہ نماز یومیہ ہو یا نماز جمعہ انجام پاجاتی تھی بلکہ یہ اقتدا بھی زیادہ معانی کی حامل تھی اور یہی زیادہ معانی کا حامل ہونا زیادہ لوکوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ اس دور میں لوگوں کی نظر میں یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ فلاں شخص چونکہ جماعت میںحاضر ہو گیا ہے، اس لئے اس نے اپنی نماز ادا کرلی ہے۔ ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا، سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ کسی بھی فرد کا کسی کی امامت میں نماز کا ادا کرنا اس کی امامت کو قبول کرنے اور اس کو قانونی اور آئینی حیثیت دینے کے معنی میں تھا۔ کہ اس نے اس کی امامت اور ولدیت کو نماز میں شریک ہونے کی وجہ سے تائید کردی تھی(۳۹)
جیساکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیاکہ نماز جمعہ وجماعت وحدت کی نشانی اور مسلمانوں کے متفق ہونے نیز اس حاکم کو قانونی طورپر قبول کرنے کے معنی میں تھا۔ ان دو نمازوں میں شرکت کا قہر نتیجہ یہی تھا اور یہ بلا واسطہ حاکم کی حکومت کو قبول کرنے اور اس کی قدرت کے ارکان کو مستحکم کرنے اور اس کی تائید پر تمام ہوتا تھااور یہ مسئلہ نماز میں شرکت کرنے والے کی نیت سے بھی متعلق نہیں تھا کہ وہ کیا ایسا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ بلکہ اس دور کے عرف میں اس کا تنہا شریک ہو جانا اس کی تائید کے معنی و مفہوم میں تھا۔ جب عبد اللہ ابن عمر نے یہ جملہ کہا: نماز جمعہ کی امامت تنہا اس شخص کا حق ہے جو اپنے رقیبوں سے جنگ میں کامیاب ہوجائے ۔(۴۰) یہ جملہ اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ یہ بات تنہا عبداللہ ابن عمر کی نہیں بلکہ اس دور کے عام مسلمانوں کی فکر تھی۔
یہاں ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ یہ طرزفکر کن معیاروں پر قائم ہے اور اس کے مختلف پہلو کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ بلکہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ علما اہل سنت کس طرح سوچتے ہیں اور ایسا کیوں سوچتے؟ مثلا ابن تیمیہ کتاب السیاسہ الشرعیة میں ایک مقام پر رقم طراز ہیں: ''تعاون کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم: خوبیوں میں تعاون اور مدد کرنا مثلا جہاد اور اقامہ حدود سے لیکر حقوق شرعیہ کے لینے اور اسے مستحقوں کو دینا یہ وہ امور ہیں کہ جن کے لئے خدا و رسول نے حکم دیا ہے۔ بہت زیادہ ایسا ہے جو اس بات سے ڈر کر کہ مبادا کہیں ایسانہ ہو کہ وہ ظالموں کے مددگاروں میں اس کا شمار ہوجائے ، مدد سے ہاتھ کھینچ لے ، پس اس نے ایک واجب عینی یا واجب کفائی کو ترک کر دیا ہے ایسا توہم کہ ایک شخص باورع، متقی ا ور پرہیزگار ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوف و سستی اور پرہیزگاری ایک دوسرے سے مشتبہ ہو جاتے۔ ہیں اس لئے کہ دونوں کا مطلب رکنا اور بازآجانا ہے۔ دوسری قسم: گناہ و دشمنی پر مدد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نفس محترم کو قتل کرنے میں مدد کرنا یا مال محترم کو غصب کرنے میں مدد کرنا یا کسی کو مارنے میں مدد کرنا جو مستحق نہ ہو یا اور ایسی ہی دوسری بہت ساریمثالیں۔ یہ تمام وہ امور ہیں جنھیں خداا و ر اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔''(۴۱)
بلاشک و شبہہ ایسی طرزفکر جیساکہ ہم نے نماز جمعہ و جماعت کی بحث میں بیان کیا، دینی پابندیاں ایک طرف تو دوسری طرف صدر اسلام کے ناہنجارحالات کا نتیجہ رہی ہیںاور اس در میان اسے فروغ دینے میں اموی اور ابتدا میں عباسی خلفا نے خوب کردار اداکیا ہے۔ اس کا امکانی راہ حل وہی ہے جسے ان لوگوں نے انتخاب کیا ۔ یعنی ان لوگوں نے بعض مواقع پر عدالت کی شرط حذف کردیا مثلا ان کے لئے یہ ناممکن تھا کہ قرآن کی وہ آیات جو جہاد اور صدقات و زکوة کا حکم دیتی ہیں، ان سے چشم پوشی کرلیں، لہذا اس مقام پر ان لوگوں کے لئے تنہا معیار ان احکام کا بجالانا ہے اور اب یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ کس کی قیادت میں اور کس ہدف کے تحت انجام پائے۔
اتفاق سے یہ مسائل وقت کے حکام کی خاص توجہ کا مرکز بھی تھے۔ وہ جس جنگ کو خود جہاد سمجھتے تھے اس میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو لازم جانتے تھے۔ جس طرح سے اس بات کو بھی پسند کرتے تھے کہ لوگوں کے شرعی حقوق کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لہذا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا کہ وہ ان احکام کو تعطیل کرنے کی فکر میں پڑتے یا اسے کمزور بناتے، یا کم سے کم جو ان کی بلند پروازیوں کے امکان کو ختم کر دیتے۔ اس لئے کہ وہ ایک طرف سے ان احکام کے جاری ہونے سے مادی منافع سے بہرہ مند ہوتے تھے اور دوسری طرف اس کے معنوی منافع بھی حاصل کرلیتے تھے اور اس طرح وہ اپنے آپ کو راہ خدا کے مجاہد اور غازیوں میں شمار بھی کرتے تھے، ان کا یہ عمل ان کی موقعیت کو مستحکم بنانے اور ان کی عوام الناس میں مقیول بنانے میں کافی مدد کررہا تھا۔(۴۲)
ہم نے ابھی تک جن دلائل کو بیان کیا ہے، ان کے باوجود یہ کہنا بجا ہے کہ نماز جمعہ و جماعت میں عدالت کی شرط کو معتبر نہ سمجھنا اور اس طرزفکر کو ایجاد کرنے، اسے محکم اور مضبوط بنانے اور دوسرے مقامات میں پورے طور سے ایک بڑی مدد کی ہے اس لئے کہ ہر علاقہ میں تمام لو گ ہر روز ان دوفریضوں سے سروکار رکھتے رہے ہیں اس کے بر خلاف یہ دونوں سبھی لوگوں کو یہ فریضہ پانچ اوقات میں ہر فرد کے لئے یکسا ں طور پر شامل ہے۔ اور ان باتوں سے ہٹ کر خود نماز، خوا اس کی شرعی حیثیت کا لحاظ کیا جائے اور چاہے لوگوں کے فہم کے اعتبار وں سے ایک خاص مقام کا حامل ہے۔ پس جب شرط عدالت کو ایسے اہم فریضہ سے ساقط کردی جائے گی تو عدالت کی شرط اور اس کے اعتبار کا ختم کر دینا مسلم ہے کہ دوسرے موارد سے بھی عدالت کی شرط ختم ہوجائے گی اور اس طرح دوسرے موارد سے عدالت کی شرط کے حذف ہوجانے سے کسی شخص کی آواز کو اعتراض اور تعجب کے عنوان سے بلند کر دے تو یہ اس کا فطری عمل ہوگا۔ بلکہ اساسی طور پر ایک ایسی جدید اسلامی فکر اپنے اصول و ضوابط کے مطابق مضبودا کردے اورآہستہ آہستہ اس کو وجود میں لائے۔
جس وقت قتادہ نے سعید ابن مسیب جو کہ تابعین کے اکابر زاہدوں میں سے تھا اپنے عقیدہ پر اصرار اور اس پر زور دینے کی وجہ سے کہ( ایک زمانہ میں دو خلیفہ کی بیعت نہیں کی جاسکتی لیکن دوسری طرف عبدالملک اس سے یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے دو بیٹوں ولید اور سلیمان کے لئے ایک ہی وقت میں ان سے بیعت لینا لے لے)۔(۴۳) کئی بار عبدالملک کے حکم سے شدید شکنجوں کا شکار ہوئے، سوال کیا گیا کہ کیا ہم حجاج ابن یوسف کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا: ہم اس سے بھی بدتر کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں۔(۴۴) صحابہ اور تابعین عموماً ایسے ہی تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر حجاج کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے اسی طرح خوارج کے رئیس نجدہ کی امامت میں بھی نماز پڑھتے تھے ۔(۴۵) البتہ یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں شیعہ حضرات اور ان کے سردار اور بزرگان بھی ان نمازوں میں شریک ہوتے تھے۔(۴۶) لیکن جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا کہ ان کا یہ عمل ایک خاص دلیل کی بنا پر تھا نہ یہ کہ وہ حضرات نماز جمعہ و جماعت میں عدالت کی شرط کے معتقد نہ تھے۔
یہ مسئلہ اہم حساس ترین نکات میں سے ہے جس نے اہل تسنن اور اہل تشیع کے فقہی و کلامی ، اس کے اعباع میں معاشرتی بناوٹ، نفسیاتی،سیاسی تبدیلیاں اور ان کی تاریخ کو جدا کردیا ہے۔ اس دور میں اس زمانہ کے حالات سے جدا قانونی حیثیت کا حامل اور اس سے وجود میں آنے والی ضرورہیں اور شیعوں کے افکار اپنے ابتدائی ایام سے ہی مقبول تھے اور اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ اس طرح سے عدالت اپنے فقہی حدود میں کہیں زیادہ واضح اور وسیع پیمانہ پر ان دو گروہوں کے کلامی مفہوم کو ایجاد کرنے میں اپنا پورا پورا کردار ادا کرگئی، نیز اس نکتہ پر توجہ کئے بغیر ان کے تاریخی، سیاسی، معاشرتیاور دینی تغیرات کے سلسلہ میں صحیح تحلیل و نجزیہ اور مختلف قسم کے رفاہ کو آیندہ کے بدلاؤ کے ساتھ وجود میں لانے کے بارے میں تحقیق نہیں کی جاسکتی۔اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اس کے بغیر ان کے آئندہ کی تاریخ میں رشد و نمو سے متعلق ایجاد ہونے والی رکاوٹوں اور تحقیق و بررسی کر سکیں۔
اور اس طرح شیعوں کے فقہی و کلامی نظام نے اہل تسنن کی عدالت کے بر عکس اپنی موقعیت کو محفوظ کررکھا ہے، اگرچہ شیعہ جس عدالت کے قائل تھے اسے معاشرتی نظام کو عملی طور پر تحقق بخشنے میں ناکام رہے ہیں لیکن ہمیشہ اسے عملی کرنے کے رہے ہیں اور کم سے کم اپنی آرزو کے عنوان سے اس کے بارے میں فکر کرتے ر ہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کے درمیان ایسی بات دیکھنے میں نہیں آتی اور اگر کبھی ایسا دیکھا بھی جائے تو وہ بھی ان کے شیعت سے لگاؤ کی بنا پر اور ایسا اتفاک زمانہ کے مختلف حصہ میں دیکھا گیا ہے۔(۴۷)
علی الوردی اسی مطلب کو بخوبی بیان کرتے ہیں: مذہب شیعہ اس دور میں ایک آتش فشاںکی طرح خاموش ہے۔ ایسا آتش فشاں ایک دور میں ابل رہاتھا اور زمانے گذرنے کے ساتھ ساتھ خاموش ہوگیا ہے۔ اس میں اور دوسرے پہاڑوں میں بس یہی فرق ہے کہ اس کے دہانے سے دھواں نکلتا ہے۔ لیکن ایک خاموش آتش فشاں اپنی ظاہری خاموشی کے باوجود خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ اس میں اور دوسرے پہاڑوں میں فرق یہ ہے کہ یہ اپنے اندر پگھلی ہوئی آگ رکھتا ہے جس کے متعلق کسی کو نہیں معلوم کہ اس میں کب انفجار واقع ہو جائے گا۔'' پھراپنے بیان میں اس طرح اضافہ کرتے ہیں: اشنا عشری شیعہ کے عقا ئد کچھ اس طرح سے تھے کہ ان کو تاریخ کے کسی بھی دور میں حکام وقت پر تنقید کرنے اور اُن سے ٹکراؤ اور معارضہ سے باز نہیں آئے ہیں۔ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر حکومت ظالم، جابر، غاصب اور شرعی حیثیت سے خالی ہے مگر یہ کہ اس حکومت کی باگ ڈور ایک عادل شیعہ اور، یا علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے جو معصوم ہو ں وہ اس کی باگڈور کو سنبھال لے۔ اس بنیاد پر شیعہ حضرات ایک دائمی انقلاب کی حیثیت رکھتے تھے جو ایک پل بھی قرار نہیں لیتے تھے اور حکام وقت کا مقابلہ کرنے سے رکتے نہیں تھے اور حاکم کواپنے ائمۂ معصومین(ع) کے ضوابط کی ان کسوٹی پر مقایسہ کرتے تھے جس کے وہ خود معتقد ہوتے تھے، اسی وجہ سے موجودہ حکومت کو غاصب اور ناقص تصور کرتے تھے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ صدر اسلام سے لیکر اب تک،پھلتا پھولتا اور ان کے اور حکام کے درمیان دشمنی میں گہرائی اور اس عقیدہ کی جڑیں پختہ ہوتی گئیں یہی وجہ تھی کہ انھیں زندیق، رافضیاور ملحد ہونے کی تہمت لگائی گئی۔ ضمنی طور پر ''رفض'' کی صفت دین اور حکومت دونوں ہی معنی میں خارج ہوجانا تھا ۔ جس شدت کے ساتھ انہیں ان مشکلات اور ذہنی دباؤ کا سامنا ان حکام کی طرف سے کرنا پڑ رہا تھا اسکی وجہ سے وہ لوگ( شیعہ)ترجیح دیتے تھے کہ انہیں شیعہ اور رافضی کے بدلے ملحد اور کافر کہاجائے، معاویہ اور اس کے اموی خلف اور ان کے بعد عباسیوں نے انھیں خاموش کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی اور انواع و اقسام کے شکنجوں کا سہارا لیا تاکہ ان کو جڑ سے ختم کر دیں، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ شیعہ ایسے تمام اقدامات کا ڈت کر مقابلہ کرتے رہے اور مستقبل میں بھی ستمگروں اور ان لوگوں سے مقابلہ اور نبردآزمائی کرتے رہیں گے جو انسانی کرامت اور ان کے حقوق سے کھلواڑ کررہے ہیں۔(۴۸) البتہ ان کی یہ روش اپنے خاص نتائج کی حامل بھی ہے کہ ان میں سب سے اہمیت کا حامل اس کا متضاد ہوناہے ہر وہ چیز جو پائیداری، ثبات قدمی اور تاریخی استمرار سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
شیعوں کے نزدیک عدالت کو ایک اصل کے عنوان سے قبول کر لینے سے ایک دینی رنگ اور ایک خاص دینی فہم و ادراک اس کے ہمراہ آگئی۔ خود شیعوں کا جوش میں آجانا، تحریک کو قبول کرنا، فداکاری اور ان کی آرزوئیں اسی ایک نکتہ کو قبول کر لینے کا نتیجہ ہیں۔ البتہ دوسرے عوامل بھی ایسے خصائص کو وجود لانے میں مددگار رہے ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ اہم واقعۂ عاشورا ہے لیکن مسئلہ تو یہاں ہے کہ یہ واقعہ خود شیعوں کے نزدیک ایک آزادی طلبی، عدالت خواہی اور مردانگی ساتھ زندگی بسر کرنا ایک اعلیٰ نمونہ ہے لہٰذا یہ واقعہ اس کی تائید اورانھیں اوصاف کے استحکام اوروہی عدالت کاآرمانی مفہوم ہے۔
یہ سارے عوامل باعث ہوئے کہ شیعت کی پوری تاریخ میں عدالت کی سب سے زیادہابھارنے اور اکسانے والی آرزو، ایک اہم مقصد اور تمنا کی صورت میں باقی ہے۔ اور یہ اسی طرح تاابد باقی رہے گی۔ یہ شیعی افکار پر اعتقاد کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ جب تک یہ مذہب اور مکتب فکر باقی رہے گا اور اپنے پیروکاروں کو ایمان اورقوت بخشتا رہے گا اور ذہنی و نفسیاتی بناوٹ اور دینی فہم و ادراک کو متاثرہے، ایسی خصوصیت کی ضرور حامل ہوگی۔ اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ بعض اسباب و عوامل کے تحت وہ کم مدت یا طولانی مدت تک کے لئے بے حرکت ہوجائے لیکن کبھی بھی پوری طرح نابود نہیں ہوسکتی۔
اہل سنت کا عدالت کو ایک اصل کے عنوان سے قبول نہ کرنے نے ان کے اندر دینی رجحان کو اور اسی طرح ایک دوسرے میںدرک وفہم ایجاد کردیا۔ یہ دونوں ان کے نزدیک ایک ایسے مرکز میں پروان چڑھے ہیںکہ عوام الناس کے نفع میں تمام ہوئی ہے۔ یعنی قدرت، امنیت اور موجودہ صورت حال کو قبول کرنا ہے۔ ان میں کون سا عامل باعث ہوا ہے کہ متعدد روایات اور نصوص میں نماز جمعہ وجماعت کے متعلق شرطِ عدالت کی صراحت کے باوجود ان نمازوں کے امام کے تقوی، دینداری اور عدالت کو واجب قرار دیتی ہیں۔(۴۹) (اور وہ نصوص جن کا ان کے نزدیک کامل اعتبار ہے۔) ان تمام عوامل کے باوجود اسے کوئی اہمیت کیوں نہیں دی گئی یا کم از کم کم اہمیت بنانے میں مشغول رہے ہیں۔ کیا اسے قبول کر لینے کی صورت میں پیش آنے والے اعتراضات اور اس کے نتائج کی وحشت(عدالت کو قبول نہ کرنے کا) باعث ہوئی؟ ہاں! دینی رجحانات اور قدرت و امنیت کے مفہوم کے تحت دین کا شعور و ادراک پیدا ہوا جو عدالت کا رقیب بن کر سامنے آیا اور اس کو پیچھے ڈال دیا تھا،اس کے سبب یہ وجود میں آیا۔
اس ماجرا کے بھی کچھ خاص نتائج ہیں جن میں اہم ترین اس دینی فکر کے تصور کا ان عوامل سے موافق ہونا ہے جس کے ذریعہ ہم نے ثبات، استقرار اور تاریخی استمرار سے تعبیر کیا ہے۔ جب کہ اس کی موجودہ صورت حال اپنی کم سے کم مشروعیت کی حامل تھی جو اسے نامشروع قرار دے اور عین اس عالم میں کہ کوئی اس سے زیادہ وسیع اور جائز آرزوئیں موجود نہ تھیں نیز اس کے حصول کے لئے لوگوں کو غور و خوض اور تحریک کی دعوت نہ دے، دینی تفکرات اور لوگوںکے دینی رجحانات اور ان کی سوجھ بوجھ بھی ایسی نہیں تھی جو ایسی دعوتوں پر لبیک کہے، ایسی صورت میں فطری طور پر ایسے ہی ثبات اور استقرار کا حاصل ہونا مسلم ہے۔
البتہ ہر گز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تشیع اور تسنن کی نگاہ سے تاریخ لازمی طور ایسی رہی ہے یا آئندہ بھی ایسی ہی برقرار رہے گی۔ دوسرے عوامل بھی رہے ہیں جس میں ہر ایک نے اپنے اعتبارسے کردار ادا کیا ہے۔ ان دونوں مذہبوں کی تاریخ نے ان عوامل کی تاثیر اور تأثرات کو اکٹھا کرلیا ہے۔ جو کچھ اوپر کہا جاچکا ہے وہ اہم ترین اور فیصلہ کن عوامل میں شمار ہوتے ہیں اور بعد میں اہمیت کے حامل رہیں گے۔ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس کو اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ فکر ان دو گروہ کے دینی افکار اور ان کی روح، ان کے باطن اور ضمیر میں سے مخلوط ہوگئے ہیںایسی جڑ جو کہ ان دونوں فرقوں کے افکار و عقائدسے پیدا ہوئی ہے۔لہٰذا جب تک ان افکار کے حامی زندہ رہیں گے، اس وقت تک ایسے واقعات اور حوادث باقی رہیں گے۔
حکومت کی ذمہ داریاں
لیکن دوسرا عامل ،گذشتہ ادوار میں حکومت اور قدرت کا مفہوم رہا ہے۔ اس دور سے مکمل جدا اور اس کے برخلاف ہے جس میں حکومت تنہا ایک خاد م کی حیثیت رکھتی ہے۔لیکن گذشتہ ادوار مین حکومت کا پہلا قدم امنیت برقرار کرناتھا۔ لیکن اس دور میں حکومت سے خدمت طلب کی جاتی ہے اور قدیم ایام میں اس سے داخلی اورخارجی امنیت کی ضمانت مانگی جاتی تھی، لوگوں کی یہ توقع گذشتہ لوگوںکی حکومت سے متعلق افکار کا نتیجہ تھی اور یہ بھی اس دور کے حالات سے متأ ثر ہونے کا نتیجہ تھی۔ ان لوگوں کی نظر میں حکومت ایک ایسامجموعہ تھی جو لوگوں کے مال، جان اور ان کی ناموس کی محافظ تھی اور اس کی پہلی ذمہ داری ان امور کو بنانا سنوارنا اور ان کو انجام دینا تھا نہ یہ کہ خدمات کا پیش کرنا مثلاً حفظان صحت اور علاج و معالجہ، ثقافت، ماحول کی درستگی، تعلیم، سالم تفریحکی فراہمی اور دوسری بہت ساری خدمات کی فراہمی تھی۔نئے زمانہ میں تبدیلیوں نے حکومت اور اس کی ذمہ داریوں کے مفہوم میں تغیر ایجاد کردیا اور امنیت کو برقرار کرنے کو انھیں فرائض کی انجام دہی میں سے ایک جزو مان لیا گیا وہ بھی نہ یہ کہ سب سے زیادہ اہمیت کے عنوان سے مانا۔
لیکن گذشتہ ایام میں مخصوصا مشرقی اسلامی دنیا میں جہاں پر سیاسی ثبات اور استمرار کی بالکل خبر نہیں تھی اور ایسی صورتحال نہیںتھی، اس لئے کہ اس دور میں تمام چیزیں اور سارے مقدسات امنیت میں خلاصہ ہو جاتے تھے اور حائز اہمیت اور مطلوب یہ تھا کہ حکومت میں اتنی صلاحیت ہونی چاہئے کہ وہ سماج میں امنیت کا تحفہ لا سکے ۔ حکومت کے لئے امنیت کو برقرار کرنا اپنے شہریوں کے لئے ایک بہت بڑی نعمت تھی جو ان کے لئے مہیا کر سکتی تھی، اگر مسئلہ کو آج کے جدید زاویۂ نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ بلکہ گذشتہ زمانہ کے حالات پر توجہ رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس موضوع کی اہمیت کے تحت اہل سنت کے بزرگ متکلمین اور فقہا کے اندیشہ اورپریشانیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہر چیز کی بازگشت اسی امنیت کی طرف ہوتی ہے خواہ وہ حفظ شعائر کا مسئلہ ہو یا حدود اور احکام الہی کے اجراء کا مسئلہ یا لوگوںکی جان و ناموس و مال کا مسئلہ ہو۔ ان کی نظر میں حکومت جہاں حافظ دین تھی وہیں لوگوںکی جانوں کی حفاظت کرنے والی بھی تھی لہذا حکومت ان کی دنیوی و اخروی مصلحتوںکو پورا کرتی تھی۔
عموماًاہل سنت کے بزرگوں نے امامت و خلافت کے متعلق جو کتابیں تحریر کی ہیں یااسی مناسبت سے اس موضوع کے تحت خامہ فرسائی کی ہے۔ انھوں نے حکومت کی سب پہلی اور اہم ترین ذمہ داری حفظ امنیت کو قرار دیا ہے؛ یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں نے تو ایسی ذمہ داریوں کو تعریف و تشریح کے عنوان سے انتخاب کیا ہے، خواہ وہ ایک محتاط فرد، صوفی خیال جیسے غزالی سے لیکر،(۵۰) ابن تیمیہ کے ایسے سرسخت اور متعصب انسان تک ،(۵۱) ماوردی کے ایسا سیاست باز سیاسی دانشور سے لیکر،(۵۲) ابن خلدون کے ایسے روشن فکر اور متفکر فیلسوف تک۔(۵۳) یہ لوگ جس دور میں زندگی گذار رہے تھے ایسی حساسیت کو محسوس کررہے تھے البتہ ان کا ایسا نظریہ ایک فطری مسئلہ تھا۔
شاید آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ پھر شیعوں کے یہاں ایسا کیوں پیش نہیںآیا ؟ یعنی شیعی بزرگ فقہا اور متکلمین نے موضوع امنیت اور اس کی حفاظت کے بابت اس حد تک اپنی حساسیت کو آشکار کیوں نہیں کیا؟ جب کہ وہ لوگ بھی قدیم زمانہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اور وہ بھی ہونے والے بدلاؤ اور حوادث کا نزدیک سے مشاہدہ کر رہے تھے؟ تو اس کے جواب میںیہ کہا جاسکتا ہے اولاً امنیت، حفظ ناموس، جان، مال اور ناحق خون کے بہانے کے متعلق شیعوں کا اندیشہ اہل سنت کے علما سے کم نہیں تھا لیکن ایسی حساسیت کے باوجود پھر بھی عدالت کے مفہوم کو فراموشی کے حوالہ کیوں نہیں کر دیا اور ان کے افکار اور اعتقادات میں یہ اصل امنیت کے تحت الشعاع کیوں نہیں قرارپائی۔ ہاں! یہ سب کچھ ائمہ علیہم السلام کی سیرت اور ان نصوص کے سبب تھا۔ جو ان کے نزدیک قابل قبول تھیں۔ یعنی اس موضوع کے لئے ان کے پاس ا یک خاص دلیل تھی کہ اگر ان کے پاس بھی یہ دلیل نہ ہوتی تو وہ بھی اہل سنت کے بزرگوں کی طرح گذشتہ حالات سے متاثر ہو کر حفظ امنیت کے مصالح اور معاشرہ میں سکون و آرام کی خاطر ویسا ہی سوچتے جیسا کہ اہل سنت کے بزرگ علما سوچا کرتے تھے۔
آخر کار تیسرا عامل، جو تاریخی حقائق اور اس کی ضرورتوں سے وجود میں آیا ہے۔ زمانہ کے کچھ حصوں کے علاوہ اسلام کی پوری تاریخ میں عملی طور سے قدرت اکثر اہل سنت کے ہاتھوں میں رہی ہے، سماج اور اس کی سرحدوں کی حفاظت اور امنیت انھیں لوگوں کے ذمہ رہی ہے۔ اس دور میں شیعہ سماج ایک مختصر سماج تھا اور یہ اقلیت میں تھے، بہت کم ایسا ہوا کہ ایسی ذمہ داریوں کو شیعوں نے سنبھالا ہو۔ البتہ یہاں پر شیعوں سے مراد اثنا عشری ہیں۔ اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ فطری تھا کہ اہلسنت کی سیاسی فکر اہل تشیع کے سیاسی نظریہ سے کہیں زیادہ وسیع اور عمیق ہے خارجی و داخلی امنیت کو برقرار رکھنے اور سماج اور معاشرہ میں امن و امان قائم کرنے، اس کے مقدمات اور لوازمات کے سلسلہ میں زیادہ متاثر ہوں۔ جب ان کی فقہ اور کلام پھلا پھولا اور اسے بالیدگی حاصل ہوگئی اور اس میں وسعت پیدا ہوئی کہ وہ لوگ صدیوں کی ملک داری کے تجربہ کے حامل اور خارجی سرحدوں کے محافظ اور وارث تھے اور انھیں اس کی سرحدوں میں امنیت قائم کرنے میں کافی مہارت حاصل ہوچکی تھی۔ لیکن شیعوں کی فقہ اور کلام نے اپنی وسعت کے دور میں ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ تو اکثر عملی حقائق کے بدلہ نظری اصول اور معیار پر تکیہ کرتے تھے۔
خاص طور سے یہ کہ اسلام اپنی پوری تاریخ میں، ہمیشہ داخلی اور خارجی کینہ توز اور سرسخت مخالفین سے برسر پیکار رہا ہے۔ وہ بھی ایسی مڈبھیڑ جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ختم ہوگی۔ بنیادی طور پر دار الاسلام کی جغرافیائی موقعیت کچھ ایسی تھی کہ وہ اپنی وسعت و ظہور کے ابتدائی ایام سے ہی دشمنوں کی جانب سے غیر محفوظ اور لگاتار بے امان حملوں کا شکار رہا ہے۔ ان سب میں ایک زیادہ اہم خطرہ مشرق کی جانب سے تھا کہ وہاں پر زرد پوست قومیں جو ایشائے وسطیٰ میں ابتدا ہی سے اسلام کے مشرقی حصہ کے لئے خطرہ بنی ہوئی تھیں ایسی دھمکی جو مغلوں کے حملوں کے مدتوں بعد تک باقی رہی۔ دوسرا خطرہ مغرب کی جانب سے تھا جس میں عیسائی اور صلیبی لوگ پیش قدم تھے جن کا موجودہ صدی کی ابتدا تک فوجی عنوان سے خطرہ لاحق رہا اور ابھی بھی اپنے دوسرے بھیس میں باقی ہے۔(۵۴)
دارالاسلام کی وسعت
اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ دارالاسلام کی حکومت میں وسعت جو مختلف اقوام، ملتوں، ادیان و مذاہب نسل و خاندان اور تہذیبوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی، یہ بذات خود ایک دوسری پریشانی تھی۔ کوئی بھی دین (اسلام کی طرح) اپنے اندر اس سے زیادہ رنگارنگی نہیں پائی جاتی ہے البتہ ایسی ہماہنگی یکجہتی اتحاد و اتفاق کو بھی برقرار نہیں کرسکا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات اہم ہے وہ اس اختلاف اور رنگارنگی ردعمل سے خالی نہیں تھی۔ یہ بھی خود اسلام کے مختلف درک و فہم کے لئے مناسب موقع ہے۔ نتیجہ کے طورپر بے پناہ فرقہ واریت اور دینی ثقافتی تناؤ اور سیاسی ومعاشرتی بے چینی کو جنم دیگا۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دین اپنیابتدا سے ہی، ایک طرف اپنے بیرونی حملہ آوروں سے روبرو تھا اور دوسری طرف سے درونی سرکشوں سے مقابلہ تھااوراسلامی حکومت کی وسعت اور اس کا آزادی نے اس کو آسان بنا دیا تھا کہ جو بھی چاہے اس کا گرویدہ ہو جائے نیز اس میں عظیم قابلیت پائی جاتی تھی جس میں نتیجةً مختلف تفسیریں اورتوجیہات وغیرہ کا تلاشنا ایک فطری امر تھا۔ ان دونوں میںسے ہر ایک بڑی ہی آسانی سے درونی مختلف الفکر لوگ جو مقابلہ آرائی حتیٰ قتل و غارت اور ایک دوسرے کے قتل عام پر کمر بستہ ہو جاتے جس سے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں او ر بے چینی اور ناامنی ایجاد کریں اور یا کم سے کم اس کو ہوا دیں۔
اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم ابن ابی الحدید کے کچھ نظریات کا تذکرہ کریں، عراقیوں کی فرقہ واریت کے اسباب کو ابوہرزہ کی زبانی نقل کیا ہے جو خود مسلمانوں کی پوری تاریخ میں ان کی فرقہ واریت کا خود ایک نمونہ ہے اور اس کی پیدائش کے علل اسباب کو نقل کریں:'' سرزمین عراق تمام اسلامی فرقوں کا مرکز رہی ہے اس لئے کہ یہ سر زمین پرانی تہذیب و تمدن کا سنگم تھی ، اس لئے کہ جہاں ایرانیوں اور کلدانیوں کے علوم پائے جاتے تھے۔ وہیں ان ملتوں کے باقی ماندہ ثقافتوں اور تمدنوں جس میں یونانی فلسفہ اور ہندیوں کے افکار کا خمیر تھا پایا جاتا تھا اوریہ افکار اسلامی طرز تفکر میںمخلوط ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ مختلف اسلامی فرقوں کے وجود میں آنے اور ان کے پھلنے پھولنے اور پروان کی سرزمین تھی۔ ابن ابی الحدید کہ عراق میں مختلف فرقوںکے اسباب کہ وہ کیسے وجود میں آئے اس کی وضاحت کرتے ہیں : میرے لئے عراقیوں اور آنحضرت کے دوران کے عربوں میں جو فرق ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ یہ سب عراق اور اس میں کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ عراق کی طبیعت اور ان کی طینت کچھ اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب مذاہب پر عقیدہ رکھنے والوں اور نئے نئے ادیان کے ماننے والوں کو پروان چڑھایا اوراور انہیں سماج کے حوالہ کیا ہے ، اس زمین کے باشندے اہل بصیرت اور صاحبان غور و خوض اور مطالب میں دقت کرنے والے ہیں اور نظریات اور عقائد میںمذاہب پراعتراض کرنے والے ہیں۔ مانی، دیصان، مزدک وغیرہ اسی سرزمین کے رہنے والے تھے جو ساسانی بادشاہوں کے دور حکومت میں میدان میںآئے۔ نہ تو حجاز والوں کی طینت و طبیعت ایسی ہے اور نہ ہی ان کے ذہن و فکر ایسے ہیں۔(۵۵)
ابن ابی الحدید کا نظریہ نہ صرف عراق کے بارے میں بلکہ بہت سے دوسرے علاقوں کے سلسلہ میں بھی صحیح تھا۔ وہی دلائل جن کی وجہ سے عراق میں مختلف فرقے وجود میں آئے یاکم سے کم اس کے پھلنے پھولنے اور پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوئے بعینہ وہی دلائل دوسرے اسلامی ممالک میں بھی موجود تھے۔ اسلام کی تقدیر کچھ اس طرح لکھ دی گئی تھی کہ اسلام دوسرے مقامات پر پھیلے پرورش پائے جو دیرینہ تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہے ہیں۔
ایسے حالات میں یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس سے امنیت اور قدرت کے سوا کوئی اور خواب نہ دیکھے، اسلام اپنی پوری تاریخ میں ہمیشہ ایسی مشکلات سے دوچار رہا ہے، اس سے خارجی خطروں سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ جس کا ایک نمونہ شرق اسلام میں مغولوں کے حملے ہیں کہ جس کی وجہ سے حد درجہ تباہی و بربادی ظہور میں آئی اسی طرح اپنی تاریخ میں غرب کی جانب سے کینہ توزی اور دائمی دشمنی اور عیسائیت کے ساتھ محاذ آرائی رہی ہے اور اگر کسی دور میں یہ جنگیں بظاہر خاموش نظر آئیں تو صرف تجدید قوت کی خاطر تھیں نہ یہ کہ یہ لڑائی ہمیشہ کے لئے تمام ہوگئی ہے۔ عیسائیت اور کلیسا کی تشکیل قرون وسطیٰ میں اسلام کو ایک غاصب دشمن کی حیثیت سے سمجھتی تھی وہ بھی ایسا غاصب کہ جس نے اس کی بعض سرزمینوں پر قبضہ کرلیا ہو اور اس کی اصالت و حقانیت کے خلاف قیام کیا ہو۔ اگرچہ اسلام اپنی تعلیمات کی بنیاد پر انھیں اہل کتاب فرض کرتا ہے لیکن عیسائیت دور حاضر سے پہلے مسلمانوں کو ایک کافر سمجھتے تھے اور اسکی نابودی کے علاوہ کچھ اور سوچ نہیں سکتے تھے۔(۵۶) لیکن اس دور میں اسلام کو ایک دین کے عنوان سے قبول کرنے کے بجائے اس کے نابود کرنے کے درپئے تھے۔
عیسائی طاقتوں کی دھمکی
مثلا حائری ساندرس کی زبانی عیسائیوں کا مسلمانوں کی نسبت عقیدہ کے سلسلہ میں لکھتا ہے:'' بہت کم سچے عیسائی ملیں گے جو عصر اعتقاد میں کسی سے گفتگو کے دوران آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کے مقابلہ میں پر سکون رہ جائیں کہ اس کی نظر میں آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کا مذہب ایک کفرآمیز مذہب تھا اور اس کے چاہنے والوں نے۔ مثلا قرن اول سے قرن ہفتم تک سوریہ کو حکومت بیزانس سے جدا کرلیا تھا۔ عیسائیت کا نام و نشان خود اس کے مرکز پیدائش سے مٹادیا تھا۔''(۵۷) اور پھر وہ خود اس طرح اقرار کرتا ہے:'' اس طرح سے عالم عیسائیت یعنی یورپ اسلام سیکھتا تھا اور یہی سبب تھا جس کی وجہ سے اسلام اور اس کے ماننے والوں کا سرسخت دشمن رہا اور برا بھلا کہتا رہا یہاں تک کہ پائک ( Pike ) آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کے سلسلہ میں جو اس نے کتاب لکھی ہے اس میں اقرار کرتاہے: کہ محمد ایک عظیم الشان انسان ہیں جو دوسرے معروف انسانوں کے مقابلہ میں ہر ایک سے زیادہ تہمت و افتراء کا نشانہ بنے۔''(۵۸)
جیسا کہ ہم نے بیان کیاکہ تاریخ کے کسی بھی دور میں عیسائیوں کی دشمنی اسلام کی بہ نسبت ختم نہیں ہوئی ۔ بلکہ وہ ہمیشہ اسلام کے طاقتور،اعتقادی، دائمی اور منظم دشمن رہے ہیں۔ اسلامی سرزمینوں پر ان کے حملے شرقی حملہ آوروں کے بالکل برخلاف جو کہ اکثر بت پرست تھے اس طرح سے کہ خود جوش طور پر اور زرخیز زمینوں، چراگاہوں اور قتل و غارتگری اور آباد علاقوں اور آبادی پر اس عنوان سے حملہ کرتے تھے اور چونکہ ان کا کوئی مذہب نہ ہوتا تھا لہٰذا مرور زمان کے ساتھ مسلمان ہوکر اسلامی معاشرہ میں گھل مل جاتے تھے۔ (عیسائیت کا مشن ) ایک ایسا سوچا سمجھا، معین، خاص ہدف اور مخصوص طرز فکر کی بنیاد پر تھا، وہ صرف اسلام کو ناپسند ہی نہیں کرتے تھے بلکہ مسلمانوںکو عیسائی کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ شرقی حملہ آوروں کا ہدف قتل و غارتگری اورمکمل نابودی تھا لیکن غربی حملہ آور اس کے علاوہ اسلام کی نابودی اور دارالاسلام کو تباہ و برباد کرنے پر کمربستہ تھے۔
مرکز کیتھولک یعنی روم اور یورپی حکومتیں غرناطہ کی حکومت کا ختم ہوجانا، Ferdinand,) lsabella ( کی متحدہ فوج کے مقابلہ میں غرناطہ کے نصیریوں کے خاندان سلسلہ کا آخری حاکم ابو عبداللہ کا شکست کھا جاناصرف ایک شکست نہیں تھی، بلکہ ایک ناقابل فراموش کامیابی تھی جو عیسائیت کو عالم اسلام کے مقابلہ میں حاصل ہوئی تھی اور ساندرس کے قول کے مطابق غرناطہ کا حادثہ ایک ناتمام انتقام اور عالم عیسائیت کا اسلام سے ایک معمولی اور ہلکاسا بدلہ تھا جو ان سے لیا تھا۔ یورپ جو ہمیشہ اسلام کی مادی و معنوی ترقیوں کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ اور یہ اس کی پریشانی مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ فتح ہوجانے کے بعد کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی غرناطہ حکومت کا ساقط ہوجانا اس جہت سے ان کے لئے اور بھی عظیم تھا مسلمانوں کی شکست کا جشن منایا گیا جبکہ ''بارتولد'' کے نوشتہ کے مطابق غرناطہ کا ساقط ہوجانا اسلام میں ایک دھماکے کا کام کرگیا اور مسلمانوں کو سیاہ پوش بنا دیا، کیتھولک کلیساؤں کے سربراہوں نے اس مناسبت سے خود رم اور واتیکان میں جشن و سرور کی محفلیں برپا کیں۔
ایک فرانسوی مؤرخ اپنی کتاب بنام ''جم سلطان'' میں لکھتا ہے: جب غرناطہ حکومت کے گرجانے کی خبر منتشر ہوئی واٹیکان اور شہر روم کے مختلف مقامات چراغاں ہوا، جشن، نمائش، گھوڑ سواری اور گائے بازی کے مسابقات پے در پے برپا ہوتے رہے۔ انھیں نمائشوں میں سے ایک نمائش میں دو لوگ بنام (( Ferdinand, lsabella ''فرذینانڈ ایسابل ''کا حلیہ بناکر ظاہر ہوئے اور ان کے سامنے ایک دوسرا شخص ابوعبد اللہ کے بھیس میں زنجیر و بیڑی میں جکڑا ان دونوں کے قدموں پر گرا ہوا تھا۔ تماشائی اسپانیائی شہزادی اور شہزادے نے اپنے اتحاد کے ذریعہ مسلمانوں کو سینکڑوں سال بعد شکست دیدی غرناطہ کی حکومت کا خاتمہ کردیا تھا، تو وہ لوگ شاہ اور اس کی بیگم کے روبرو خوشی میں شاد و خرم ہو ہو کر خوش حالی سے نعرے لگاتے تھے۔
اس جشن کے چشم دید گواہ میں بایزید دوم، سلطان عثمانی کا بھائی جم تھا کہ جسے پاپ نے سلطان عثمان کو خوش رفتار رہنے کے لئے اسے اپنے پاس قید کررکھا تھا۔ اسی فرانسوی مؤرخ کے بقول، ابوعبد اللہ کا پابہ زنجیر ہونا اور اس (( Ferdinand, lsabella کے قدموں میں گرنا ہر نمائش سے زیادہ اس شاہزادہ کے لئے سخت تھا۔ ایسی نمائشوںکو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیتھولک کے سربراہ ایسی نمائشوں کے برپا کرنے کے ذریعہ مسلمانوں کی ذلت کو دکھانا چاہتے تھے اور وہ بھی جم سلطان کے سامنے یا اس کے دائرہ ٔ اطلاع میں برپا کرنا جو اپنے دور کی سب بڑی اسلامی حکومت کے تخت و تاج کا مالک ہونے والا تھا۔ وہ اپنے اس عمل کے ذریعہ عالم عیسائیت کو سمجھا نا چاہتے تھے کہ
۱۔اب جہان اسلام زمان سابق کے بر خلاف غرب کے مقابلہ میں ناتواں اور عیسائیت اسلام کے مقابلہ میں کامیاب ہے۔
۲۔مسلمانوں اور مخصوصا عثمانی بادشاہوں کی اند رونی کیفیت کا شیرازہ بکھیر دیا جن میں حکمرانی اور جہان بانی کا شوق پایا جارہا تھا۔(۵۹)
قدرت اور امنیت
ایسے حالات میں یہ فطری طور پر افکار و محسوسات قدرت و امنیت کے خالق اور حافظ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور عدالت سے کوئی سر وکار نہ ہو کہ اس کی رعایت کی جارہی ہے یا نہیں، ان حالات میں جو بات قابل اہمیت تھی وہ صاحب قدرت اور شان و شوکت کا حامل ہونا تھا اس لئے کہ یہی عوامل دشمن کو ڈرا سکتے تھے اور اسلام کی سرحدوں کی محافظت کرسکتے تھے اسی وجہ سے ہر ایک حاکم کو قدرت مند بنانے اور اسے صاحب قوت بنانے کی فکر میں مشغول ہوتا تھا۔ یہ ہر ایک کا وظیفہ ہے اور وہ بھی ایک دینی اور اسلامی وظیفہ۔ اس لئے ان کے نزدیک اسلام سے دفاع اس طرح حاکم سے دفاع کے مترادف تھا، کہ حاکم سے دفاع کئے بغیر اسلام سے دفاع ممکن نہیں تھا ان لوگوں کی نظر میں شخص حاکم اہم نہیں تھا اور وہ کیا کرتا ہے اور کس حد تک احکام اسلامی نیز عدالت کا پابند ہے، یہ سب ان کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا بس ان کے لئے یہ اہم تھا کہ وہ اسلام کا نمونہ ہے اور ہر ایک کو اسی کی خدمت میںہونا چاہئے، اس کے احکامات اور فرامین کی اطاعت کرتے ہوئے اسے قوی بنانے میں تمام تر کوشش صرف کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ا س لئے کہ یہ ظاہری شان و شوکت ہے جو داخلی دشمنوں کو خاموش رہنے پر مجبور کردیتی ہے اور بیگانوں کو ڈراتی اور امن و امان قائم کرتی ہے۔(۶۰)
اسی نکتہ کو ابن حنبل اس مقام پر بڑے اچھے انداز سے توضیح دیتے ہیں کہ جہاں حکام کی اطاعت کو واجب شرعی قرار دیتے ہیں، حکام اور امیر المؤمنین کی اطاعت واجب ہے خواہ وہ صالح ہو یا فاجر ہو اور اس شخص کی اطاعت جسے لوگوں نے خلیفہ کے عنوان سے قبول کرلیا ہے یا وہ شخص جو شمشیر یا قہر و غلبہ کے ذریعہ ان پر مسلط اور ان کا خلیفہ بن گیا یا امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوا ہے جہاد امیروں کی ہمراہی میں لازم ہے خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، روز قیامت تک مقبول ہے، ان کی طرف سے غنائم کی تقسیم، خراج اور حدود کو قائم کرنا قبول ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے جو اسے طعنہ دے یا ان کے مقابلہ میں کھڑا ہو۔ انھیں صدقات دینا جائز اور کافی ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، ان کی امامت میں نماز پڑھنا اور وہ شخص کہ جس کی امامت میں نماز صحیح ہے، ان کی امامت میں نماز پڑھنا صحیح ہیاور جو ان نمازوں کا اعادہ کرے بدعت گذاری، آثار سلف کو اہمیت نہ دینا اور سنت کی مخالفت ہیاور جو امیروں کی امامت میں نماز جمعہ پڑھنے کو صحیح نہ سمجھتا ہو وہ صالح ہوں یا فاجر، گویا اس نے نماز کی فضیلت کو درک نہیں کیاہے، بلکہ سنت تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ دو رکعت نماز بجالائی جائیاور اس کے کامل ہونے کا اعتقاد بھی رکھا جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا چاہئیاور اگر کوئی مسلمانوں کے امام پر خروج کرے جبکہ لوگوں نے اس کے گرد حلقہ بنا لیا ہو اور اس سے خواہ اپنی رضا و رغبت سے یا قہر و غلبہ کی وجہ سے راضی ہوگئے ہوں، تو اس نے مسلمانوں اور سنت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کی مخالفت کی ہے اور اگر وہ مرجائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔(۶۱)
مسلمان صدر اسلام میں ایسے حالات میں جی رہے تھے اور یہ کلام صدر اسلام میں کہ جس میں اہل سنت کے کلامی و فقہی عقائد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، صحیح تھا۔ یہ اصول و قوائد ایسے ہی شرائط اور ضرورتوں کے تحت بنائے گئے۔ البتہ آنے والی دہائیوں نے اسے ثابت بھی کردیا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے کلام میں اس دور کے لوگوں کی ذہنیت اور ان کی حساسیت کو بخوبی بیان کیا ہے جس کی بعد میں امیروں نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے تائید کی ہے۔ وہ کہتا ہے:
''ضعف السلطان اضر من جوره لان ضعفه یعم و جوره اخص''
یعنی سلطان کے ضعیف ہونے کا ضرر اس کے ستم سے کہیں زیادہ ہے اس لئے کہ اس کا ستم خاص لوگوں کو اور ضعف ہر ایک کو شامل ہوتا ہے۔(۶۲)
اس دور میں اس بات کا امکان تھا کہ اس میں سے صرف کسی ایک کا انتخاب کیا جائے، یا فسادات، ہرج و مرجاور خارجی دھمکیوں پر راضی ہوجائیں یا پھر حاکم کے ظلم و استبداد اور جور کے سامنے تسلیم ہوجائیں اس کے اسلام کی سیدھی راہ اور عدالت سے منحرف ہوجانے کو تحمل کریں، ایسے حالات میں عموما دوسری صورت کو انتخاب کیا جاتا ہے۔
غزالی کا نظریہ
غزالی اس مقام پر اپنے نظریہ کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں امامت کے عقلی نہیں بلکہ شرعی وجوب کے اثبات کی کوشش کرتے ہوئے ایسے مطالب کو ذکر کرتے ہیں کہ جو گذشتہ بیان کی گئی مشکلات اور اس کی وجہ سے ہونے والے اعتراضات پر ایک روشنی بھی ہے...۔
لیکن دوسرا مقدمہاور وہ یہ ہے کہ قوی او بہادر سلطان کے ذریعہ دنیاوی امور، جان و مال کی امنیت برقرار رکھی جاسکتی ہے، اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ جب کوئی سلطان یا خلیفہ مرجاتا ہے تو اگر اس کے مرتے ہی کوئی قابل اطاعت خلیفہ یا اس کا جانشین نہیں آتا تو فساد شروع ہوجاتا ہے اور ہر طرف قتل و غارتگری پھیل جاتی ہے، قحط و بھوک مری شروع ہوجاتی ہے اور چوپایے مرنے لگتے ہیں اور صنعتیں بند ہو جاتیں ہیں، اشرار قتل و غارتگری میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کسی کو موقع بھی نہیں مل پاتا ہے مگر یہ کہ کوئی اپنی جان بچا کر فرار کرجائے، عبادت یا تحصیل علم میں مشغول ہو جائے، ایسے فسادات میں اکثر مارے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ دین و سلطان جوڑواں ہیں۔ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ بہت جلد نابود ہو جاتی ہیاور جس کا کوئی نگہبان نہیں ہوتا نتیجةً ضائع ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر عاقل انسان کو یہ معلوم ہے کہ عوام کو ان کے مختلف طبقات، افکار اور رجحانات کے ساتھ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی ایسا فرد ان کا نگہبان نہ ہو جو انھیں جمع کرسکے تو وہ نابود ہو جائیں گے، اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ ایک قدرتمند سلطان کہ جو ہر ایک پر مسلط ہو۔
پس اب یہ بات روشن ہو گئی کہ کسی نظام کو باقی رکھنے کے لئے ایک سلطان کی ضرورت ہے۔ دین کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لئے دنیوی نظام کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اخروی فلاح و بہبود کے لئے دین کے نظام کی ضرورت ہے اور یہی وہ نکتہ ہے کہ جو انبیاء (ع) کا ہدف رہا ہے، پس معلوم ہوا کہ امام کا ہونا شرعی ضرورت ہے کہ جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا اس نکتہ کو خوب یاد رکھ لو۔(۶۳) لیکن قاضی عبد الرحمن بن احمد ایجی، معروف متکلم اسی نظریہ کو بیان کرتے ہیں، وہ وجوب نصب امام کے لئے ضرر محتمل کو قرار دیتے ہیں اور اس نکتہ کی تصریح میں فرماتے ہیں:
اب ہم اپنے علم کی بنیاد پر کم و بیش یہ جانتے ہیں کہ شارع کا مختلف قوانین کے وضع کرنے کا مقصد، وہ خواہ معاملات یا مناکحات سے متعلق ہو یا جہاد، حدود، و قصاص یا روز جمعہ و اعیاد دینی شعائر کی تعظیم، ہو ان کے تحت کچھ مصلحتیں ہیں جو دنیا یا آخرت میں اس کے بندوں کے نفع میں ہیں اور رہیں گیاور یہ مصالح اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتے کہ جب تک کے شرع کی جانب سے کوئی امام معین نہیں کیا جاتا تاکہ جو اس سے مربوط ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے، اس لئے کہ عوام اپنی مختلف خصلتوں، آرزؤں، نظریات، جھگڑے کے ہوتے ہوئے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی دوسرے کے سامنے تسلیم ہوجائے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں جنگیں اور فسادات شروع ہوجاتے ہیں بسا اوقات سب کی ہلاکت ہوجاتی ہے یہ اس تجربہ کا نتیجہ ہے، جو ایک سلطان کے مرنے سے اس کے جانشین کے نصب ہونے تک جو فسادات ہوتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے اس لئے کہ اگر دوسرے خلیفہ یا سلطان کے انتخاب میں تاخیر ہوجائے تو روز مرہ کی زندگی معطل اور بے کار ہوجاتی ہے اور اس میں ہرج و مرج واقع ہوجاتا ہے اور اس مدت میں ہر ایک اپنی جان و مال اور ناموس کی حفاظت کے لئے دست بہ شمشیر ہو جاتا ہے جو دین اور تمام مسلمین کی نابودی کا باعث ہے۔(۶۴)
ہم نے مذکورہ بالا قول کو اس کی اہمیت کے پیش نظر کامل طور پر ذکر کر دیا ہے لیکن ان نکات کے ہوتے ہوئے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ دوسرا انتخاب یعنی حاکم کے ظلم و استبداد کے سامنے سر جھکا دینا اور اس کا راہ مستقیم اور اسلامی عدالت سے منحرف ہونا کہ جو خود ہی ایک قسم کی ضرورت کا نتیجہ تھا، ان کے درمیان استبداد پسندی کے تفکر کو جنم دینے کا باعث تھا اور اسی کی مناسبت سے تمام امور و جوانب میں افکار و مبانی کو اپنے مطابق شکل دی۔ یہ ایک وقتی ضرورت کے عنوان سے باقی اور جاوید اثر چھوڑتی ہے کہ جواب تک باقی ہے اور جوان نسلوں کو دانشوروں کی طرف سے بے شمار اشکالات پر آمادہ کیا ہے۔(۶۵)
حفظ نظام
یہ عوامل کا مجموعہ حفظ نظام اور اس کی فکری ضرورت کے پیش نظر ہے، صرف مسئلہ یہ تھا کہ نظام محفوظ رہے اور یہ ضرورت تمام ضرورتوں پر اولویت رکھتی تھی اور دوسرے عوامل یا تو اسے قوی بنانے یا وہ فرعی اور امر ثانوی کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایسا طرز فکر طبیعی طور پر ہر قسم کے نطفۂ اعتراض خواہ وہ عدالت کی برقراری یا سنت پیغمبر پہ عملی بازگشت کے عنوان سے ہوں، اسے وہیں دبا دے گا، اس تفکر کے دائرے میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ عموم افراد اس نطام کو قوی، مستحکماور اس کی حفاظت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور جو بھی اس سے جدا ہے وہ مسلمانوں کی صف سے خارج ہے یہاں تک کہ دین سے خارج ہوجانے کا نتیجہ ہو جایا کرتا تھا۔ ان شرائط کے تحت حد اقل اعتراض اگر ہوسکتا ہے تو وہ قلبی اور شخصی ہو سکتا ہے یعنی انسان حاکم کی بدعتوں کو دل سے قبول نہ کرے لیکن چونکہ اس کے سامنے اعتراض کرنا مسلمانوں کی صف سے خارج ہوجانے کا باعث ہے لہذا اس کا اظہار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کی ذمہ داری صرف قول و فعل کے بدلے دل سے انکار کرنا ہے۔ آنے والی داستان اس نکتہ کی خوب وضاحت کرتی ہے۔
ایک روز بغداد کے فقہا جمع ہوکر ابن حنبل کے پاس آئے اور کہنے لگے: اس شخص سے مراد عباسی خلیفہ واثق ہے جو مامون اور معتصم کی طرح خلق قرآن کی تبلیغ کرتا تھا، اس نے لوگوں کے عقائد کو فاسد کردیا ہے اور اپنے اس عمل سے باز نہیں آتا کچھ کرنا ہوگا؛ فقہا کا ارادہ یہ تھا کہ وہاں ابن حنبل سے اس کے مقابلہ میں ایستادگی (مقابلہ) کا فتوا حاصل کریں لیکن اس نے جواب میں کہا کہ تمھاری ذمہ داری صرف قلبی انکار ہے، آپ لوگ اپنے دل میں اس عقیدہ کا انکار کریں لیکن اس کے مقابلہ میں کھڑے ہونے یا اس کی مخالفت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔(۶۶)
ابن حنبل نے جو کچھ کہا وہ عافیت طلبی یا کسی ڈر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ وہ سختیوں کے دور کے قہرمان تھے جسے بعد میں ایام المحنة کا نام دیا گیا وہ خلق قرآن کے نظریہ کے اصلی ترین مخالفین میں سے تھے اور اس راہ میں اس حد تک اصرار کیا کہ ان کی بے حرمتی کی گئی اور انھیں بے حد مارا گیا، معتصم کے دور میں انھیں اس قدر تازیانے مارے گئے کہ نزدیک تھا کہ ان کی جان نکل جائے، ان کا جواب دینا عافیت طلبی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ وہ واقعا ایسی ہی فکر رکھتے تھے اور اسی کی وصیت بھی کیا کرتے تھے۔(۶۷)
لیکن وہ کیوں ایسی فکر کے حامل تھے یہ امر ان کے فقہی و کلامی مبانی سے مربوط ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، ان کا عقیدہ تھا کہ قہر و غلبہ اور تلوار کے زور پر امامت و خلافت ثابت تو ہوجاتی ہے اور جب وہ قائم ہوجائے تو کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اس کے سامنے قیام کرے اور جو قیام بھی ہوگا وہ نامشروع ہوگا۔ پس جب نظام اور حفظ نظام اصالت کی شکل اختیار کرلیں تو اس صورت میں یہ امر کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ کون اس کے مالک ہیں، یا اس میں حاکم کے شرائط ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ بے اہمیت ہوجائے گا۔ اصل نظام کا قدرتمند ہونا ہے نہ کہ وہ شرع و عدالت کے موافق ہے یا نہیں، یہ مسئلہ وجوب اطاعت و مشروعیت کا باعث بنتا ہے نہ کہ اس کی خصوصیات اطاعت و مشروعیت کا باعث ہے اور چونکہ ایسے شرائط حاکم میں پائے جاتے ہیں لہٰذا اس خلیفہ کی اطاعت واجب ہے جو خلق قرآن کا معتقد اور اس کی تبلیغ و ترویج کرتا ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کا اعتقاد تھا کہ حاکم کی مخالفت کے نتیجہ میں ہونے والے نقصانات قولی و فعلی امر بہ معروف اور نہی از منکر کے نتیجہ میں حاصل ہونے والے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے۔ اگرچہ یہ ایک حق بات ہے، لیکن اگر اس کے حدود معین نہ ہوں اور ہر صورت میں اسے درست مان لیا جائے تو اس صورت میں استبداد اور دین و عدالت سے انحراف کے لئے ایک بہترین موقع فراہم ہو جائے گا جیسا کہ ایسا ہی ہوا بھی ہے۔(۶۸)
بالکل اسی بنیاد پر تھا کہ جس کی وجہ سے ابن حنبل نے کہا کہ واثق کے خلاف زبان اعتراض نہ کھولنا اور کوئی اقدام بھی نہ کرنا اور اسی نکتہ کی وجہ سے تھا کہ معتصم، شدت پسند، جاہل اور قدرتمند خلیفہ کو امیر المؤمنین کے علاوہ کسی دوسرے نام سے نہ نوازیں، جب کہ اسی کے ہاتھوں شدید تریں شکنجے برداشت کئے۔(۶۹)
یہی وہ عوامل تھے کہ جس نے اہل سنت کے بزرگ علما کے ذہنوں میں مسئلہ امنیت اور اسکے نظامی تحفظ کی فکر ڈال دی بالخصوص تیسرا عامل نہایت مؤثر اور فیصلہ کن تھا، نیز یہ اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک اساسی فرق تھا اور وہ عامل کہ جس کی وجہ سے شیعوں کو طول تاریخ میں مذمت یا انھیں سرزنش کی جاتی رہی، یہی تیسرا (آخری) عامل تھا۔ انھوں نے ہمیشہ کہا اور کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے اقدامات کے ذریعہ مسلمانوں کی صفوں سے خارج اور اختلاف کے پیدا ہونے کا باعث ہیں، بلکہ بعض تو اسی علت کی وجہ سے امام حسینـ پر اعتراض کرتے ہیں، کہ کیوں انھوں نے مسلمانوں کے اجماع کے خلاف قدم اُٹھایا اور ان(کی صفوف) میں تفرقہ ڈالا۔(۷۰)
یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امامـ پر کی جانے والی تنقید صحیح ہے یا نہیں یعنی کیا امامـ نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا یا مسئلہ کچھ اور تھا، یہاں جو چیز ہر ایک سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تنقید ان کے افکار اور اعتقاد کا نتیجہ ہے، ایسے خیالات کا مالک ہونا ایسی ہی تنقیدوں کا باعث ہوتا ہے اور ایسا ہوا بھی۔ وہ لوگ جو امامـ پر اعتراض کرتے ہیں وہ ایسے خیالات کے مالک ہیں اور وہ لوگ کہ جنھوں نے اپنی زبانیں بند رکھیں ان مخصوص روایات کی وجہ سے ہے کہ جو آپ کی شان میں ہیں بلکہ اہل سنت کے بزرگ علما نے ان روایات کو نقل بھی کیا ہے۔ یعنی مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنے کی حرمت جو ان کے افکار کا ایک طبیعی نتیجہ تھا اور وہ روایات جو امامـ کی شان اور مرتبہ پر دلالت کرتی ہیں، ان دونوں کے درمیان تضاد کو دیکھتے ہوئے احادیث کو اختیار کیا ہے، ان لوگوں کا خاموش رہنا بلکہ بعض مواقع پر تمجید و تعریف کرنا اسی علت کی وجہ سے تھا نہ اس وجہ سے تھا کہ واقعہ کربلا ان کے فقہی و کلامی موازین اور معیار سے موافق تھا۔ البتہ اس مقام پر اہل سنت کے ان علما کے سلسلہ میں ہماری بحث ہے جو الگ تھلگ اور حکومتوں سے وابستہ نہیں ہیں، ورنہ ان کے درمیان دین فروش اور ظلم و استبداد کے خوگر علما بھی ہیں جو فاسد حکام کے اعمال و کردار کی توجیہ کے لئے لاف و گزاف باتیں کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اگرچہ ان کی بات امام حسینـ کی اہانت کا باعث ہی کیوں نہ بنے۔
ابن قیم کا نظریہ
اس مقام پر بہتر ہے کہ اہل سنت کے فقہا میں سے ایک عظیم فقیہ ابن قیم کے نظریہ کو ذکر کریں، وہ اپنی اہم اور واقعی کتاب اعلام الموقعین میں ایک جدا فصل بنام زمان و مکان، احوال و نیاتاور نتائج کے تغیر کے ساتھ فتوی کا مختلف اور متغیر ہو جانا ہے، وہ اس فصل میں کہتے ہیں: کہ کیا شریعت لوگوں کے دنیوی اور اخروی مصلحتوں کی وجہ سے بنی ہے؟ ایک مفصل بحث کرتے ہیں اور پھر نہی از منکر کے درجات اور اس کے شرائط کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس نکتہ کے تحت اس طرح اپنے بیان کو جاری رکھتے ہیں: آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت نے نہی از منکر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ وہ احکامات اجراء ہوں جسے خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، پس اگر اسی نہی از منکر کی وجہ سے کوئی عظیم منکر اور عصیان انجام پائے کہ جسے خدا اور اس کا رسول ناپسند کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ خدا ایسے منکر کو پسند نہیں کرتا اور اسے انجام دینے والے کو عذاب دے گا جیسے کہ قیام اور خروج کے ذریعہ سلطان یا کسی والی (گورنر) کے لئے نہی از منکر کرنا، کیونکہ یہ نہی از منکر ابد تک کے لئے ہر فتنہ کی جڑ ہے، اصحاب نے آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت سے ان والیوں اور امیروں سے قتال کرنے کے سلسلہ میں سوال کرتے ہیں کہ جو نماز میں اس کے وقت سے تاخیر کرتے ہیں، تو کیا ہم ان سے قتال کریں؟ تو آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت نے جواب میں فرمایا: نہیں، جب تک کہ وہ نماز کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی امیر کو کسی ایسے کام میں مشغول دیکھے جو اس کے نزدیک مکروہ ہے تو صبر کرے اور اس کی اطاعت سے منھ نہ موڑے۔اگر کوئی شخص اسلام پر وارد ہونے والی بڑی یا چھوٹی بلاؤں کا تجزیہ کرے تو اسے بخوبی معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ اس اصل پر عمل نہ کرنے اور منکر پر صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں نے ایک منکر کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگئے، آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت نے مکہ میں بڑے بڑے منکرات اور ناپسندیدہ امور کا مشاہدہ کیا، لیکن آپ میں اتنی قدرت نہ تھی کہ اس کی روک تھام کرتے۔ لیکن جب خدا وند عالم نے مکہ کو آپ کے لئے فتح کردیا اور وہ دار السلام بن گیا تو پھر آپ نے خانہ کعبہ میں تبدیلی لانے کے لئے کمر ہمت باندھی اور اسے ویسا ہی بنایا جیساکہ جناب ابراہیمـ نے بنایا تھا، لیکن جس بات نے آپ کو اس مہم سے روکے رکھا تھا درواقع آپ قادر بھی تھے لیکن ایک بڑے فتنہ میں گرفتار ہوجانے کا ڈر تھا، اس لئے کہ اس حرکت کو قریش برداشت نہیں کرسکتے تھے کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفر کو چھوڑے ہوئے انھیں زیادہ دن نہیں گذرے تھے، یہی علت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے امیروں سے جنگ کا حکم نہیں دیا اور اس منکر کو روکنے کیلئے کوئی اقدام نہ کریں ورنہ اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہوجائے گا۔(۷۱)
عدالت خواہی اور قدرت طلبی
اس مقام پر اہم یہ ہے کہ ان دو نظریات اور تفسیروں کے نتائج بالکل جد ا اور متفاوت ہوں گے تاریخ تشیع اور تسنن نیز ان کی موجودہ صورت حال کے تجربوں نے اس بات کو ثابت کردیا ہے کہ وہاں نظریات اور تفاسیر سے زیادہ انھیں دو مختلف اقسام کے نتیجہ سے متاثر ہیں، ان میں سے ایک مہم ترین فرق یہ ہے کہ دوران معاصر میں انقلابی عناصر اہل سنت کی حکومت میں بالکل شیعہ حکومت کے خلاف انقلابی عناصر جو عدالت خواہ اور قدرت طلب ہے، اس سے بالکل متفاوت ہے۔(۷۲)
دور حاضر میں حقیقی شیعوں کی سب سے بڑی مشکل بلکہ سب سے حساس ترین اور پریشان کن بات ان کی عدالت خواہی ہے۔ ان کے اسلامی اور سیاسی اعتقاد اور طرز فکر جو ان کے لئے الہام بخش اور ان کی تحریک کا سرچشمہ ہے وہ ان کی عدالت خواہی انصاف پسندی ہے وہ لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے تاکہ عدالت کو پورے معاشرہ میں قائم کرسکیں، یا بالفاظ دیگر یہ کہنا مناسب ہے کہ انھوں نے قیام کیا ہے تاکہ ایسے اسلام کو برپا کریں جس کا اصلی پیغام عدالت اور اس کی برقراری اور استواری کو استحکام بخشیں جب کہ اہل سنت کے درمیان اٹھنے والی تحریکیں صرف اس لئے ہیں کہ وہ ایک قدرتمند اور باعظمت اسلامی مرکز کی بنیاد ڈالیں، صدر اسلام میں قائم مسلمانوں کی قدرت و شوکت کو دوبارہ پہلے ہی کی طرح برقرار کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ گذشتہ جیسی قدرت کے مالک رہیںاور ان کے لئے قدرت کے نمونے صدر اسلام میں خلفاء ہیں، ان کی نظر میں اسلام دین کے پہلے مرحلہ ہی میں ایک قدرت ہے اور اس کی تاریخ قدرت اور اقتدار ہے۔ لیکن ان کے مقابلہ میں شیعہ بلکہ اس دور کے شیعہ پہلے دور میں اسلام کو دین عدالت قرار دیتے ہیں اور اس کی اصلی تاریخ عدالت اور انصاف ہے مثلا ان کی نظر میں خلیفہ دوم کی مہم ترین خصوصیت قدرت و عظمت ہے اور ان لوگوں کی نظر میں امام علیـ کی مہم ترین خصوصیت آپ کی عدالت اور مساوات ہے۔ وہ لوگ صدر اسلام کے تابناک اور درخشان دور میں خلفاء کی شکل میں ایسے قدرتمند افراد کو دیکھتے ہیں جو اس دور میں ایک عظیم حکومت حاکم تھی درحقیقت اس دور میں سچے خلفاء کی شکل میں عدالت و انصاف اور مساوات کا مظہر دیکھتے ہیں جو ایک سادہ انسان کی طرح زندگی گذارتے تھے اور تنہا دین و عدالت کی خاطر سر جھکاتے تھے اور بس۔(۷۳)
درست یہی علت موجب تھی کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جب قدرت اور حکومت کی باگ ڈور ذمہ دار انقلابیوں کے ہاتھ میں آگئی، تو اس کے داخلی تغیرات کا عدالت اور عدالت اجتماعی کے اجرا کرنے یا اسے اجرا نہ کرنے کی بہ نسبت جائزہ لینا چاہئے۔ تمام نکات میں ہر ایک سے اہم نکتہ جو انقلاب کے بعد داخلی اُتار و چڑھاؤ کی شکل میں نظر آتا ہے وہ یہی نکتہ تھا۔ اور دوسرے مسائل اسکے بعد اہمیت رکھتے تھے لیکن اگر بالفرض ایسا کوئی انقلاب اہل تسنن کی سرزمینوں پر واقع ہوتا تو یہ مسلم تھا کہ عدالت کی بہ نسبت لوگ اس قدر حساس نہ ہوتے بلکہ احتمال قوی تو یہ ہے کہ وہ اس انقلاب کو قدرتمند بنانے کی فکر میں رہتے۔ البتہ یہ روش اس انقلاب کے قدرتمند ہونے اورمکمل طورپر اجتماعی نیز مختلف افکار کے حامل عناصر کے جذب ہونے کا باعث ہوتی۔(۷۴)
انقلابی پوشیدہ توانائیوں کے مقامات
امنیت و عدالت کے متعلق ایسے تفکرات کا ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت کی حکومت میں ہونے والے اکثر قیام دینی اور ثقافتی لحاظ سے بامقصد تھے اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ان میں سیاسی تحریکیں دیکھنے میں آئی ہوں، جبکہ تشیع کی حکومت میں فاطمی خلفاء کے ہونے کے باوجود سیاسی تحریکیں کثرت سے دیکھنے میں آئی ہیں، شیعوں کے نزدیک حکام کے خلاف قیام کے لئے تا حدکافی دلائل تھے۔ لہذا شیعوں کے نزدیک ایسے قیام کے وجود میں آنے کا امکان ان اہل تسنن کی بہ نسبت کہیں زیادہ تھا جن کے پاس نہ ایسے اصول تھے بلکہ ایسے قیام موجودہ نظام کے لئے مخل تھے لہذا ان کے نزدیک نامشروع اور ناجائز شمار کئے گئے ہیں۔
اہل سنت کے درمیان دین و تہذیب کی خاطر ہونے والے قیام تنہا ان کے نزدیک سیاسی و معاشرتی نظری اصول کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔ معاشرتی و سیاسی میدان میں کہ جو جائز بھی ہو اور ان میں انقلابی عوام کی تغییر طلب توانائیوں کو اپنے اندر جگہ بھی دے سکے اور انھیں کامل ہدایت کرسکے، فطری طورپر ایسی تبدیلیاں اور اصلاحات وغیرہ دین و تہذیب کے دائرے میں امکان پذیر ہیں اورشیعوں کے لئے ایسی کوئی مشکل نہیں تھی جو اہل تسنن کیلئے ہے، بلکہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ انقلابی توانائیاںاپنے مشروع دائرے میں جاری ہوں خواہ وہ معاشرتی ہوں یا سیاسی یا اسلحوں کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہوں، اس سلسلہ میں کوئی مشکل نہ تھی لہذا انقلابی توانائیاں اپنا ایک فطری مقام حاصل کرچکیں، لیکن اہل سنت کے لئے ایسا کوئی امکان نہیں تھا، ان کے وہاں عصیان و طغیان اور عمومی غم و غصہ کے اظہار کرنے کے مقامات بند کردئے گئے تھے؛ حاکم اور بدعتوں کے خلاف قیام نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر تحریکیں بے دینی اور کج فکری کو مٹانے کی خاطر وجود میں آئی تھیں بشرطیکہ ان کا حاکم سے کوئی ربط نہ ہو۔ کبھی یہ تحریکیں معتزلہ سے مقابلہ کے لئے کبھی شیعیت و تصوف اور فلاسفہ سے مقابلہ کے لئے تو کبھی مذاہب اربعہ اور فقہی اور کلامی مکاتب میں سے کسی ایک سے مقابلہ کے لئے اور کبھی لوگوں کے عقائد اور ان سے مقابلہ کے لئے وجود میں آتی تھیں جو ایک خاص، متعصب اور خشک مزاج گروہ کے لئے ناپسند تھے جس کی وجہ سے ان کے مال، ناموس اور خون ہدر اور حلال ہو جاتے تھے۔(۷۵)
تاریخی لحاظ سے مسلمانوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کے لامتناہی سلسلہ کا اصلی سبب یہی عامل تھا۔ ان فرقوں میں متعدد مشترک نکات کے ہوتے ہوئے جو انھیں ایک مرکزی نکتہ کی طرف راہنمائی کرتے تھے، ان نکات کے ہونے کے باوجود اسلام کی تاریخ میں اسلامی فرقوں کے درمیان خوںریز لڑائیوں کی کثرت ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی، سیاسی اور قومی عوامل بھی دخیل رہے ہیں۔ لیکن اس نکتہ کو فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ انقلابی توانائیوں کے خروج کے لئے جائز اور صحیح مقامات نہ ہونے کی وجہ سے کہ جس کی مدد سے سیاسی اورمعاشرتی اصلاحات انجام دی جاتیں ہیں، خود ایسی توانائیوں کے منحرف ہونے کا عظیم عامل ہے جو فطری ہونے کے ساتھ ساتھ ہے، جب ایسی توانائیاں اپنے جائز مقامات سے خروج کے لئے محروم کردی گئیں تو اس صورت میں یہ امر فطری ہے کہ یہ توانائیاں ان مقامات سے خارج ہوں گی جو ان کی نظر میں جائز ہوں گی۔ اور بجائے اس کے کہ اسے حاکم کے نظام کو برقرار کرنے کے لئے صرف کرے مختلف بہانوں سے خود مسلمانوں کیلئے وبال جان بن جائے گی۔(۷۶)
یہ بات مخصوصا اسلام جیسے دین کیلئے بہت اہم ہے۔ اسلام دوسرے ادیان کے مقابلہ میں کہیں توانا ہے کہ وہ انھیں اکٹھا کرنے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں قدرتمند ہے، دیگر ادیان بھی کم و بیش فردی کامیابیوں کے لئے اپنی توانائیوں کو صرف کرتے ہیں، دین کوئی بھی ہو اس کا آخری ہدف فرد کی فلاح اور کامیابی ہے، اسلام بھی ایسا ہی دین ہے، لیکن اس میں اور دیگر ادیان میں فرق یہ ہے کہ یہ انفرادی کامیابی اجتماعی کامیابی کے زیرسایہ حاصل ہوتی ہے کہ جو اس دین کی ترقی میں ہو۔
انتہائی کامیابی یہ ہے کہ یہ دین اپنیمعاشرتی ہدف کو حاصل کر لے اور انسان اسی صورت میں کامیاب ہوگا کہ جب وہ اپنے آپ کو ایسے اہداف کے حصول کی خاطر وقف کردیاور چونکہ ایسا ہی ہے لہذا یہ دین یعنی دین اسلام دوسرے ادیان کے مقابلہ میں ہر ایک سے بہتر افراد کی پوشیدہ استعداد کو آشکار کرے اور ان صلاحیتوں کو اپنے اہداف کی کامیابی کے راستہ میں صرف کرے، یہی وجہ ہے کہ ا یک مسلمان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنی استعداد کو زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے پھیلانے میں صرف کرے اور فداکاری کی حد تک کوشش کرے، اس کا یہ عمل اس کی انتہائی کامیابی کا راز ہے۔ لیکن دوسرے ادیان میں یہ کامیابی ایک قسم کی نفسانی تمرین یا کسی فردی یا بعض اوقات اجتماعی کوششوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہ کوشش بھی اسلام کی طرح اجتماعی اور اسے عمومی بنانے کے لئے نہیں ہوتی۔ لیکن اس دین میں یہ کامیابی اکثر انفرادی یا اجتماعی کوشش کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی اجتماعی کوشش کہ جو اس کے اہداف کو کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ اس درمیان اہم بس یہ ہے کہ اسلام میں اتنی توانائی ہے کہ وہ ایک مسلمان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو تجلی بخشے اور اس کی اچھی طرح پرورش کر کے انھیں استعمال کرسکتا ہے۔(۷۷) یہ موضوع کی مزید وضاحت کے لئے اس سلسلہ میں بحث کی جائے۔
انسان میںفداکاری کا جذبہ
انسان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی دوسری شی کے ضمن میں یا کسی شی کے تحت الشعاع میں آنا چاہتا ہے، انسان کی یہ خصوصیت ثابت اور تغییر ناپذیر ہے اور اگر کسی شخص میں یہ خصوصیت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ خصوصیت بالکل نہیں جاتی ہے بلکہ یہ اختلال اس کے اندرونی پراکندگی کی وجہ سے ہے، ایسے لوگ مختلف اور گوناگون عوامل کے درمیان واقع ہوتے ہیں۔اور ان کی توانائیاں پراکندہ ہوچکی ہیں، نیز ان میں ایسی خصوصیات کو اظہار کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔
لیکن وہ عناصر جو انسان کو اپنے جاذبہ میں لے سکتے ہیں ان میں ایک دین ہے کہ جو بدون شک ہر ایک سے اہم اور توانا ہے اور یہ ایسا صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں دین خواہی اور خدا پرستی کی فطرت موجود ہوتی ہے اور دوسری طرف خود دین عظیم مفاہیم کا مجموعہ اور صاف و شفاف ماہیت کا حامل ہے، یہی وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے دین انسان میں اس کی تہوں تک نفوذ کرجاتا ہے اور اسکی مرئی اور غیر مرئی تمام طاقتوں کو خود استعمال کرتا ہے۔ اس مسئلہ میں اسلام اور دوسرے ادیان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عیسائیت ایسی خصوصیت سے سرفراز نہیں ہے قرون وسطی میں عیسائیت نے اپنے ماننے والوں کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح اسلام نے اپنے ماننے والوں کو استعمال تھا۔ ایک عیسائی مبلغ یا جنگجو اسی جوش و ولولہ کے ساتھ جاںفشانی کرتا تھا کہ جس طرح ایک مسلمان مبلغ یا مجاہد کرتا تھا لیکن اس دور میں اسلام کے علاوہ تمام ادیان نے اپنی اس روش میں تجدید اور اس کا رخ بدل دیا ہے، بہت سی حقیقتوں، عناصر اولیہ اور اصول سے چشم پوشی کرلی ہے، موجودہ عیسائیت قرون وسطی کی عیسائیت کے مقابلہ میں درست اور ایک ایسے دین میں ڈھل چکی ہے کہ جس میںاپنی محدودیت کی وجہ سے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گذشتہ ایام کی طرح اپنے چاہنے والوں کی توانائیوں کو اکٹھا کرسکے اور انھیں اپنی خدمت میں لے سکے۔
اور آج جو عیسائیوں میں ایام سابق کی طرح قدرت نہیں پائی جاتی تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہیں بلکہ اکثراس عیسائیت کے ضعف کی وجہ سے ہے جس کے وہ معتقد ہیں اس لئے آج کی عیسائیت میں وہ قدرت اور قاطعیت نہیں ہے جو ایام سابق میں تھی بلکہ اس قدرت کی حامل نہیں ہے کہ جس کا ہر مذہب محتاج ہوتا ہے،جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دین اپنی بقا یا کسی دوسرے بہانوں کی وجہ سے تمدن جدید، اس کی ضرورتوں اور اس کے اقتضائات کی وجہ سے بلکہ اپنے مادی معیاروں اور نظام مادی کی وجہ سے قدم بہ قدم پیچھے ہٹتا جارہا ہے اور اپنی حقیقت کو کھوبیٹھا ہے اور موجودہ صورت کے مطابق ہونے کی فکر میں ہے، یہ امر جس طرح بھی واقع ہو وہ اپنی بچی کچھی توانائی بھی کھو بیٹھے گا جس کے ذریعہ وہ اپنے ماننے والوں اور اپنے عاشقوں کے درمیان تبدیلی لانا چاہتا ہے گا تاکہ اس کی راہ میں جانثاری کرے، آج کے دور میں عیسائیوں کا ضعف ان کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس عیسائیت کے ضعف کی وجہ سے ہے کہ جو آج کلیسا کے ذریعہ تبلیغ کیا جارہا ہے۔(۷۸)
آج کے دور میں دوسرے ادیان اور خصوصا عیسائیت میں ایک بنیادی فرق یہی ہے۔ اسلام نے ایسے مختلف اسباب جو خود اس کی ماہیت سے مربوط ہیںاور ان کی وجہ سے دور حاضر میں اس راستہ کو نہیں انتخاب کیا جسے اپنا نے کے لئے دوسرے ادیان مجبور ہوئے او ر اسلا م ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا، قرن حاضر کے متمد ن مسلمانوں نے بہت کوشش کی اور اس کی ماہیت سے چشم پوشی کرتے ہوئے آج بھی اسی انتخاب پر اصرار کررہے ہیں جسے دوسرے ادیان نے اپنالیا ہے۔ شاید یہی وہ اسباب ہیں کہ عصر حاضر میں جوانوں کے وہ اعتقادات نہیں ہیں جو ان کے آباء واجداد کے تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین نے زمانہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصالت اور حقیقت، خلوص اور صراحت و قاطعیت، یقین اور تمامیت کی حفاظت کرنے کے بجائے سابق جاذبہ کو محفوط رکھا ہے اور ابھی اسی خلوص اور جاذبوں سے سرفراز ہے جن کا ایام سابق میں حامل تھا۔ جس طرح آج نسل جوان کو سیراب کررہا ہے اسی طرح قرون گذشتہ میں ان کے اسلاف کو سیراب اور انھیں استعمال کیا ہے۔(۷۹)
بہرحال ہماری بحث اسلام کے سلسلہ میں یہ تھی کہ اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کی پوشیدہ قدرتوں کو آشکار کرے اور انھیں اپنا عاشق بنالے اور انھیں اپنے اہداف کی راہ میں اکٹھا طاقتوں کو اپنے اہداف و مقاصد کی ترقی میں استعمال کرے لیکن نکتہ یہاں پر ہے کہ جب بھی طاقتیں یہ پروان چڑھیں اور آشکار ہوئیں انھیں سیاسی و اجتماعی میدان میں ظاہر ہونے کا موقع نہیں مل سکا اور انحراف اورتعصب کا شکار ہوگئیں۔ اور پھر اس شی کے مقابلہ میں آجاتی ہیں جسے بدعت کا نام دیا جاتا ہے، جب احساسات اور عواطف جوش میں آتے ہیں تو عقل و منطق بیکار ہوجاتی ہے، اس صورت میں انسان بدعتوں کا مقابلہ کرکے دین سے متعلق اپنے فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے موقع پر اس کے لئے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ جس پر وہ حملہ کر رہا ہے وہ اس کا خونی بھائی ہے یا دینی بھائی،بلکہ اس کی نظر میں مدمقابل سے مقابلہ دین سے اخلاص کا ایک وسیلہ ہے اور اس کا یہ عمل دین و حق اور قرآن و پیغمبر کی نصرت کی مانند ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ سامنے والے کو منحرف سمجھ رہاہے اگرچہ اس کا انحراف ظنی یا وہمی ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوشش رہتی ہے کے اس سے مقابلہ کرکے اپنی ایثار و قربانی کی آگ کو خاموش کرے اور پوشیدہ فداکاری کو آشکار کرسکے۔(۸۰)
اسلامی تاریخ میں اہل تسنن کے درمیان خونین جنگوں کے حوادث کم نہیں ہیں۔ مقام تعجب ہے کہ حنفی، شافعی۔(۸۱) اہل حدیث یا غیر اہل حدیث کے درمیان شیعوں کی بہ نسبت خونین جنگوں کی کثرت ہے۔(۸۲) یہاں تشیع یا غیر تشیع کا مسئلہ نہیں تھا۔ البتہ جس نکتہ کو ہم نے بیان کیا اس کے تحت اہل تسنن کے طرف سے شیعہ مخالف حرکتیں اور شیعوں کی طرف سے اہل سنت مخالف تحریکیں کہیں زیادہ وجود،میں آئی ہیں، اس لئے کہ شیعہ ہمیشہ سے اقلیت میں رہے ہیں اور اہل تسنن کی مانند فقہی و کلامی محدودیتوں کی وجہ سے اجتماعی و سیاسی تحریکوںاور انقلابی توانائیوں کو بروئے کار لانے نیز ان تحریکوں کے سہارے تبدیلیاں پیدا کرنے کی فکر میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے نزدیک فقہی و کلامی مبانی اور مذہبی طرز تفکر نیزتاریخی تجربہ اس طرح نہیں تھے کہ جو اہل سنت کو دین سے خارج ہونے کا نام دے دیتے۔(۸۳) بلکہ بنیادی مشکل یہ تھی کہ دینی خلوص کو ظاہر کرنے کے لئے بدعت کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا لیکن ہم نے اس بات کو بھی ذکر کردیا ہے کہ ان بدعتوں سے مقابلہ کیا جاتا تھا کہ جو حاکم وقت سے مربوط نہ ہوں۔ گویا بدعتوں سے مقابلہ نے دینی فدا کاری کے اصل و بنیاد کو اپنے اندر جذب کرلیا تھا، اس لئے کہ اس کے اظہار کرنے کے تمام راستہ مسدود ہوچکے تھے، یعنی ''اپنے آپ کو دین کے عظیم اہداف کی راہ میں قربان کردینا'' اور اس طرح یہ بدعتوں سے مقابلہ کی صورت اختیار کرگیااور یہ ایسی حرکت تھی جو اب بھی باقی ہے۔(۸۴)
حاکم نظام کا طرز تفکر
ابھی تک جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ شیعوں اور سنیوں کے قرن اول و دوم سے متعلق سیاسی نظریا ت کا سلسلہ تھا اور یہ کہ کس طرح اہلسنت کی فقہ اور ان کاکلام وجود میں آیا۔ اور اس اسلوب نے اسے تحقق بخشنے میں کیا کردار پیش کیا۔ لیکن بعد والی صدیوں میں یہ بنیادیں کیونکر واضح ہوئیں اور اس میں تبدیلیاں آئیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جس پر روشنی ڈالے بغیر موجودہ صورتحال کے سلسلہ میں تحقیق نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ بالخصوص انھیں ادوار میں اہل تسنن کے اجتماعی، مذہبی اور نفسیاتی گروہ عملی طورپر وجود میں آئیاور انھیں ایام میں خلفاء بنی عباس کا دینی اور سیاسی طریقہ کار نہایت مؤثر اور یقین آور رہا ہے اگرچہ اہل سنت کے سیاسی اور فکری اصول خلفاء راشدین، بنی امیہ اور مخصوصا معاویہ کے دورمیں بنائے گئے تھے لیکن درحقیقت یہ بنی عباس تھے جنھوں نے اسے ایک خاص شکل میں پیش کیا اور اسے قطعی بنایا، انھیں دین کی ضرورت تھی اور اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے اور اپنی حکومت کو قوی و مضبوط بنانے اور اسے دوام و استمرار عطا کرنے کے لئے ممکن حدتک اس سے استفادہ بھی کرتے تھے۔(۸۵)
اسلامی علوم، فقہ، حدیث، تفسیر، کلام، رجال اور تاریخ کی تدوین و نشر اشاعت کی بازگشت بھی انھیں کے دور میں ہوتی ہے لہٰذا ان کی عمومی سیاست کی وجہ سے یہ امر طبیعی تھا کہ یہ مسئلہ ان کے مصالح و منافع کے زیراثر قرار پائے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی یہاں تک کہ اہل سنت کی فقہ اور کلام اس دور کے معاشرہ پر حاکم نظام سے وابستہ ہوگئے اور انجام یہ ہوا کہ یہ ایک موجودہ نظام کی آئیڈیالوجی نے اسے توجیہ کرنے اور اسے مشروع بنانے کی شکل اختیار کر لی۔(۸۶) اور جب عباسی خلافت کا قلع قمع ہوگیا اور اس کی بنیاد گرگئی تو اس کے بعد بھی یہ پیوند باقی رہا اور صاحبان قدرت کی خدمت کا مقام بنا۔
اس نکتہ کی مزید توضیح ضروری ہے۔ درحقیقت واقعیت یہ ہے کہ عباسی خلفاء اپنی خلافت اور قدرت کو مضبوط بنانے کے لئے سابق خلفاء سے کہیں زیادہ دین کے محتاج تھے، امویوں کے دور میں اسلامی معاشرہ عباسیوں کے دور سے کہیں زیادہ منسجم اور متحد تھا اس کے علاوہ جدید مسلمان امویوں کے دور میں نظام جدید سے مرعوب اور ایک ایسی قدرت کے سامنے تسلیم تھے جس نے ان شکست خوردہ ممالک کے سلاطین کے تختہ الٹ دیا تھا، وہ تازہ مسلمان یا تو ان گذشتہ حوادث کا نظارہ کررہے تھے یا عربوں کے رقیب یا عرب نسل لوگوں کی خادم بنے ہوئے تھے جو قدرت کی خاطر کھڑے ہوئے تھے، ان کے درک کرنے کے لئے سالہا سال درکار تھے پھر کہیں وہ مؤثر اور فعال انداز میں سیاسی اور اجتماعی بلکہ دینی اور ثقافتی مسائل میں شرکت کرسکتے تھے۔
یہاں تک کہ امویوں کی مدت تمام ہونے لگی یعنی غیر عرب مسلمانوں نے اسلامی معاشرہ میں قدم رکھ دیا جس کا انجام یہ ہوا کہ اموی شان و شوکت کی نابودی کے اسباب فراہم ہوگئے اس کے علاوہ متعد د گروہ اس میدان میں سامنے آگئے اور اس کے تمام جوانب کو مضبوظ بنادیا دوسرا مسئلہ جدید افواج کی موجودگی تھی جو سیاسی نعرہ لگا رہی تھیں بلکہ اسے دینی اور ثقافتی جنبہ بھی حاصل تھا جس کی بناپر کثرت سے مثبت نتائج کے باوجود سیاسی اور اجتماعی پراکندگی میں اضافہ ہوا۔(۸۷)
انھیں اسباب و علل کی وجہ سے امویوں کے مقابلہ میں عبا سیوں کا اقتدار زیادہ پائیدار ہوا۔(۸۸) یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ عباسی خلفاء امویوں کے مقابلہ میں نالائق یا شدت پسند تھے بلکہ حالات کے بدل جانے کی وجہ سے تھا، عباسیوں کا دور ایسا نہیں تھا کہ جس میں امویوں کی سیاست کو باقی رکھا جاتا اور اگر یہی اموی عباسیوں کے دور میں ہوتے تو اسی سیاست کو اپناتے جسے عباسیوں نے اپنایا تھا۔ اور انھیں جیسی قدرت کے مالک بھی ہوتے۔
اس مقام پر جو نکتہ قابل اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ان شرائط نے اہل سنت کی فقہ و کلام پر خصوصاً ان ایام میں اپنا اثر چھوڑ دیا اور اسے رونق مل گئی یعنی خلیفہ کا فوجی قدرت میں ضعیف ہونا اس بات کا باعث ہوا کہ اس کی قدرت کو محکم بنانے کے لئے دین کا سہارا لیا جائے، درحقیقت دین اس قدرت کا قائم مقام بن گیا جسے تلوار کے زور پر حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا۔
لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیںہے کہ اہل سنت کے تمام وہ علما جنھوں نے ایسے امور انجام دیئے ہیں خلیفہ کے حکم کے تابع تھے یا کسی اور منفعت کی خاطر انجام دیا ہو، بلکہ ان لوگوں کے درمیان ایسے علما بھی تھے جنھوں نے دین کی حفاظت اور لوگوں کی سلامتی کے لئے اسی طریقہ کا انتخاب کیا تھا، اس دور میں ان لوگوں کے لئے اس بحرانی اور کشمکش کے دور میں جو مسئلہ سب سے زیادہ اہم تھا وہ اسلام کی ایک قوی مرکزیت اور دین کی حفاظت کرنے والوں اور دیگر لوگوں کی جان ومال کی محافظت تھی، جبکہ حاکم ایسی مرکزیت کو تن تنہا ایجاد نہیں کرسکتا لہٰذا دین سے مدد لینا مسلم تھا اس لئے کہ اسی کی مدد سے ایسی مرکزیت ایجاد کی جاسکتی تھی۔
اس طرح دین ایک آئیڈیالوجی کی شکل میں آگیا۔ لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین سماج اور حکومت کو چلانے میں موجودہ نظام کے آئیڈیالوجی کی ضرورتوں کے پیش نظر جواب گو ہو بلکہ بیشتر ایک پشت پناہ کی حیثیت سے تھا جو کم و کاست اور ضعف کی تلافی کرسکے، البتہ یہ تلافی اس وقت ممکن تھی کہ جب موجودہ نظام میں ظاہری اعتبار سے سہی شرع کی رعایت کرے، یہاں اس بات کا امکان نہیں تھا کہ لوگوں کو اعتقادی اعتبار سے حاکم کے مقابلہ میں قیام کا حکم دیا جاتا اور وہ دین کا دفاع کے عنوان لے کر اُٹھ کھڑے ہوتے، جبکہ یہ نظام کلی طورپر اس کے ظواہر سے بے پرواہ تھا۔(۸۹)
جدید اعتراضات
اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا مناسب ہے کہ ہارون کے بعد عباسی خلفاء فوجی اعتبار سے کسی ضعف کے شکار نہیں تھے اہل سنت کی فقہ و کلام کی جب بازگشت سیاسی و حکومتی مسائل کی طرف ہوتی ہے تو اس کی شکل بدل جاتی تھی، یہ موضوع ہم عصر زمانے سے پہلے تک اہل سنت کی طرف سے کسی اعتراض کا باعث نہیں بنا لیکن ان آخری سالوں بالخصوص آخری دہائیوں میں بہت سارے اعتراضات کا باعث ہوا اور اب ان کے مظاہر کا سیاسی اور انقلابی گروہوں کے نوشتوں اور مصر، شمالی افریقا اور بعض عرب کے اسلامی ممالک میں موجود گروہوں میں خوا ہ اسلامی گروہ ہو یا غیر اسلامی سراغ ملتا ہے۔(۹۰)
لیکن شیعہ طرزفکر نے شروع ہی سے ایسی کوئی راہ طے نہیں کی، اس لئے کہ اس کے اصول اس طرح نہیں تھے کہ جو موجودہ حاکم نظام حتیٰ جہاں پر شیعی حکومتیں برقرار تھیں، بدل جاتے۔ جب موجودہ نظام کی مشروعیت ان اصول وقوائد کی بنیاد پر ہو جو اس کے شرائط کے مطابق تھے، ایسی صورت میں یہ آئیڈیالوجی موجودہ نظام کی آئیڈیالوجی سے تبدیل نہیں ہوسکتی اور اپنے آپ کو اسکی توجیہ میں استعمال کرے۔ اہل سنت کے دینی نظریات کے نظری اصول و مبانی کچھ اس طرح تھے کہ جو موجودہ صورتحال کو مشروع دکھانے اور اس کی توجیہ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں رکھتے تھے۔
یہ اس وجہ سے تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان نظری اور اعتقادی اصول و مبانی تاریخی اور سیاسی واقعیتوں کے تحت تاثیر واقع ہوئے ہیں بالخصوص اس جگہ جہاں صدرا سلام کی طرف بازگشت ہورہی ہو تشکیل پائی اور پروان چڑھی ہو یا بعبارت دیگر یہاں پر ایڈیولوجی اس سے ماخوذ واقعیت کی فرع تھی۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ا شارہ کیا ہے کہ اہل سنت مسئلہ امامت اور رہبری میں شیعوں کے بر خلاف کہ جو پہلے ہی مرحلہ میں شان نہیں بلکہ ذی شان کی دریافت کرتے اور اس کے بعد اس کی تفسیر کرتے ہیں، ان لوگوں کی نظر میں مخصوصا وہ مسائل جو صدراسلام میں واقع ہوئے ہیں وہ مشروعیت اور حقانیت رکھتے تھے، لہذا یہ ایک حقیقت تھی کہ وہ ان کی تعریفیں بھی انھیں کے دائرے میں کریںاور دوسرے یہ کہ وہ لوگ دین کی حفاظت حکومت اور اس کے حکومتی نظام کے سایہ میں ممکن سمجھتے تھے۔(۹۱) اور چونکہ انھوں نے اس مسئلہ کو ایک اصل کے عنوان سے قبول کیا تھا لہذا اسے توجیہ کرنے اور اس کی مشروعیت کو ثابت کرنے کی کوشش میںلگے رہتے تھے۔ ان کے افکار و اذہان ابتدا ہی سے اسی قالب میں ڈھلے اور رچے بسے تھے نیز انکی نظر میں اصحاب، تابعین اور ان کے بعد آنے والے علما کاا جماع، قرآنی نصوص اور سیرہ نبوی بھی اسی کی تائید کرتی تھی۔(۹۲) یہاں اہم یہ نہیں تھا کہ انھوں نے ایسی اصل کو قبول کرلیا ہے اور اس طرح ان کے اذہان سوچنے لگے ہیں۔ بلکہ قابل اہمیت یہ ہے کہ انھوں نے اسے اسلامی تعلیمات اور دینی دستورات کے عنوان سے ایک جزو سمجھ لیا تھا، لہٰذا وہ لوگ اس کی اس طرح تفسیر کرتے تھے۔ اور یہ مسلم ہے کہ ان کے درمیان ایسے لوگوں کی کثرت تھی جو دنیا دوستی، سوئے استفادہاور حکام سے نزدیک ہونے کے لئے اسے قبول کرتے اور اس کی ترویج کرتے تھے لیکن انھیں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے مخصوص دلائل کی بنیاد پر جس کا ذکر آئے گا قبول کرلیا تھا۔(۹۳)
بہر حال یہ مبانی شیعوں کے نزدیک ایک دوسری شکل میں تھے جو اپنے ضوابط، معیار اور اپنی اقدار کے علاوہ کسی دوسرے اعتبار سے فکر نہیںکیا اور تسلیم نہیں ہوئے یعنی دین کی حفاظت کا تنہا راستہ موجودہ صورت حال کو بدل دینے اور حاکم کی قدرت کو کمزور بنانے نیز جس طرح اہل سنت حاکم کی قدرت بڑھانے کے قائل تھے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تاریخی ادوار کے بعض دور میں اس کے برخلاف عمل کیا اور اعتقاد رکھا ہے۔ اسی وجہ سے موجودہ صورت کو اسی صورت میں قبول کرتے تھے جب وہ ان کے اصول و قواعد کی بنیاد پر ہوں یا اس کے شرائط اس طرح ہوں کہ جب دین کی حفاظت اور حراست موجودہ نظام کی عدم مخالفت پر منحصر ہو، ایسی صورت میں نہ تو اسے رسمی طورپر قبول کرتے تھے اور نہ ہی اس کے مقابل قیام کرتے تھے۔(۹۴)
ان دو اصول و مبانی کے درمیان موجود تفاوت شاید پہلی نظر میں چنداں اہمیت نہ رکھتا ہو لیکن دور جدید کے بدلتے حالات نے اپنی اہمیت کو آشکار کردیا ہے اہل سنت کی حکومت میں دور حاضر کی اسلامی تحریک کی نظری مشکلات اور ان مشکلا ت کا شیعوں میں نہ ہونا اسی تفاوت کا نتیجہ ہے جس طرح سے نئی نسل کی تنقیدوں کے مقابل اہلسنت کی محفلوں کا معنی دار سکوت اسلام کی حمایت کے پیش نظر تھا اور ان کے توسط سے کی گئی تفسیر کے کیوں گذشتہ اور حال میں فاسق و فاجر حکام کی حمایت کرتا رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔(۹۵)
اگرچہ بعض روشن فکر شیعہ حضرات وہ خواہ ایران میں ہوں یا دوسرے ممالک میں انھوں نے تقریبا ایسے ہی اعتراضات شیعہ علما پر وارد کئے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ اور اس کے اسباب و علل کچھ اور تھے لہٰذاقابل حل تھا۔ اگرچہ ایام سابق میں شیعہ علما شیعہ حکام کے درباروں میں حاضر ہوئے ہیں، جس کی ایک خاص اور بعنوان ثانوی علت تھی کہ اس زمانے میں شیعیت کے علاوہ قدرت کو مضبوط کرنے کے لئے صرف شیعی ہی مرکزیت تھی نہ اس لئے کہ وہ انھیں مشروع یا اسے واجب الاطاعہ فرض کرتے ہوں، اس لئے کہ مذہب حقہ کے دفاع اور ضروری مصلحتوں نے انھیں وقتی طور پر ایسی موقعیت کو اپنانے کے لئے مجبور کردیا تھا۔ اس کے علاوہ دورحاضر میں ایسے کوئی شرائط مہیا نہیں تھے لہذا دین کی حمایت میں حکام کے مقابلہ پر مجبور ہوگئے لہٰذاان کے خلاف قیام کیا، خواہ وہ حکام شیعہ ہی کیوں نہ ہوں انھوں نے دین کی مصلحت کے مطابق وہی کیا جو کرنا چاہئے تھا۔
شیعہ کا موقف
بہر حال طول تاریخ میںبادشاہوں کے دربار میں شیعہ اور سنی علما کا حضور مکمل طورپر علل و اسباب کی تبعیت میں متفاوت ہے۔ ایک شیعہ عالم کسی بھی حال میں ایسے حاکم اور اس کے حاکمانہ نظام کو قبول نہیں کرسکتا تھا کہ جس نے ناجائز طریقہ سے قدرت حاصل کی ہو اور دین و شرع کے مخالف طرز عمل ہو۔ اور اگر کبھی اس کی حمایت اور تائید کیلئے مجبور ہوجاتا تھا تو وہ بھی ایک خاص دلیل اور ایک امر ثانوی کی وجہ سے تھا۔(۹۶) لیکن ایک سنی عالم دین کے لئے ایسی کوئی مشکل درپیش نہیں تھی، اس کی نظر میں حاکم چونکہ ایک حاکم ہے اور قدرت و حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا مشروع اور اس کی اطاعت واجب ہے یا کم از کم اس کی نظر میں اس کے خلاف قیام کرنا یا اس کی مخالفت کرنا حرام ہے اور اگر ادوار گذشتہ میں بعض علما نے حاکم کو ایک حاکم ہونے کی وجہ سے اس کے واجب الاطاعت ہونے میں شک و تردید کا اظہار کیا ہے تو اسی کے بالمقابل ان کے نزدیک یہ بھی مسلم ہے کہ ایک حاکم کے مقابلہ میں قیام کرنا حرام قرار دیا گیا۔(۹۷)
البتہ یہ بھی مسلم ہے کہ اخلاقی عوامل بھی اہل سنت کے علما اور متقی و پرہیزگار فقہا کے لئے بادشاہ کے تقرب میں مانع ہوئے ہیں، چونکہ حکومت و سلطنت عموما دنیا پرستی، عیش ونوش، ظلم و تعدی اور آخرت و قیامت سے غفلت کے ہمراہ ہوتی ہے لہٰذا اس سے دوری اختیار کی۔ چنانچہ وہ لوگ بھی جو اس طرح کی زندگی گذاررہے تھے وہ بھی ان سے دوری اختیار کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ یہ روش کسی اعتقاد کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی پہلو ہے۔ درحقیقت ان سے دوری اختیار کرنا دنیا اور دنیا پرستی سے پرہیز علما اہلسنت کے نزدیک ممدوح اور مطلوب تھا۔ ان لوگوں نے اس مسئلہ میں اسی موضوع کے تحت احادیث یعنی سلاطین سے دوری کو اپنے لئے نصب العین قرار دیا تھا۔(۹۸)
مذکورہ بالا نکات کے مدنظر اب اس مسئلہ کے تحت بحث کریں گے کہ کیوں بعض علما اہل تشیع اپنے دور بلکہ آئندہ ادوار میں ممتاز موقعیت کے مالک ہوتے ہوئے بھی سلاطین کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اور عملی طورپر صفویوں کے دور میں اکثر علما ایسے ہی تھے۔
اس مسئلہ کی دلیل اس دور میں سیاسی حالات اور نیز عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان دائمی کشمکش ہے۔ عثمانیوں یعنی صفویوں کے دشمن شیعہ تھے۔ لہٰذا یہ ان کے فائدہ میں تھا کہ تشیع کو اسلام سے خارج اور اسلام سے ناآشنا اور اس کے مخالف ہونے کے عنوان سے متعارف کرائیں، وہ لوگ اس کے ذریعہ عوام کی حمایتوں اور انھیں ان کے خلاف بھڑکانے کے مالک ہوئے۔ انھیںدین کا دفاع کرنے اور اخروی درجات سے بہر ہ مند ہونے کے لئے میدان جنگ میں کھینچا اور انھوں نے بھی ایسا ہی کیا۔(۹۹) لیکن اہم تو یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے دشمنوںکے خلاف ابھارنا تنہا صفویوں کے خلاف نہیں تھا اور ہو بھی نہیں سکتا تھا بلکہ ان کی مملکت میں رہنے والے شیعوں کو بھی شامل تھااور یہی وہ علت تھی کہ ان کی سلطنت میں رہنے والے شیعہ ہمیشہ قتل وغارت گری ذہنی دباؤ اور اذیت کا شکار رہے بلکہ بعض اوقات یہ قتل عام اس قدر وسیع تھا کہ بعض مناطق سے شیعوں کا نام و نشان تک مٹ گیا بطور مثال جب سلطان سلیم اول نے اپنے باپ سلطان بایزید ثانی کی بادشاہت چھین لی اور اس کے بھائیوں کو قتل کرکے تخت سلطنت پر بیٹھ گیا تو اس نے سب سے پہلے چالیس ہزار شیعوں کے قتل عام کا حکم جاری کیا۔(۱۰۰)
درحقیقت ان دونوں کے درمیان سیاسی رقابت دینی رقابت اور دشمنی کا موجب ہوگئی۔ اور واقعیت تو یہ ہے کہ اگر فرض کرلیا جائے کہ ان دونوں نے سیاسی رقابت بڑھانے میں ایک جیسا کردار اد اکیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کے نام پر جنگ و جدال کی آگ بھڑکانے میں صفویوں سے کہیں زیادہ عثمانی پیش پیش رہے ہیں اس لئے کہ صفوی شیعہ تھیاور شیعوں نے کبھی بھی اہل سنت کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جس کی وجہ سے ان کے مقابلہ میں کبھی قیام بھی نہیں کیا۔(۱۰۱)
لیکن اس کے برخلاف متعدد دلائل کی وجہ سے صحیح ہے کہ جس کی یہاں پر بیان کرنے کی گنجائش نہیںہے۔ اہل سنت اکثر و بیشتر ہوا ہے کہ خود فروش، دنیا پرستاور مزدور علما یا ظالم و سفاک حاکم کے بھڑکانے پر شیعوں کے خلاف اقدام کیا ہے، یہاں بھی مسئلہ یہی تھا عثمانی سلاطین اسی ذہنیت اور سوابق کے پیش نظر بآسانی ان کی حکومت میں رہنے والے شیعوں کے خلاف انھیں ابھار دیا لیکن اس کے نتیجہ میں سامنے آنے والے نقصانات ان کی توقع سے کہیں زیادہ اور طولانی تھے جس کی تمام محرکین اور سلطان کو امید تھی۔(۱۰۲)
شیعہ علما اور صفوی سلاطین
ایسے حالات میں فطری طورپر علما تشیع مجبور تھے کہ وہ تشیع کے واحد مرکز کے دفاع میں سلطان وقت کی خدمت میں رہیں۔(۱۰۳) تا کہ اس کے ذریعہ ایسی قدرت کو جو مسلسل گوناگون رقیبوں اور مختلف دباؤ کا شکار تھی کا تحفظ کریں اور اس کی حفاظت اور مرکزیت اور شان و چوکت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک مانع بنیں وہ بھی عثمان کی حکومت میں ہونے والے بے رحمانہ قتل عام کے مقابل کیوں کہ ان کی طاقت روکنے والا ایک عامل تھا عثمانی شیعوں کی ہتک حرمت اور ان کے قتل و غارت ہونے کے لئے ان بحرانی ایام میں شیعوں کی سرنوشت خواہ ایران کے اندر ہو یا باہر اس درجہ صفویوں کی قدرت اور قوت سے وابستہ ہوئی کہ ان کے تحفظ کے لئے ان کی تقویت کرنے کے کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اس بحث کو اس دور کے تاریخی حالات کی عکاسی کرنے والے نمونوں پر ختم کریں گے۔
سلطان مراد چہارم (۱۰۳۲۔ ۱۰۴۹ ق) کہ جو اس وقت صفویوں کے قبضہ میں تھا اس نے خواہش کی اور اس نے اپنے ہدف کو پانے کے لئے ایران سے جنگ کے لئے آمادہ ہوگیا، لیکن اسے یہ نکتہ خوب معلوم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے صفویوں کو شکست نہیں دے سکتا لہذا اس نے قبائلی اور مذہبی فتنہ کو ہوا دینے کی ٹھان لی اور علما سے شیعوں کے خلاف جنگ کا فتوا طلب کیا لیکن علما اہل تسنن نے ایسا فتوا دینے سے انکار کردیا لیکن ایک نوح آفندی مقامی جوان اس کے لئے، تیار ہوگیا اور اس نے ویسا ہی فتوا دیا جیسا سلطان مراد نے چاہاتھا۔ ''جو بھی ایک شیعہ کو قتل کرے اس پر جنت واجب ہے۔
اس فتوا کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ: خدا آپ کواس گروہ کے مقابل سعادتمند بنائے جو کافر، باغی، فاجر، جنھوں نے ہر قسم کا عناد، فسق، زندقہ، الحاداور کفر و عصیان کو اپنے اندر جمع کرلیا ہے اور جو بھی ان کے کافر، ملحد ہونے، وجوب قتالاور انھیں قتل کرنے جواز میں تامل کرے وہ بھی انھیں کی طرح کافر ہوگا۔ اور پھر اس طرح کہتا ہے: انھیں قتل کرنے کا جواز ان کا باغی اور کافر ہونا ہے، وہ اس لئے باغی ہیں کہ وہ خلیفہ، خلدہ اللہ تعالی ملکہ، کی اطاعت سے قیامت تک کے لئے خارج ہوگئے ہیں اور خدا فرماتا ہے: سرکشوں اور اطاعت نہ کرنے والوں سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ حکم خدا کے سامنے تسلیم نہ ہوجائیں اور یہاں پر امر وجوب کے لئے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے اس کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے لہٰذا سزاوار ہے کہ جب خلیفہ ایسے باغی اور طاغی گروہ سے جنگ کرنے کی دعوت دے جسے زبان رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم سے کافر اور ملعون کہا گیا ہے اس کی آواز پر لبیک کہو بلکہ ان پر واجب ہے کہ اس کی نصرت کریں اور اس کے ہمراہ ان سے جنگ کرنے کے لئے قیام کریں اور آخر میں اس طرح اضافہ کرتا ہے: ''لہٰذا ایسے کافر اشرار کا قتل کرنا واجب ہے چاہے توبہ کریں یا نہ کریں نیز جزیہ لے کر یا موقت امان یا دائم امان دے ان کے قتل سے بازآنا جائز نہیں ہے نیز ان کی عورتوں کو کنیز بنانا جائز ہے کیونکہ مرتد کی بیوی کو جو دارالحرب میں ہیں جہاں کہیں بھی ہوں امام یا برحق خلیفہ کی حکومت سے باہر ہے تو انھیں کنیزی میں لینا جائز ہے، اس لئے کہ دارالحرب کے علاوہ جہاں بھی وہ ہیں وہ بھی دارالحرب کی مانند ہے۔ اسی طرح ان کے بچوں کو غلامی میں لینا ان کی ماؤں کے ہمراہ جائز ہے۔''(۱۰۴)
یہی فتوا ایک ایسی جنگ کا باعث ہوا اور سات ماہ تک طولانی جنگ ہوتی رہی اور دونوں طرف سے ہزاروں کے قتل عام کا موجب بنا یہاں تک کہ یہ جنگ ۱۷رجب ۱۰۴۸ سے ۳محرم ۱۰۴۹تک جاری رہنے کے بعد ایران اور عثمانی کے درمیان مقام شہر قصر شیرین پر معاہدۂ صلح کے ذریعہ تمام ہوئی۔
اس جنگ کے تمام ہونے کے بعد اسی فتوا کی بنیاد پر عثمانی حکومت میں رہنے والے شیعوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی، جس میں جہاں تک چاہا قتل عام کیا، ان میں بدترین اور ہولناک قتل عام شہر حلب کے شیعوں کا تھا اس لئے کہ یہ شہر حمدانیوں کے دور سے شیعہ نشین رہا ہے، یہ قتل عام اس قدر دردناک اور وسیع پیمانہ پر تھا کہ ان کی کثیر تعداد قتل کردی گئی اور جو لوگ آس پاس کے گاؤں میں فرار کرگئے صرف انھیں کی جانیں محفوظ رہ گئیں، اس جنگ میں تنہا شہر حلب میں چالیس ہزار شیعہ شہید ہوئے کہ جن میں ہزاروں کی تعداد میں سادات تھے۔ نجف کے عالم بزرگ سید شرف الدین علی ابن حجة اللہ شولستانی نے اس قتل عام کے خلاف ایرا ن میں فتوا صادر کیا تاکہ اس ہولناک قتل عام سے روکا جاسکے۔(۱۰۵)
شیعوں کی گوشہ نشینی اور اس کے نتائج
اس مقام پر اس نکتہ کی یاد دہانی ضروری ہے کہ اہل تسنن کے مقابلہ میں شیعہ ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ اہل تسنن کے سماج میں ایک اقلیت کی صورت میں انھیں کے درمیان اپنا گذر اوقات کرتے تھے حتی وہ مقامات کہ جہاں وہ اکثریت میں تھے اور قدرت بھی انھیں کے ہاتھ میں تھی، اپنے ہمسایوں کے درمیان ایک جزیرہ کی مانند زندگی گذاری ہے۔ شیعوں کی گوشہ نشینی مخصوصا ایران میں جب شیعہ سلاطین نے قدرت سنبھالی، تو ایران سے خارج دنیائے اسلام کے مذہبی سماج سے قطع رابطہ کا باعث بنی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کا داخلی سماج پہلے سے زیادہ دیگر سماجوں سے دور ہوتا گیا اور جب اسلامی ممالک مخصوصا شیعی حکومتوں کی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی تو ایرانی معاشرہ اپنی اصالت کے تحفظ کی خاطر اپنے ہی دائرے میں محدود ہوگیا۔(۱۰۶)
اگرچہ یہی صورتحال اہل تسنن کے درمیان بھی مشاہدہ کی جاسکتی ہے لیکن اہل تسنن کی گوشہ نشینی شدت اور عمق کے لحاظ سے شیعوں کے برابر کبھی بھی نہ رہی ہیاور اس تفاوت کے نتیجہ میں ظاہر ہونے والے آثار ان دو گروہوں کی فرہنگی، سیاسیاور اسلامی افکار، مخصوصا علما اور دینی مفکرین جو رسالت کے دفاع کی ذمہ داری لئے ہوئے تھے اس خاص گروہ کے درمیان بخوبی قابل دید ہے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ شیعوں کے درمیان اسلامی تفکراہل سنت سے کہیں زیادہ محکم، اصیل اور پائدار ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنی مفکرین کا وسیع پیمانہ پر تمدن جدید سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہے کیونکہ ان کے درمیان ہم عصر مفکرین کی شیعوں کی نسبت تعداد زیادہ ہے لہٰذا ان کا طرزتفکر بھی زیادہ عینی غیر انتزاعی ہے سنیوں کے درمیان اصلاح طلبی اور تجدد خواہی جیسے تفکرات کی تاریخ کا طولانی ہونا احتمالا انھیں اسباب کا نتیجہ ہے، جب یہ مسلم ہوجائے کہ اپنی حقیقت و اصالت کی برقراری ماضی پر افسوس کرنے، اجنبی اور بیگانوں کو بدون چون و چرا دور کرنے کے ہم پلہ ہے تو اس صورت میں اصلاح اور تجدد کا کوئی امکان باقی نہیں رہ سکتا، ایسے تفکرات دین اور دینی اصول و مبانی سے آنے کے بجائے زیادہ تر خلوت طلب شیعوں کے تاریخی تجربہ اور شیعہ مذہبی سماج سے پیدا ہوئے ہیں۔
البتہ شیعوں کی کنارہ کشی اور دور رہنے کے اسباب کم از کم ایران میں متعدد ہیں۔ شیعی گروہوں اور جماعتوں کا دیگر مذہبی تشکیلات سے ارتباط نہ رکھنا، نیز موجودہ حاکم سیاسی قدرت نے اس میں ایک دوسرے عنوان سے شدت پیدا کردی اور اس گوشہ نشینی پر مجبور کیا۔ ان دونوں کے آپس میں ارتباط نہ رکھنے نے جدید تاریخ میں اجنبیوں اور جدید فرہنگ کے اثر و رسوخ کی زیادتی انھیں کے مقابل تھی کیونکہ استعماری سابقہ نہیں رکھتا تھا اور جدید فرہنگ اور تفکر کہ جو عملی طورپر اسی حاکم قدرت اور ان کے پٹھوں اور بہی خواہوں کے ذریعہ سماج میں داخل ہوگئی لہٰذا ان دونوں کا مقابلہ مذہبی سما ج اور جدید کلچر و تہذیب کے عنوان سے انجام پایا لہٰذا اس تہذیب و ثقافت نے بھی خود کو مذہبیوں کے قالب میں استعمار، فائدہ طلبی اور فساد اور بے دینی سوا کچھ ظاہر نہیں کیا لہٰذا انھوں نے اس سے کلی طورپر احتراز ہی میںعافیت سمجھی لہٰذا اپنے آپ کو سمیٹ کر شور و غل سے دوراپنے معاشرہ کو سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کریںقوی احتمال کی بنیاد پر ایسے حالات اور شرائط میں کوئی قدم اٹھانا نہ مناسب تھا اور نہ ہی مفید۔(۱۰۷)
لیکن سنیوں کے مذہبی سماج کا جدید فرہنگ سے تعلق ایسا نہیں تھا چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اس سماج سے گہرا لگاؤ اور ان پر حاکم سیاسی قدرت نے کم و بیش انھیں افکار اور تغیرات کے روبرو کردیا تھا تاکہ جس سے حاکم نظام دوچار تھا، دوسرے یہ کہ ان کا جدید فرہنگ سے ڈائریکٹ رابطہ تھا۔ سنیوں کا تمام معاشرہ، ہند سے لے کر مشرق وسطی اور شمالی افریقا تک استعمار گروں کے زیراثر تھا، وہ لوگ تمدن جدید کی تمام خصوصیت کو اس کے تمام ابعاد و جوانب کے ہمراہ اپنی اولاد کی صورت میں مشاہدہ کرتے تھے۔ لیکن ایران میں اس کے نمونے عمومی طورپر بلکہ کلی طورپر ایک کم ظرف اور خود باختہ انسان تھے جو نہ انھیں پہچانتے تھے اور نہ ہی ایسی شناخت کی فکر میں تھے۔ ان کا اس سے تمسک کی اصلی غرض اخلاقی، اجتماعیاور دینی قیود سے فرار کرنا تھا یعنی اسے اپنے لئے ایک امتیاز اور تشخص کا ذریعہ اور لوگوں پر برتری جتانے کا وسیلہ بنالیا تھا۔(۱۰۸)
خلاصہ کلام یہ ہے کہ تاریخ معاصر میںسنی اور شیعہ سماج کادور بالکل مختلف رہا ہے، ان دونوں نے تمدن جدید اور جدید فکر و فرہنگ کو دو متفاوت صورت میں مشاہدہ کیا تھا اور ان دونوں نے فرہنگ و تمدن نیز نئے افکار کا دو طرح سے تجربہ کیا تھا لہٰذا اس فرہنگ نے بھی ان پر دو الگ عنوان سے حکومت کی اور اپنے زیراثر رکھا درحقیقت یہ دو تجربوں کے وارث اور دو تغیرات کے فرزند ہیں، ان دونوں کی دینی حالت مخصوصا موجودہ صورتحال ان کی اسلامی تحریک کے سلسلہ میں تحقیق آخری نکتہ کو مدنظر رکھے بغیر نا ممکن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب تک جو کچھ اہل سنت اور اہل تشیع کے سیاسی مبانی کے سلسلہ میں وضاحت دی گئی ہے ان میں اسلامی تحریکوں کا کیا حال تھا، ان میں کیا فرق تھا اور ان کے اسباب کیا تھے۔
دباؤ اور نئی ضرورتیں
واقعیت تو یہ ہے کہ شیعہ حکومت میں اسلامی تحریک کسی خاص نظریات مشکل سے روبرو نہیں تھی اعتقادی اصول، فقہی قواعد، تاریخی تجربہ سے حاصل شدہاور نفسیاتی اور اجتماعی ڈھانچے اس طرح نہیں تھے کہ جو تاریخ جدید کے سیاسی اور انقلابی تقاضوں کے تحت اسلامی جواب حاصل کرنے کے لئے سیاسی اور انقلابی اقدامات پر مبنی ہوں شیعوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ علماے دین کی رہبری اور اپنے دینی تفکرات کے سایہ میں ظالم اور وابستہ حکمرانوں کے مقابلہ میں کھڑے ہوجائیںاور اس کی نابودی تک اس کا مقابلہ کریں، یہ صورت حال ذخائر کے مالک ممالک کی نفسیاتی، فرہنگی، اخلاقی آثار اور آخری دہائیوں میں اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی تحولات و تغیرات سے موافق ہونے اور اس کے مواہب سے مالامال ہونے کی وجہ سے تھی۔ یہاں تنہا مسئلہ یہ نہ تھا کہ دین اور اس کے اقدار کی حفاظت کی خاطر ان حکام سے مقابلہ کیا جائے جو انھیں کوئی اہمیت نہیں دیتے یا اس کے مخالف ہیں۔ جیساکہ ہم پچاس یا سوسال پہلے تک شاہد رہے ہیں، آخری دہائیوں میں اسلامی تحریکیں تنہا دوآخری دہائیوں کے علاوہ صرف اس وجہ سے وجود میں آئی تھیں کہ حکومت وقت جو دینی مصلحتوں کو مدنظر رکھے بغیر اقدامات انجام دیتی اور من مانی کرتی تھی کا مقابلہ کیا جاسکے، بلکہ اہم تو یہ تھا کہ ایسے مبارزہ اپنے آخری ہدف پر نظر کئے بغیر موضوع رکھتے تھے۔ یہاںیہ اہم نہ تھا کہ دین سے دفاع اور فاسد نظام کو صحیح بنانے کے لئے ان کا مقابلہ کرنا چاہئے، بلکہ مہم یہ تھا کہ مختلف تحولات و تغیرات اور سماج میں مختلف پارٹیوں کا سیاسی اور انقلابی اقدامات انجام دینا جوانوں اور مسلمانوں کے ذہن میں ایک ایسی فضا بنا رہا ہے کہ جس کے پیش نظر اسلامی اصول کے مطابق ایک روش کا انقلابی اور جہادی ہونے کے ساتھ ساتھ وجود میں آنا ضروری تھا۔ اس لئے کہ اس راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا پیاسی روحیں، دین خواہ، عدالت پسند جوان جو اپنے اندر ایک مبارزہ طلب اور عدالت خواہ نظریہ سے بُھن رہے تھے سیراب ہوجائیں نیز وہ لوگ اس درجہ پیاسے اور پریشان تھے کہ اگر خدا نخواستہ اسلام میں اپنا جواب نہیں پاتے تو کسی دوسرے مکتب کی طرف چلے جاتے تھے لہٰذا دین اپنے فرزندوں کے تحفظ کے لئے مجبور تھا کہ انقلابی اور مبارزانہ نظریہ پیش کرے۔(۱۰۹)
جیسا کہ ہم نے اس بات کو بیان کردیاہے کہ شیعی تفکر اور اسکے تاریخی تجربہ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے اندر کسی تغیر و اصلاح کے بغیر اس احتیاج کا جوا ب دے یا اس احتیاج کو پورا کرنے کے لئے وہ خلاف اجماع کوئی عمل انجام دے یا اپنی ظرفیت سے بڑھ کر توجیہوں اور وسیلوں کا سہارا لے، مخصوصا واقعہ عاشورا لوگوں کے خون، احساسات اور عواطف سے خمیر ہوچکا تھا۔ جس کا ہر لحظہ کار آمد اور ایک ایسے پیغام کا حامل ہے کہ جو ظالم اور فاسد حاکم خواہ کتنا بھی قوی ہو اس کا مقابلہ کرنا چاہئے اور اسے نابود کرنے کے لئے آخری سانسوں تک ایستادگی اور مقابلہ کرنا چاہئے۔ یہ واقعہ نسل جدید کی راہنمائی کے لئے ایک اہم منبع ہے کہ جس کے ذریعہ اس مشکل کو حل کیا جاسکتا ہے جدید نسل دوچار ہے۔(۱۱۰)
لیکن اہل سنت کے درمیان ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ ان کے سامنے ایک طرف عصر جدید کا دباؤ اور جوانوں کی شیفتہ اور پیاسی روح تھی کہ جو اپنے سیاسی، دینیاور انقلابی جواب حاصل ہی کرکے تھی تو دوسری طرف ان کی فقہ اور کلام نیز تاریخ کے تجربہ عملی طورپر ایسی ضرورتوں کو پورا کرنے سے معذور و مجبور تھے کیونکہ مشکل بھی نظری اور خیالی اعتبار سے تھی اور عملی، تاریخی اور اجتماعی اعتبار سے بھی، سنی تفکر اپنے زیادہ سے زیادہ انقلابی شکل میں ہونے کے باوجود کبھی بھی زبانی امر بالمعروف اور نہی از منکر کے دائرے سے وہ بھی اسلامی قدرتوں کے زیر نظر کبھی آگے نہیں بڑھی البتہ وہاں پر جہاں بادشاہ مسلمان ہو نیز طول تاریخ میں اہل سنت کی آزاد و اور جوانمرد شخصیتوں میں ایسے لوگ تھے جنھوں نے اپنے زمانہ کے ظالم حکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیااور مخلوق کی رضایت کی خاطر خالق کے غضب کو نہیں خریدا ان کی دینا کی خاطر اپنا ایمان نہیں بیچا، حاکم کی شان و شوکت اور اس کا لالچ دلانا نیز دھمکی دینا آنکھوں میں نہیں سماسکا بلکہ پوری صلابت اور اقتدار کے ساتھ ان کے توقعات اور آرزؤں کے مقابلہ میں ڈٹے رہے، سلطان کی مرضی کے خلاف حق بات کہی اور تمام مشکلات اور سختیوں کو اپنی جان کے بدلہ خرید لیا۔(۱۱۱)
اہل سنت کے عظیم اور بزرگ انقلابی یہی لوگ ہیں۔ ان میں یہ اخلاقی قدرت اور روحی توانائی پائی جارہی تھی کہ وہ دنیا پرستوں اور دنیا کے مقابلہ میں اپنے ثبات قدم کا مظاہر کریں اور یہ امر دوران جدید کی ضرورتوں سے شدیداً متفاوت تھی، موجودہ دور میں یہ عوام امام حسین ـ، زید ابن علیاور دیگر امر بالعروف اور نہی از منکر کرنے والوں اور شیعی شخصیتوں کی تلاش میں ہے جو دین و ایمان کی خاطر ظالم حکام کا مقابلہ کرے اور لوگوں کو ان کے عالی اہداف کی جانب دعوت دے، نہ ابن حنبل، سعید ابن مسیب اور دیگر محدثین جیسے لوگ جنھوں نے ایام المحنہ میں بڑی سختیاں کاٹیں لیکن پھر بھی اپنے عقیدہ پر باقی رہے۔(۱۱۲)
حکام کے مقابلہ میں ان لوگوں کا انکار قلبی اور قولی تھا نہ فعلی۔ البتہ انکار قولی بھی ان مقامات پر بہت کم تھا کہ جہاں اس سے مقصود صرف حاکم پر تنقید ہو۔ اس لئے کہ وہ انکار فعلی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لئے ان کا اقدام کرنا بھی دکھاوے کے لئے نہیں تھا بلکہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق یہ کام کرتے تھے۔ لہذا اس میں زمانہ کے تحولات و تغیرات کا کوئی دخل نہیں تھا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، سنیوں کے سیاسی تفکر نے اس بات کو ایک اصل کے عنوان سے قبول کرلیا تھا کہ مسلمان حاکم کے سامنے قیام اور مسلحانہ مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ ظالم جابر اور جائر و فاسق ہی کیوں نہ ہو۔(۱۱۳) لیکن دور حاضر کی ضرورت کے علاوہ کوئی دوسری چیز پوری نہ کرسکی۔
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکام کہ جن سے مقابلہ کے لئے سنی جوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں گذشتہ ان کے جیسے حکام سے ظلم و ستم اور فسق و فجور میں بڑھے ہوئے ہیںاور ان اسباب کی وجہ سے وہ ایسی آرزؤں کو اپنے دل میں لئے ہوئے ہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ کلی طورپر اس دور کے حالات گذشتہ ادوار کے حالات سے کہیں زیادہ متفاوت اور جدا ہیں۔ گذشتہ ادوار میں ظالم و فاسق حکام کے مقابلہ میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ سماج میں دین اور عدالت کو برقرار کرسکیں، عدل و دین کو قائم کرنے کی ضرورت کا اقتضاء یہی تھا۔ اور یہ امر اس بات کا مستلزم تھا کہ ان کے مقابلہ میں کھڑے ہوںاور اس راستہ کے علاوہ ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس لئے کہ سماج میں پیدا ہونے والے فسادات اور انحرفات حاکم کی وجہ سے تھے اور اجتماعی، سیاسی، فکری اور فرہنگی احتیاج کو پورا کرنے کے لئے ایک انقلابی اور کبھی مسلحانہ تفکر کو پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تاکہ اس کی روشنی میں جوانوں کو دین سے منحرف ہونے پر روکا جاسکے۔(۱۱۴)
لیکن ہمارے دور میں یہ مسئلہ ایک دوسری شکل اختیار کرچکا تھا، اس دور کے حاکم یا یک بازیچہ یا مطیع یا کم از کم بڑی حکومتوں سے متحد تھے۔ یہ حاکم دراصل نظام کو نہیں چلاتا تھا، بلکہ وہ ان دستورات کو جاری کرتا تھا کہ جو دوسروں کی طرف سے اس کے لئے صادر ہوتے تھے، لیکن گزشتہ ادوار میں حاکم ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا، جو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق حکم صادر کرتا تھا اور اس دور میں حقیقی قدرت کہیں اور تھی اور اس دور کے حاکم صرف اور صرف ایک مجری کی حیثیت رکھتے تھے اور بس۔(۱۱۵)
اس کے علاوہ اس دور میں سیاسی، اجتماعی اور فرہنگی و نفسیاتی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ اس دور کے ناگفتہ بہ حالات و شرائط کے مقابل ہر مکتب ایک راہ حل پیش کرتا تھا اور ان میں سے ہر ایک اسے حل کرنے کی صلاحیت کا دعویدار تھا۔ایسے حالات میں اسلام بھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا، یہ راہ حل عموما موجودہ حالت کے مطابق ہونا چاہئے تھا جس میں جوانوں کی مبارزہ طلبی اور انقلاب پسندی جیسی خصوصیات پائی جاتی ہوں، ایسی خصوصیات کہ جو تضاد و کشکمکش سے بھر پور صنعتی شہری معاشرہ ہی میں اکٹھا ہو سکتی تھیں اور ایک واقعی نیاز کی صورت اختیار کرسکتی تھیں۔(۱۱۶)
اگر ایسے دور میں اسلام اپنا راہ حل پیش نہ کرتا تو یہ مسلم تھا کہ یہ بھی اپنا اعتبار کھو بیٹھتا۔ اور کوئی بھی دین اسی وقت اپنے اثر و رسوخ کو محفوظ رکھ سکتا ہے کہ جب وہ واقعیتوں اور ضرورتوں کے مقابلہ میں لاپرواہ نہ ہو، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دین کی شائستہ موقعیت فعال اور خلاق تبادل کی مرہوں منت تھی، جب تمام مکاتب و ادیان بطور صحیح یا ناصحیح موجودہ حالت کی اصلاح کے مدعی یا اس کی جگہ ایک مطلوب اور صحیح صورت کو قائم مقام بنانے کے لئے پیش قدم نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جوانوں کا بے شمار طبقہ ان کی طرف جذب ہوا جارہا تھا، ایسی صورت میں اسلام خاموش رہ کر تماشائی بننا نہیں چاہتا تھا۔ اس لئے کہ نہ یہ صورت ممکن تھی اور نہ ہی متدین و دیندار حضرات، علما، دانشور، روشن فکر اور طالب علم کی دینی غیرت اور عہد ایسی اجازت نہیں دیتا تھا۔(۱۱۷)
ان دو عاملوں کے علاوہ ایک تیسرا الزام آور عامل بھی موجود تھا اور یہ ایک عامل داخلی تھا، ان آخری دہائیوں میں اکثر مظاہر حیات تغیرات کے جال میں گرفتار ہوچکے تھے اور ایسی صورت میں یہ امر طبیعی تھا کہ اپنی شرائط کے مطابق روح و فکر اور شخصیت کی پرورش کرے۔ دوران معاصر کے جوان اپنے آباء اجداد کے ماحول اور فضا سے بالکل الگ ماحول میں پلے بڑھے تھے، اس کی روح و شخصیت، ذہنی اندیشہ، احساس، احتیاج، آرزو و ارماناور فہم و اخذ نتیجہ دوران معاصر کے سریع التاثیر اجتماعی و اقتصادی اور فکری و سیاسی تحولات و تغیرات کی ضد میں تھے یہاں تک کہ فہم دینی بھی اپنی ممکن نوع التزام میں گذشتہ افراد کی فہم دینی سے متفاوت تھی، بلکہ وہ ایک دوسرے زمانے، تجربہ اور ضرورتوں کے فرزند تھے۔(۱۱۸)
سیاسی،معاشرتی اور تاریخی اسباب کی بنیاد ہی شخصیتی، روحی اور اصلی جلوہ گاہ، دینی اور سیاسی مباحث تھے۔ دینی فہم وشعورکے تحت نسل جدید اور اس سے پہلے والی نسلوں کے درمیان فرق مباحث دینی کے سمجھنے میں ہے۔ اور چونکہ صورت حال ایسی تھی، اس سلسلہ میں اہل سنت کے تفکرات اپنے تمام ممکنہ ترقی اور جدت تفکر اس کا تعارف نہیں کراسکی، ان کے درسی طرز تفکر جس کے شرائط دیگر زمانہ میں تمام ہوچکے تھے لہٰذا اس کے بعد کارآمد نہیں رہے مخصوصا ًیہ بحث کہ جو اپنے ایک خاص مضر اثرات کی حامل تھی، اہل سنت کی سیاسی فکر کا ایک عظیم حصہ اجماع پر قائم ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ نسل جدید کے اعتراضات، اشکالات اور سوالات اور تنقیدوں کی تاب تحمل نہیں رکھتی اور نہیں لاسکتی تو عملی طورپر بہت سارے فرضی اصول اور مبانی بلکہ من گھڑت کا خانہ خراب کردیا۔(۱۱۹)
بہر حال ان عوامل و اسباب اپنے ساتھ دیگر نئے الزامات ضرورتیں پیش کیں۔ بنیادی مشکل یہ تھی کہ یہ ضرورتیں گذشتہ کی میراث اور ان کے افکار سے بالکل ٹکراؤ رکھتی تھیں ایک عظیم اور وسیع فقہی اور کلامی نیز تاریخی اور حدیثی مجموعہ کہ اگر برفرض پورے طورپر حاکم یا حاکم نظام چارہ جوئی نہیں کررہا تھا تو کم از کم اسے کمزور کیا جارہا تھا وہ چاہتے تھے کہ اس کا کوئی جواب دریافت کریں انھوں نے پہلی بار اپنی پوری تاریخ میں حاکم کے سامنے حجیت بلکہ دینی الزام کے ساتھ بیٹھیں اور گذشتہ تاریخ اور فقہا کے فتووں کے نمونے تلاش کریں تاکہ اس کی مدد سے ان کے قیام کی توجیہ کریں اور اُسے مشروعیت بخشیں اور ایسا ناممکن تھا کیونکہ واقعی ضرورت بھی ناقابل انکار تھی اور اعتقادی بنیادیں اور تاریخی تجربہ ایک دوسرے سے تضاد رکھتے تھے۔ ایسی ہی بھول بھلیاں نے اسے تھیوری اور راہ حل پر مجبور کیا کہ جس کا کوئی سابقہ بھی نہیں تھا اور اسی حدتک اعتقادی کلیت اور اہل سنت کے متفق علیہ اور اجماع سے دور بھی تھا۔سید قطب کی معالم فی الطریق نام کتاب میں ذکر شدہ تھیوریوں سے لے کر غیر معتدل گروہ کی افکار تک التکفیر و الھجرة مصطفی شکری کی کتاب نے عبدالسلام کی الفریضہ الغائبہ سے فرج حاصل کی الامارة و الطاعة و البیعة نامی تھیں کی کتاب تک سلسلہ جاری رہا ہے۔
معلوم نہیں ہے کہ آئندہ کن نظریات سے وابستہ ہونا ہے، کیوں یہ تمام نظریات کسی خاص اصول کے پابند نہیں ہیں تاکہ اسے دیکھتے ہوئے آئندہ حالات کی پیشین گوئی کی جاسکے۔ جو نکتہ اس مشکل کا راہ حل بن سکتا ہے وہ موجودہ شرائط اور جہادی راہ حل حاصل کرنے کا مبارزہ طلبوں کی جانب سے دباؤ ہے نیز ان لوگوں کی ذہنیت ہے جو اپنی مشکلات کے سلسلہ میںفکر کرتے ہیں۔ ایک روز سماج کو جاہل معاشرہ سے مشابہ قرار دیتے ہوئے اس سے مقابلہ کو واجب سمجھتے ہیں اور دوسرے روز آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کی سوانح حیات میں سے بعض پہلوؤ ں کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے ذریعہ جو ایسے معاشرہ سے کنارہ کش ہوگئے ہیں ان کی مدد سے سماج کو اسلامی بنائیں۔ کبھی ابن تیمیہ کے فتوؤں کا سہارا لیتے ہیں اور ایک ایسے معاشرہ سے مقابلہ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ جس میں مسلمان رہتے ہیں اور قابل تکفیر نہیں ہیں لیکن بہر حال ظالم حکام اور ان کے طاغوتی قوانین اور نظم و نظام کے تحت زندگی گذرار ہے ہیں اور کبھی حاکم کی جانب سے بیعت کے شرائط کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی مشروعیت کو ساقط اور اس سے مقابلہ واجب قرار دیتے ہیں۔(۱۲۰)
ہم بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک ہی ہدف ہے لیکن اسے حاصل کرنے کے لئے ہر ایک نے ایسے ایسے راستوں کا انتخاب کیا جن میں کسی قسم کی کوئی مشابہت اور موافقت نہیں ہے۔ یہ صورت خود ہی ہمارے اس مدعا کی دلیل ہے کہ ایک طرف ناقابل تحمل اور ناقابل تعدیل اور انحراف دباؤ پایا جاتا ہے جو خود ایک واضح اور قطعی جواب کا خواہاں ہے اور دوسری طرف اس کا کوئی راہ حل بھی نہیں ہے اور چونکہ صورت حال کچھ ایسی ہی ہے لہذا ہر ایک اس مشکل کی تمامیت کو مد نظر رکھے بغیر راہ حل کی تلاش میں مشغول ہے، اگر ہر ایک قرآنی آیات اور احادیث نیز تاریخی نمونہ کی روشنی میں کوئی حکم اخذ کرے تو اس صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ اسے باطل کرنے کے لئے اسی قرآن اور روایات اور تاریخ سے اس کے برخلاف تھیوری سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کے سلسلہ میں تمام وہ مطالعات جو اس کے اصول، مبانی، روح اور کلیت کو نظر انداز کرے اور اس کے مجموعہ اور بے بنیادوں سے سازگار نہ ہو تو وہ نادرست، ناقابل اعتماد اور دائم نہیں رہ سکتا ایسے صاحبان نظر اور ان کے نظریات کی مشکل اسی نکتہ میں پوشیدہ ہے۔(۱۲۱) یہی وجہ ہے کہ ایسے نظریہ چند جوان کو چند دنوں تک اپنی طرف جذب تو کر لیتے ہیں لیکن کچھ ہی مدتوں میں ناپید ہوجاتے ہیں۔ اس مسئلہ کو بہتر سمجھنے کے لئے بہتر ہے کہ ہم ان افکار کو تاریخی لحاظ سے مورد مطالعہ قرار دیں۔
اسلامی حکومت کی فکر
اہل سنت کی تاریخ میں اسلامی حکومت کی فکر اور اسے قائم کرنے کی کوششیں عثمانی خلافت کے سقوط تک پہنچتی ہیں۔ آغاز اسلام سے عثمانی خلافت کے سقوط تک برابر اسلامی سرزمینوں پر اسی کے قوانین حاکم رہے بلکہ اہم تو یہ ہے کہ پوری تاریخ میں خلیفہ کا ہونا دینی و معنوی اعتبار سے ایک عظیم پشت پناہ ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں کی تسکین کا باعث اور اس نکتہ کی یاد دہانی کرتا رہا ہے کہ اسلام کے قوانین و ضوابط ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں جاری و ساری رہے ہیں اور انھوں نے اس وظیفہ پر عمل بھی کیا ہے۔
عثمانی خلافت کے سقوط سے پہلے اسلام کی اپنی تاریخ میں، سیوطی کی تعبیر کے مطابق فقط تین سال مسلمان خلیفہ کے بغیر رہے ہیں۔(۱۲۲) اس کوتاہ مدت کے علاوہ اسلامی سر زمینوں پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلیفہ رہا ہے۔ یہ خودہی اپنے مقام پر اسلامی نہ ہونے یا اس کے پائیدار ہونے کی فکر کو ختم کردیا تھا تاکہ اس کے بعد ایسی حکومت کی بنیاد ڈالیں، اس کے علاوہ خود خلیفہ کا ہونا اس امر کا موجب تھا کہ اسے شرعا اور وجوباً مان لیا جائے، اس کے سامنے تسلیم اور اس کے فرامین کے سامنے گردن جھکا دی جائے اور اس کی بیعت کی جائے،اس لئے کہ ان کی نطر میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی گردن پر کسی امام یا خلیفہ کی بیعت ہو اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔(۱۲۳)
ان حالات میں مسئلہ،سیاسی تبعیت کا نہیں تھا بلکہ اس کے سامنے تسلیم ہوجا نے اور اس کی بیعت کرنے کا مسئلہ تھا یعنی ایسا ہر گز نہیں تھا کہ وہ خلیفہ کے سیاسی نفوذ کے زیر سایہ زندگی گذاریں، اٹھارویں صدی کے اواخر کے بعد جب عثمانی خلافت میں بڑی تیزی سے انحطاط اور ضعف پیدا ہوگیا تو اکثر مسلمان استانبول میں مستقر خلیفہ کے ماتحت نہیں رہ گئی تھے اور اس کے بعد سے اس نے اپنی گذشتہ شان و شوکت، قدرت اور افتخار سے ہاتھ دھو لیا تھا۔ ان تمام نقصانات کے باوجود اس کی دینی عظمت رسمی اور قانونی حیثیت سے مانی چکی تھی اور اس کی بیعت کو ایک عظیم فریضہ سمجھتے ہوئے انجام دے چکے تھے۔(۱۲۴)
خلافت کا خاتمہ
عثمانی خلافت کا سورج ۱۹۲۴ء میں ترک جوانوں کے ذریعہ غروب ہوگیا۔ مسلمانوں کے لئے خلاف توقع ایک عظیم سانحہ تھا۔ سارے مسلمان اس بات کا احساس کرنے لگے کہ ان کا عظیم پشت پناہ چل بسا ہے اور سب سے اہم فریضہ ترک ہوگیا ہے، اب ان کے لئے خلیفہ کے بغیر تدین ا ور اعزاز کے ساتھ مسلمان ہوکر زندگی گذارنا دشوار۔ اس وقت عثمانی خلافت کے زوال سے جو احساسات اور ہیجان عثمانیوں میں پیدا ہوئے بطور نمونہ ملک الشعراء ''شوقی''کے اشعار کی طرف رجوع کرنے سے بخوبی اندازہ ہوگا۔(۱۲۵)
عثمانی خلافت کے گرتے ہی عالم اسلام بالخصوص مصر میں جو تغیرات اور تبدیلیاں وجود میں آئیں، اس کی طرف ایک اشارہ کرنا ضروری ہے۔
مصر میںاس دورکے مشہور و معروف حوادث میں سے ''خلافت کی تشکیل کے لئے مجمع عام اسلامی'' کے عنوان سے ایک دائمی کمیٹی کی تشکیل تھی۔ کہ اس نے الخلافة الاسلامیة کے عنوان کے مجلہ (رسالہ) بھی نکالا۔ اس کمیٹی کا ہدف یہ تھا کہ اسلامی ممالک میں موجود حاکموں میں سے کسی ایک کو خلیفہ کے عنوان سے انتخاب کرلیں۔(۱۲۶) اس کمیٹی اور اس کے مجلہ کے علاوہ بہت سی علمی محفلوں میں امامت و خلافت کے عنوان سے بحثیں ہوتی رہیں۔ اس بحث و گفتگو کا انجام یہ ہوا کہ اشارہ بلکہ قاطعیت کے ساتھ اس بات کا اعلان کردیا کہ اتاترک کے ہاتھوں عثمانی خلافت کا خاتمہ سے اسلامی سماج کی اسلامیت ختم ہوگئی ہے اور تمام مسلمان خطاکار ہیں یہاں تک کہ کسی دوسرے خلیفہ کی بیعت کریں، یہ گناہ اپنے اخروی عذاب کے باوجود دنیاوی عذاب میں گرفتاری کا باعث ہوگا جو بہت جلد ہی ان تک پہونچے گا۔ اور یہ کہ مسلمان منصب خلافت کے ختم ہوتے ہی جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہیں اور جو بھی اس دور میں مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔
اس موضوع کے تحت بے شمار مجلے مقالے اور فتوے منتشر ہوئے اور یہ بھی کہا: اس زمانہ میں بھی گذشتہ ادوار کی طرح امام کا نصب کرنا ہر ایک پر واجب ہیاور تمام مسلمان ایسے امام کو منتخب نہ کرنے پر جس سے وحدت برقرار ہوجائے، تاحد ممکن گنہگار بھی ہیں۔ اور اس دنیا میں جو کچھ اہل بصیرت جانتے ہیں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور آخرت میں بھی جو کچھ خدا جانتا اسکی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے... وہ جماعت کہ جس کی پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا اسے اس وقت تک ہمیں مسلمان نہیں کہا جاسکتا جب تک اس کا کوئی اما م نہ ہو اور اپنے ارادہ و اختیار سے اس کی بیعت کی گئی ہو... مسلمانوں کا امام ان کی حکومت کا رئیس بھی ہے اور ان پر واجب بھی ہے کہ اس کی عزت، قدرت اور شان و شوکت بڑھانے میں لگے ہوں۔(۱۲۷)
عثمانی خلافت کے سقوط کے بعد بعض مسلمان مفکرین اور علما کو رشید رضا کی تعبیر کے مطابق ''جس حد تک اس دور میں مسلمان خلافت کا احیاء کرسکتے ہیں اسی حد تک کوشش کریں''(۱۲۸) اس کے مطابق خلافت کو احیاء کرنے کے لئے ابھارا، لیکن بے شمار دلائل کی بنیاد پر انھیں یہ توفیق حاصل نہ ہوسکی۔ گذشتہ ادوار اور اس دور میں بہت بڑا فرق تھا، گذشتہ ادوار میں جب کسی موقع پر خلافت ختم ہوجاتی تھی تو دوسرے مقامات پر اسے احیاء کردیا جاتا تھا۔ لیکن عثمانی خلافت کے خاتمہ کے بعد حالات بدل چکے تھے۔ تنہا مسلمان نہ تھے بلکہ غیر بھی اس امر میں دخیل اور مؤثر تھے اس لئے کہ ایسے حالات میں وہ بھی خاموش تماشائی نہیں بن سکتے تھے۔
اس کے علاوہ ایک نئی نسل پڑھی لکھی اور دانشور ظہور میں آچکی تھی۔ سیاسی اور اجتماعی اہم پوسٹیں انھیں کے ہاتھ میں تھیں۔ اس مسئلہ میں ترک جوانوں کی طرح سوچتے تھے وہ صرف خلافت کی بازگشت کی جانب مایل نہیں تھے بلکہ شدت سے اس کے مخالف بھی تھے، جیساکہ مصر کا اخبار نویس اور سیاست داں محمد حسین ہیکل، بھی انھیں افراد میں سے تھا۔ اس نے عبدالرزاق کے افکار کی شدت سے حمایت کرتا تھا اور حکومت کے گرتے ہی اس کے دفاع کے عنوان سے کتاب فورا بعد ہی منظر عام پر آگئی تھی، اس پر تنقید کرنے والے کے مقابلہ میں صف آرائی کرتا اور خلافت کو احیاء کرنے والوں کو اپنی تنقیدوں کا نشانہ بناتا اور وہ اس طرح کہتا ہے: علماء اسلام میں سے اس عالم کے لئے کیا کہا جائے گا جو مسلمانوں کے لئے خلافت کے نہ ہونے کا خواہاں ہے ا ور وہ بھی ایک زمانہ میںکہ جس میں تمام مسلمان حکام خلیفہ بننے کی فکر میں ہوں۔(۱۲۹)
''اسمیت'' دوران معاصر میں مصر اور اسلام کے متقابل روابط کو محمد حسین ہیکل کی سوانح حیات بیان کرتے ہوئے تحقیق و بررسی کرتا ہے: اس دوران مصر میں ہر ایک سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی تبدیلیوں سے متأثر تھا۔ ان میں سے ہر فرد ایک حد تک ۱۹۲۰ء میں مدرنیست کی جانب سے ہونے والے ان اقدامات سے متأثر تھا جو اسلام اور مسلمانوں کی قدرت کو محدود کرنا چاہتے تھے ایسے اقدمات جو عبد الرزاق کی کتاب الاسلام و اصول الحکم نیز فی الشعر الجاھلی طہ حسین میں منعکس ہو چکے تھے۔(۱۳۰)
بہرحال حددرجہ کوشش اور بعض خلافت کے واجب شرعی ہونے کے سچے مقصد کے باوجود ناکامی سے دوچار ہوئی، خلافت کا دور ختم ہوا اور اسے دوبارہ احیاء کرنے کے لئے تمام کوششیں بے ثمر ثابت ہوئیں۔ مسلمانوں نے خلافت کو اپنی خواہش اور چاہت کے باوجود اس امر کو قبول کر لیا کہ اب خلافت کو دوبارہ احیاء نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ اس وقت بعض اسلامی ممالک کے حکام اس عنوان کے لئے خود کو نامزد کرنے کے بارے میں وسوسہ میں مبتلاء ہوئے۔ لیکن ان وسوسوں کو زیادہ حیات نہ مل سکی اور اس خواب نے واقعیت کو اپنا قائم مقام بنادیا۔ اور یہ فکر فراموشی کے حوالہ کردی گئی۔(۱۳۱)
اس حادثہ کے ختم ہوتے ہی ایک دوسرا حادثہ وجود میں آیا اور پروان چڑھنے لگا اور وہ اسلامی حکومت کی فکر تھی کہ جو اکثر مذہبی علما اور دانشوروں کی نظر میں اسلامی خلافت اور اس کے استمرار کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔(۱۳۲) خلافت کے سقوط سے پہلے اس فکر کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ گذشتہ خلفاء اور سلاطین اگرچہ فاسق و فاجر تھے لیکن دین کے مقابلہ میں جس طرح وہ لوگوں کے درمیان رائج تھا نہیں آئے، حتیٰ کہ بہت سے موارد میں ان کے منافع کا اقتضاء یہی تھا کہ اس کی ترویج کریں۔ جس طرح سے کہ معاشرہ کی دینی واقعیت کے مقابلہ میں خارجی یا داخلی اہم اسباب بھی واقع نہیں ہوئے۔ ہر شی ایک حد تک دین اور دینی میراث کے مطابق موافق تھی۔
لیکن زمانہ کے گذرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا تھا۔ صنعتی، علمی اور فکری تغیرات اور مذہبی محدودیتوں کا وسیع ہوجانا، پورے طورپر بیگانوں کا تسلط، بالواسطہ یا بلاواسطہ استعمار سے حکام یا صاحبان قدرت کا وابستہ ہونا، ان تمام اسباب و علل نے ایک جدید تغیر ایجاد کردیا تھا گویا دین ہر طرف سے حملوں کا شکار ہے، یہاں اہم مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہعثمانی خلافت اسلامی معاشرہ کی سیساسی، اجتماعی اور نظامی اسلامیت کا آخری مظہر درہم برہم ہوچکا تھا، بلکہ سب سے اہم تو یہ تھا کہ بنیادی اعتبار سے حالات بالکل بدل چکے تھے اور واقعا ًاس وقت کے مسلمان اس بات کا احساس کر رہے تھے کہ ان کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔(۱۳۳)
ایسے حالات میں ایک دوسرے جدید مفہوم کی نگاہیں جمی ہوئی تھیں اور وہ حکومت کا موضوع تھا۔ لیکن یہ کوئی نیا مفہوم نہ تھا۔ ہاں! اس کا اسی شکل میں محقق ہونا جیساکہ قرن حاضر کے وسط میں واقع ہوا اور ایک دینی و سیاسی ہدف کی شکل میں ظاہر ہونا یقینا ایک جدید مسئلہ تھا۔ اس مفہوم نے بڑی تیزی سے کثیر تعداد میں حامیوں کو اکٹھا کرلیا نیز اصلی اور قابل قبول اور متفقہ طورپر ایک سیاسی ارمان کا خلا اسلامی معاشرے کے سیاسی ارمان سے پُر ہوگیا اس کے بعد بہت سے حوادث رونما ہوئے جو اسے عمومیت بخشنے اور محبوب بنانے میں نہایت مددگار ثابت ہوئے۔(۱۳۴)
مغربی قوانین کا نفوذ
انھیں حالات کے ساتھ ساتھ تیزی سے غربی قوانین اسلامی ممالک میں نفوذ کرگئے البتہ خلافت کے خاتمہ سے اس کا کوئی ربط نہیں تھا اس لئے کہ اگر عثمانی خلافت باقی بھی رہتی تو بھی غربی قوانین تمام اسلامی ممالک بلکہ خود ترکی میں نفوذ کرجاتے، بلکہ اس دور میں بھی ایک حد تک نفوذ کرچکے تھے۔ یہ اس دور کے مجموعی حالات کی وجہ سے تھا اور اس میں عثمانی خلافت کاکو ئی کردار نہیں تھا اگرچہ بعض نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔(۱۳۵)
اس دور میں اسلامی ممالک میں رہنے والے تمام مسلمان اپنے محدود معاشرہ میں بیدار ہوچکے تھے۔ بدلتے حالات، حد سے زیادہ دباؤ، غربیوں کے مقابلہ میں ناتوانی جیسے عوامل نے انھیں متأثر ہونے اور عکس العمل دکھانے پر مجبور کردیا تھا، منکرین اور دین کے مخالفین، مغربی نظام اور اس کے قوانین اور فرہنگ و تمدن کے مدعی کھلم کھلا تنہا اس میدان کے شہسوار تھیاور کوئی نہ تھا جو انھیں روکتا ا ور ان کی من مانیوں کے سامنے قیام کرتا، بلکہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو اس طغیانی موج کا سامنا کرتا اور انھیں روکتا۔(۱۳۶)
ایسے حالات میں یہ فطری بات تھی کہ اسلامی ممالک کے اساسی قوانین مغربی قوانین کے پرتو میں بنائے جائیں اور ان پر نظر ثانی کی جائے اور چونکہ تمام اسلامی ممالک آزادی خواہی کی اٹھنے والی موج کے ہمراہ تھی ایک جدید تاریخ میں قدم رکھ رہے تھے لہذا اس دور میں کوئی بھی ہوتا تو اس کی نظر سب سے پہلے قانون اساسی پر جاتی، اب ایسے حالات میں مغربی قوانین کے علاوہ اور کون سے قوانین تھے کہ جس سے جدید قوانین اقتباس کئے جاتے۔(۱۳۷)
یہ موضوع چونکہ توضیح طلب ہے لہذا ہم اسے جاری رکھتے ہیں، اسلام کی پوری تاریخ میں مسلمان جہان سوم میں جینے والے انسانوں کی طرح ہمیشہ اپنے حکام کے ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں ظلم و ستم اور استبداد کی سب سے بڑی خصوصیت قانون اور مخالفت ہے، جو کسی قانون کا نہ تو پابند ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قانون کے سامنے تسلیم ہوتا اور اسے قانونی حیثیت بھی نہیں دیتا ہے۔ اب ایسے حالات میں انقلابات آتے گئے اور لوگوں کی آنکھیں کھلنے لگیں کان متوجہ ہوئے اور جب ان کی آنکھیںکھلیں تو انھوں نے دیکھا کہ وہ نہایت بچھڑے ہوئے، سیاسی و اجتماعی اعتبار سے بد ترین شرائط میں جی رہے ہیں۔ البتہ ان احساسات کو ہوا دینے میں دانشمندوں کی نئی نسل نے بڑی کوششیں کی ہیں، اس وقت کے مسلمان ظاہری اعتبار سے اپنے سماج کا اس وقت کے مغربی ترقی یافتہ ممالک سے مقابلہ کرتے ہوئے اس نتیجہ پر پہونچے کہ اور اپنی اس بدبختی کا سبب سیاسی استبداد ہیاور اس کا اصلی سبب حقوقی اور قانونی نظام کا فقدان ہے لہذا جس حد تک آزادی خواہی کی فکر کو ہوا دے سکتے تھے دیا اور اپنے ہدف تک رسائی کے لئے قانون اساسی اور دیگر قوانین کی تنظیم و تدوین پر زور دیا۔
ان کی نظر میں پورے طورپر مشکل آزادی کے نہ ہونے اور استبداد کی حاکمیت کی وجہ سے تھی کہ جس سے چھٹکارا اساسی قانون کا وجود تھا، ایسے حالات میں فطری طورپر تشفی بخش قانون وہی مغربی قانون تھے۔(۱۳۸) شاید یہ ان کے انتخابوں میں ایک بدترین انتخاب تھا جسے اسلامی سماج انجام دے سکتا تھا کہ جس کے بعد بے شمار ناگفتہ بہ حالات کا سامنا تھا، ہم اس مقام پر اس انتخاب کے صحیح نہ ہونے کے سلسلہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے بلکہ اہم تو یہ ہے کہ اس انتخاب کے بعد لاتعداد قوانین کسی احتیاج کے بغیر اسلامی ممالک میں پھیل گئے جبکہ اسلامی ممالک کو ان قوانین کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگرچہ یہ مسلم ہے کہ اس دور میں کوئی قانون تدوین کرنے والا نہیں تھا لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کے منابع فقہ اور اسلامی قوانین ہیں ان کے پاس ضرور تھے۔ جن کی مدد اور سہارے اپنی مختلف مشکلات کو حل کرسکتے تھے جیساکہ بعض اسلامی ممالک میں ایسا ہی ہوا۔(۱۳۹)
بہر حال اسلامی ممالک میں نظام کو موجودہ صورت حال کے مطابق حقوقی اور قانونی نظام کو مارڈن انداز میں سنوار نے کا پہلا موقع تھااور جیساکہ ہم نے بیان کیا کہ یہ تجربہ مومن اور متدین حضرات کی عدم موجودگی میں انجام پایا اس لئے کہ وہ وحشت رعب و اور دبدبہ میں زندگی گذار رہے تھے اور دشمن کے لئے میدان کو خالی کر چکے تھے لیکن جب انھیں ہوش آیا تو دیکھا کہ بہت سے قانون اسلامی اصول و مبانی کے برخلاف اس کے باوجود اور اس کے مقابل جدید قوانین کے سامنے تسلیم ہیں۔
یہاں مناسب ہوگا کہ ویلیم شیفرڈ کے نظریا ت کو بیان کریں، کہ کس طرح مسلمان تاریخ جدید میں وارد ہوئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ کہتا ہے: یہ فوجی طاقت تھی کہ جس کی مدد سے پہلی مرتبہ اسلامی حکام تک تغییرات کو راستہ ملا، جسے اٹھارویں اور انیسویں صدی کی ابتدا میں ہند میں انگلینڈ کی فتوحات، روس کے ہاتھوں، ۷۴۔۱۷۶۸، کی جنگوں میں عثمانیوں کی شکست، اگرچہ عثمانی دارالحکومت والے اسی صدی کے آغاز ہی میں مغربی نظام کی فوقیت و برتری کے پیش نظر اپنے سماج کو ایک حد تک مغربی شکل و صورت میں ڈھالنے کے لئے قدم اٹھاچکے تھے۔ لہذا سب سے پہلے جنگیں اصلاحات موجب بنیںکہ جس کی وجہ سے عثمانی اصلاح طلب جد و جہد پر مجبور ہوگئے، لیکن جب یہ اصلاحات شروع ہوگئیں تو پھر جو حدود ان کے رہبروں نے معین کئے تھے اس میں محدود نہیں رہ سکتی تھیں۔(۱۴۰)
اس کے بعد اپنے بیان کو اس طرح جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: اگر عیسائی الہیات اس دنیا میں خدا اور اس کے افعال کی ماہیت کو معلوم کرنے کی تلاش میں تھی تو مسلمان فقہا خداوندعالم کے ارادہ، قوانین اور شریعت الٰہیہ کو سمجھنے کی کوشش میں تھے کہ جس میں تمام انسانوں کے وظائف کوبیان کردیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نئے حالات کے مطابق قوانین کو مخصوصا اجتماعی و سیاسی اعتبار سے ڈھالنے کیلئے تمام کوششیں ہورہی تھیں لیکن الہیات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی،وہ شک و شبہات کہ جسے غرب میں داروین نے ابھارا تھا اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، جب کہ قرآ ن نے خلقت کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق ہے۔(۱۴۱)
یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اہل سنت کی حکومت میں اسلامی تحریکوں کی فکری آغاز کا سدباب ہوجاتا ہے اور جیساکہ اس سے پہلے بھی ہم نے وضاحت کی ہے کہ ان کے نزدیک فقہ و کلام اور تاریخی تجربوں کی عمارت ایسی نہیں تھی جو ظاہری مسلمان حاکم کے سامنے قیام کی اجازت بس اتنا تھا کہ قلبی اعتبار سے ان کے سامنے تسلیم نہیں تھے، اس سے دور ہوئے اور اس کی خدمت میں نہ رہیاور یہ حددرجہ گستاخی تھی کہ اس کے سامنے زبان اعتراض کھولیںاور اس کی جانب سے ہونے والے مظالم اور بدعتوں اور زیادتیوں کے خلاف اقدام کریں، لیکن حاکم اور اس کے نظام کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کی مختلف دلائل سے اجازت نہیں دیتے تھے کہ سیاسی اور نظامی اعتبار سے کوئی قدم اٹھائیں۔ اس زاویہ سے نظام حاکم کے خلاف اعتراض کرنا درست نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی راہ حل تھا لیکن دور حاضر میں غیر اسلامی قوانین کے ظہور کرتے اسے حاکمیت عطا کرتے ہی حاکم پر اعتراض کا ایک نیا باب کھول دیا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام سنی ہم عصر تحریکوں کو موقع مل گیا کیونکہ یہ ایک نئی راہ حل تھی کہ جس نے انھیں حیات و فعالیت کا موقع فراہم کیا۔(۱۴۲)
شریعت کی مطابقت
ان کی نظر میں اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی قوانین کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سب کو اسلامی قانون تسلیم کرنا ہوگا اس لئے کہ تنہا یہ قانون ہے کہ جسے حاکمیت حاصل ہے، اس راہ میں جد و جہد ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جس میں چون و چرا اور تغییر و تبدیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ وہی مفہوم ہے جسے بعد میں ''تطبیق شریعت'' کانام دے دیا گیا۔ جس نے اپنی طرف انقلابی اور متدین اہل سنت کے افکار کو متوجہ کرلیا تھا اور جو تحریکیں اس غرض سے وجود میں آئی تھیں ان کی توجیہ کا موقع مل گیا۔(۱۴۳)
موجودہ صدی کے اواخر میں اہل سنت کی طرف سے جتنی تحریکیں اور قیام وغیرہ وجود میں آئے ہیں وہ سب اسی ہدف کے پیش نظر تھے۔ ان کے نزدیک اسلامی حکومت یعنی وہ حکومت کہ جس میں اسلام کے تمام احکامات جاری و ساری ہوں۔ لہذا حکومت کو اساسی بنانا یعنی اسلامی قوانین کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام مراحل اور شعبوں میں جاری کرنا اور انھیں حاکمیت عطا کرنا پس یہ ایک ایسی فکر ہے کہ جو خود ہی اصلاحی ہے نہ کہ انقلابی۔ جو موجودہ نظام کی ضد نہیں ہے بلکہ موجودہ قوانین کے خلاف ہے۔ اس کا ہدف صرف قوانین کو بدل دینا ہے نہ کہ حاکم کو بدلنا مقصود ہے اور اگر حاکمِ وقت قوانین کے بدلنے پر راضی ہوجائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کی بقا کے ساتھ قوانین کی تغییر قابل قبول ہے۔اور اگر موجودہ قوانین کے دفاع میں عوام کے سامنے کھڑا ہوجائے اور کسی بھی صورت میں اس کی تغییر کو قبول نہ کرے تو اس صورت میںاس بات کا امکان ہے کہ اسکے خلاف قیام کا فتوا دے دیا جائے۔(۱۴۴)
اس تحریک کااصلی ہدف اور مقصد سماج کے حقوقی اور قانونی نظام کے ذریعہ اسے اسلامی بنانا ہے۔ نہ کہ سیاسی حاکمیت کی تبدیلی کی آڑ میں اسے اسلامی بنانا مقصود ہے۔ یہاں اصل مشکل اس تغییر کے لئے حاکم کی رضایت ہے اور اگر وہ خود ان تغیرات کو انجام دے تو اس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے، اسی نظریہ کے مطابق سعودی حکام اور دوسرے حکام ۸۰ء میںکہ جس میں اسلام خواہی اپنے اوج پہ تھی، اپنی شریعت کی تطبیق کرنے لگے، پاکستان میں ضیاء الحق نے، سوڈان میں نمیری نے اور مصر میں سادات نے اور دیگر خلیج فارس کے شیوخ نشین مقامات مطلوب ہیں۔(۱۴۵)
البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ طرز تفکر چالیس پچاس سال پہلے کہ جب غیر اسلامی قوانین رائج اور غالب تھے، اگرچہ وہ ایک اصلاحی تفکر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا لیکن اس دور میں اسے ایک انقلابی تفکر مانا جاتا تھا۔ لیکن یہی تفکر آج کے دور میں کہ جس میں حالات پوری طرح بدل چکے ہیں اور جوانوں کی نفسیاتی اور مذہبی آرزوئیں اور رجحانات دگرگوں ہوچکے ہیں، ایسے حالات میں ان کی جہادی اور انقلابی روح کو سیراب نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ لوگ اس دور میں اس اس تفکر کی ظرفیت سے کہیں زیادہ متوقع اور عظیم اہداف کو حاصل کرنے کی تلاش میں ہیں، یہ لوگ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی قوانین اور اقدار کے جاری ہونے کے خواہاں ہیں۔ اور تنہا حیات اجتماعی میں قوانین اسلامی کی حاکمیت کے قائل نہیں ہیں کہ شریعت اپنے قوانین کو اجتماعی امور سے مطابقت دے، اہل سنت کی حکومت میں موجودہ تحریکوں کی اصل مشکل اسی ایک نکتہ میں پوشیدہ ہے۔ دورحاضر میں ان لوگوں کے لئے فقہ و کلام میں جو چھوٹ ملی ہے وہ موجودہ نسل کی قطعی اور شدید ضرورتوں کو برطرف کرنے اور اس کا جواب دینے سے معذور ہے۔(۱۴۶)
اسی محدودیت کی بناپر اکثر اسلامی تحریکوں کے سربراہ خواہ وہ سید قطب ہوں یا عتیبی یا عبدالسلام فرج، ہر ایک نے اپنے لئے توجیہ کا باب کھول لیا ہے جو اہل سنت کے نزدیک کلی طورپر ان کے اصول اعتقادات اور اجماع سے اجنبی ہیں۔ ان سربراہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی توجیہ میں قرآنی شواہد اور سنت نبوی کے علاوہ گذشتہ علما کے فتاوی مخصوصا ابن تیمیہ اور ابن قیم کے نظریات کا سہارا لے کر ایک ایسے تفکر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو موجودہ حاکم کے خلاف قدم اٹھانے کو مشروع قرار دیتا ہے بلکہ اسے واجب بھی سمجھتا ہے۔ اگر سنی علما ایسے تفکرات کو شک و شبہہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دعویداروں، وضع کرنے والوں اور سربراہوں کو اعلانیہ طورپر خوارج کا لقب دیتے ہیں۔ تو یہ سنیوں کا طرزعمل اپنے تحفظ اور عافیت طلبی کے عنوان سے نہیں ہے بلکہ ان کے کلام و فقہ میں متفق علیہ اصول و مبانی پر اعتماد کے پیش نظر ہے اور انکا سہارا لے کر انہیں خوارج کہتے ہیں۔(۱۴۷)
وہ لوگ کو جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اس لئے کہ قرآن و سنت، سلف صالح اور سیرہ صحابہ کہ جس پر تمام سنیوں نے زمان دراز تک عمل کیا ہے اور اسے درک کیا ہے انہیں مدنظر رکھتے ہوئے ایسے نظریات کو قبول نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ یہ نظریات قرآن و سنت اور سیرۂ صحابہ سے نہایت مفرط ترین نتیجہ تھا جسے ان لوگوں نے حاصل کیا تھا۔ اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایسے لوگ بھی رہے ہوں گے کہ جن کی نیتوں میں کھوٹ یا ان میں کسی قسم کی کوئی وابستگی ہوگی جب ہی ایسی بات کہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا سہارا لیا بلکہ ایسا ہوا بھی ہے، اس دور میں سعودی اور وہابی علما اسی فکر کے طرفدار ہیں، بہرحال حقیقت جو بھی ہے، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کا قائل کون ہے یہ بات اپنی جگہ پر صحیح اور درست ہے۔(۱۴۸)
یہ تھے چند نظری مسائل لیکن انکے علاوہ کچھ اور بھی مسائل ہیں۔ جیساکہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ تاریخ معاصر میں سنی اور شیعی تحریکوں میں فرق صرف ان کے افکار و نظریات میں نہیں ہے بلکہ اجتماعی اور نفسیاتی فکرمیں بھی ہے۔ ہر ایک نے اپنے اصول اور خصوصیات کے مطابق نفسیاتی اور اجتماعی عمارت بنا رکھی ہے۔ اور یہ فرق صدیوں کے دو متفاوت نظریہ تجربوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا جتنی عظیم اور وسیع تحریکیں بھی ان دو گروہوں میں اٹھیں گیں وہ سب انھیں دو متفاوت مجموعہ سے متأثر ہوں گیں اور حقیقت بھی یہی ہے اور جب کہ ایسا ہے تو پھر یہ توقع بیجا ہے کہ ان تحریکوںکے اسلامی ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے مظاہر اور ان کے اثرات یکساں ہونا چاہئے۔یہ بات درست ہے کہ یہ دونوں تحریکیں اسلامی ہیں اور اسلام کو حاکمیت عطاکرنے کو اپنا ہدف بنائے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ تویہ ہے کہ یہ دونوںنظریات اسلام کی مختلف تفسیریں ہیں جو اب تک چلی آرہی ہیں اور ابھی بھی واقعیت وہی ہے جو پہلے تھی۔(۱۴۹)
اہل سنت کی انقلابی اوراسلامی تفکر کی پہلی مشکل فقہی و کلامی محدودیت ہے کہ جو اس بات کی اجازت نہیںدیتی کہ ظالم حکام کے مقابلہ میں قیام کیا جاسکے اور دوسری طرف سرعت سے بدلتے ہوئے حالات ہیں بعض اسلامی ممالک میں جوان نسلوں کی اسلام خواہی نے انھیں جہاد اور مبارزہ کی دعوت دی ہے۔ یہی دو اسباب موجب بنے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت کے علما اور دین کے دلدادہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی ہمراہی نہ کرسکے۔(۱۵۰)
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حکام کا علمی و دینی مراکز پر قبضہ کرنا اور انکے استقلال کو سلب کرلینا نیز انھیں اپنی خدمت کے لئے مجبور کرنا بھی ایسے حالات کو وجود بخشنے میں مؤثر رہے ہیں۔ سنی ممالک میں صاحبان قدرت مخصوصا عربی ممالک جو اسلامی تحریکوں کے عظیم مراکز ہیں وہ خواہ تونس ہو یا مراکش، مصر ہو یا سوریہ یا سعودی عرب (عربستان) اور یمن، ان آخری دہائیوں میں ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ علمی و دینی مراکز اور تعلیم کو جدید اصول و قوانین کے تحت قرار دینے کے بہانے سے انھیں اپنے قبضہ میں لے لیں اور وہ اپنے اس ہدف میں ایک حد تک کامیاب بھی رہے ہیں، اہم یہ نہیں تھا کہ یہ تغیرات ان مراکز پر تسلط کا باعث بنے بلکہ اہم تو یہ تھا کہ وہ اپنی پایداری دینی اصالت اور علمی شمول کھو بیٹھے اور یہ روش ضرورت روزگار کے خلاف تھی جب کہ دینی ضرورتوں اور علمی و اخلاقی ضرورتوں کو اسی حد تک پورا کرنا واجب تھا کہ جتنا جینے اور اس کے درک کرنے کا محتاج ہیاور یہ بات مسلم ہے کہ وہ لوگ جو مختلف میدانوں میں اسلام کی عظیم میراث سے بے خبر ہیں وہ اس دور کی مختلف ضرورتوں کا شائستہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔(۱۵۱)
یہ مشکلات ۱۹۶۰ء کے درمیان وجود میں آئیں اور ۱۹۷۰ء کے حالات نے انھیں عروج بخشا اور پھر انقلاب اسلامی ایران نے اسے کمال تک پہونچایا، اصل مشکل اسلام کی ایک جدید تفسیر کی تلاش تھی جو انھیں انکے جہادی تفکر میں مددگار ثابت ہوسکے۔ انھیں اسلامی معاشرہ کی برقراری میں رہنمائی کرے اور ان سے کہے کہ اسلامی معاشرہ تک رسائی کے لئے کیا کرنا چاہئے اور کس طرح ان سے مبارزہ کریں، انھیں حالات میں ایک علمی و دینی، آگاہ اور قابل اعتماد شخصیت کی مدد سے قیام کربیٹھے، لیکن اصل مشکل یہ تھی کہ انھیں قلت کا احساس تھا اور جو کچھ انھیں انجام دینا تھا اسے پوراکرنے کا ارادہ بنا چکے تھے کہ انھیں کیا کرنا ہے اور کیا حاصل کرنا ہے۔ ان کی مختصر معلومات ان سوالوںکا جواب بن گئی کہ جس کا جواب پہلے دیا جاچکا تھا اور ہدف یہ تھا کہ ان کے جواب کے لئے تائید حاصل کریں۔(۱۵۲)
ایسے حالات میں یہ جوابات پورے طورپر اسلامی نہیں ہوسکتے تھے۔ ہاں انھیں ایک اسلامی رنگ مل سکتا تھا اور چونکہ یہ جوابات جوانوں اور طالب علموں کے اعتقادات و افکار اور نفسیات کے مطابق تھے لہذا انھیں تیزی سے اپنے طرف جذب کرلیا اور انھوں نے اسے ایک اسلامی راہ حل سمجھ کر قبول بھی کرلیا۔ لیکن اس میں دو ایسی بنیادی مشکلیں تھیں کہ جس کی وجہ سے بدلتے حالات کا مقابلہ کرنے اور اسے دوام بخشنے سے عاجز تھا۔ ایک نظریہ کی میزان مقاومت بالخصوص انقلابی اور جنگجو افراد کے نظریات، زمانہ کے حوادثات کے مقابلہ میں اسی وقت ٹھہر سکتا ہے جب دور حاضر میں پیش آنے والی مشکلات کا جواب دینے پر قادر، منسجم اور اصول و قوانین پر قائم ہو، لیکن یہ فکر ایسی خصوصیات سے عاری اور خالی تھی۔
چوتھی فصل کے حوالے
(۱)اس طرز تفکر کے عملی نمونہ کتاب العواصم من القواصم ابن عربی اور مخصوصا محب الدین خطیب کے حواشی میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں کہ جہاں تک ان لوگوں کی خطاؤں کی توجیہ و تفسیر کرتے ہیں جو ان سے دفاع کرتے ہیں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ عملی طور پر واقعیت کو معیار قرادیتے ہیں، ان لوگوں کی نظر میں عدالت وہی ہے جو اپنی ابتدا سے تھی نہ یہ کہ کوئی عظیم مفہوم ہے کہ جسے موجودہ صورت حال سے مطابقت دے۔
آپ زیاد کی طرف سے معاویہ کے تعارف کو ملاحظہ کریں جس میں صرف اور صرف ایک سیاسی پہلو ہے اور اس کی قدرت کو دوام بخشنا منظور ہے۔ الجوہر النفیس فی سیاسة الرئیس ص۷۳۔
مثلاآپ ابن عربی جو معاویہ کا دفاع کرتا ہے کی توجیہ کا مطالعہ کریں جب کہ اسی نے ابن عدی کے قتل کا حکم دیتا ہے کہ جس پر ہر ایک نے اعتراض کیا یہاں تک کہ عائشہ نے بھی اعتراض کیا علی و بنوہ ص۲۱۹ پر ابن عربی کی توجیہ کو ملاحظہ کریں: اگر یہ مان لیاجائے کہ ابن حجر کو قتل کرنا ظلم تھا مگر یہ کہ قتل کا موجب فراہم ہوجائے تو میں کہوں گا: اصل یہ ہے کہ امام کا قتل کرنا حق ہے اور جو اس قتل کے ظلم ہونے کا قائل ہے اسے اپنے اس مدعا کو ثابت کرنا ہوگا اور اگر یہ ظلم تھا تو پھر معاویہ پرتمام گھروں میں لعنت کرنا چاہئے تھا۔ جب کہ بغداد جو عباسیوں کی خلافت کا مرکز تھا اور امویوں سے ان کی رقابت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی بغداد کی مسجدوں کے دروازوں پر یہ جملہ لکھے ہوا ہے آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کے بعد بہترین لوگوں میں ابوبکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی اور پھر خالالمؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ص۲۱۳۔
(۲)اس طرح کے فکری نمونہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن حنبل کے نظریات اور آثار میں ملاحظہ کرسکتے ہیں۔ السیاسة والشریعة ص۱۰و ۲۱؛ اعلام االموقعین، ج۳، ص۳۔ ۶ الاحکام السلطانیة اور نیز گذشتہ فصل کی ۵۴ویں توضیحات کو ملاحظہ کریں۔
(۳)المواقف فی علم الاصول ص۳۲۳
(۴)مزید وضاحت کے لئے من العقیدة الی الثورة نامی کتاب، ج۱، ص۳۔ ۴۱ کے مقدمہ ملاحظہ ہو۔
(۵)ملاحظہ کریں۔
Amir H.Saddiqi Caliphate and kingship ,pp .۲.۵
(۶)یہ بات شیعوں کے نزدیک بھی قابل قبول ہے، رجوع کریں الشیعة والحاکمون ص۷،۸ اسی طرح الفکر السیاسی الشیعی ص۲۶۸۔ ۲۷۱۔
(۷)بطور نمونہ مراجعہ کریں، عدالت کے سلسلہ میں امویوں کی تفسیر سے متفاوت مفہوم کے تحت غیلان دمشقی کا ارمنستان کے لوگوں کو قیام کے لئے دعوت دینا۔ ذکر باب المعتزلہ ص۱۷ و ۱۶ اسی طرح عدالت کی برقراری کے لئے ہونے والے شیعوں اور معتزلہ کے قیام انتفاضات الشیعة ص۹۷۔ ۱۱۰۔
(۸)مطلوب حاکم اور حاکم کے مطلوب نظام نیز یہ کہ عدالت کو اس کا مقام نہیں مل سکا ہے جو ہونا چاہئے لہٰذا اہل سنت کے مضبوط اور پختہ افراد کی پریشانیوں کو دریافت کرنے کے لئے مناقب الامام احمد ابن حنبل ص۴۳۸، اسی طرح طبقات الحنابلہ ج۲، ص۳۱ملاحظہ ہو اور کس طرح یہ لوگ عمر ابن عبد العزیز کی طرح متوکل جیسے فاسق و فاجر، ظالم و جابر سفاک اور ستمگر کی صرف ا س وجہ سے تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بدعتوں کا مقابلہ کیا تھا۔
(۹)حقیقت تو یہ ہے کہ شیعوں کے عقائد کا تمام پابندیوں کے باوجود سماج میں نفوذ اہل سنت کے عقائد سے کہیں زیادہ ہے کہ جس سے صرف اور صرف موجودہ حاکمیت ہی نے فائدہ اُٹھایا ہے۔ من العقدة الی الثورة ص۱،۲۶۔
(۱۰)معتزلہ کی مذمت اور تنقیص نیز ان کے اعتقادات کو شکل دینے سے متعلق اہل سنت کی پریشانیوں کو طبقات الحنابلة ج۲، ص۳۰، ۳۱ اسی طرح کتاب الابانة عن اصول الدیانة ص۱۳، ۱۶ نامی جیسی کتابوں میں ملاحظہ کریں
(۱۱)فقہ السنة ج۱، ص۲۰۹ و ۲۱۰ المحلی ج۴، ص۲۱۳، ۲۱۴ اور اس مسئلہ کی تفصیل کو المجتہد و نھایة المقصد ج۱، ص۱۴۷، ۱۴۸ کے آغاز میں ملاحظہ کریں۔
(۱۲)اس سلسلہ میں امام باقرـ سے نماز جماعت کے بارے میں کئے گئے سوال کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لئے وسائل الشیعہ ج۵، ص۳۸۱ حدیث نمبر۵ نیز ۸ ص۳۷۷ اسی طرح مستدرک وسائل الشیعہ ج۶، ص۴۵۷ ملاحظہ کریں۔
(۱۳)حنابلہ نماز جماعت میں شرکت کو واجب سمجھتے ہیں۔ الفقہ علی المذہب الاربعة ج۱، ص۳۷۵ نامی کتاب ملاحظہ ہو، ظاہریہ فرقہ بھی مکلفین پر نماز جماعت کو واجب سمجھتا ہے بدایة المجتہد ج۱، ۱۴۳۔
(۱۴)غیبت کے زمانے میں نماز جماعت و جمعہ کے جواز کے قائلین کی دلیلوں کی رد جامع المقاصد نامی کتاب کی ج۲، ص۷۴، ۳۸۰ ملاحظہ ہو نیز کتاب رسالة صلوة الجمعة حیدر ابن المولی محمد الذرفولی، شیخ انصاری کی تقریظ کے ہمراہ اسی طرح رسالة فی صلوة الجمعة کرکی، کو کتاب رسائل المحقق الکرکی ج۱، ص۱۱۷، ۱۴۰ ملاحظہ ہو۔
(۱۵)کنزل العمال ج۷، ص۵۸۱و ۵۸۲۔
(۱۶)ابوبکر کی پیش نمازی باعث بنی تھی کہ جس کی وجہ سے حسن بصری، ابن حزم اور اہل حدیث کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہوگئی کہ ابوبکر کی خلافت منصوصاور آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کی سفارش اور تائید سے تھی معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی ص۱۳۳۔
(۱۷)مزید وضاحت کے لئے البدر الزاہر فی صلاة الجمعة والمسافر ص۶۔۸ ملاحظہ ہو۔
(۱۸)رسائل المحقق الکرکی، ج۱، ص۱۴۴
(۱۹) Shorter Encyclopaedia of Islam,p.۳۵۰
(۲۰)الامامة و السیاسة، ج۱، ص۳۴، فقہ السنة ج۱، ص۲۰۹
(۲۱) Goldziher Muslim Studies , Vol ۲nd , P, ۵۰
(۲۲)عیون الخبار، ج۲، ص۲۸۲
(۲۳)گذشتہ حوالہ، ص۲۸۱
(۲۴)اس مسئلہ پر اہل سنت اور شیعوں کا اجماع ہے کہ آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت نماز جماعت سے اعراض کرنے والوں کو سرزنش ہی نہیں بلکہ تہدید بھی کی ہے اور ڈرایا بھی ہے، کنز العمال ج۷، نماز جماعت میں شرکت کرنے کے وجوب کے باب میں، ص۵۸۲، ۵۸۱۔ نیز نماز جمعہ میں شرکت کے وجوب کے باب میں، ج۵، ص۳۷۶، ۳۷۷ نیز جامع المدارک ج۱، ص۴۸۹، کہ جو منقول ہے الشھادات وسائل الشیعة نامی کتاب سے۔
(۲۵)اس مسئلہ میں عباسیوں کی روش بھی امویوں کی جیسی تھی کہ جو کچھ نماز جماعت و جمعہ سے مربوط تھا اسے اپنی ذات سے مخصوص کرلیا تھا خلفاء عباسی کے آشکار ترین دینی مظاہر سیادت میں ایک یہ تھا کہ پنجگانہ نمازوں کے اوقات میں ان کے گھروں کے سامنے طبل بجایا جاتا تھا تاکہ اس کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان کریں، یہ عمل صرف اور صرف خلفاء سے مخصوص تھا اور کسی دوسرے بلکہ ولی عہد کو بھی یہ اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ اپنے گھر کے سامنے طبل بجائیں تاکہ اس مظہر سیادت میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا خلیفہ کا شریک نہ ہونے پائے۔ نظام الوزارة فی الدولة العباسیة محمد سفر الزہرانی کی تحریر کردہ کتاب ص۲۶ جو کہ ابن جوزی ج۷، ص۹۲ المنتظم نامی کتاب سے منقول ہے۔
(۲۶)فقہ السنہ ج۱، ص۲۷۲، مؤلف شعبی کے بقول اس طرح نقل کرتے ہیں: جب معاویہ کا پیٹ بڑا ہوگیا تو وہ نماز جمعہ کے خطبہ کو کھڑے ہونے کے بدلہ بیٹھ کر دینے لگا۔ اس مطلب کو کتاب وسائل الشیعة ج۵، ص۳۱، حدیث۱، سے مقایسہ کریں۔
(۲۷)امامت کے سلسلہ میں فاسق اور بدعتگذار کی امامت اور اس مسئلہ میں مذاہب اربعہ کے نظریات کے لئے الفقہ علی المذاہب الاربعة نامی کتاب کی ج۱، ص۴۲۹ ملاحظہ کریں۔
(۲۸)وسائل الشیعہ ج۵، فاسق کی اقتدا کی حرمت کے باب میں ملاحظہ کریں، ص۳۹۲، ۳۹۵۔
(۲۹)وسائل الشیعة ج۵، ص۳۸۱، ۳۸۲۔
(۳۰)بطور نمونہ الفصل فی الملل والاھواء والنحل، ج۴، ص۸۷، نیز اعلام الموقعین ج۱، ص۴۸۔
(۳۱)البدر الزاہر، ص۷، ۸ نیز من العقیدة الی الثورة، ج۱، ص۲۲و ۲۳، جس میں حاکم کی طرف سے نماز جمعہ و جماعت کے امام کے منصوب ہونے کی کیفیت اور ان دونوں میں متقابل روابط کی نقادانہ انداز میں تحقیق و بررسی کی گئی ہے۔
(۳۲)الائمة الاربعة ج۴، ص۱۱۹، ۱۲۰۔
(۳۳)المحلی ج۴، ص۲۱۴۔
(۳۴)المحلی ج۴، ص۲۱۳۔
(۲۵)سابق حوالہ ص۲۱۴۔
(۳۶)معجم الفقہی الحنبلی الجزء الثانی، ص۵۷۵ نیز الابانة عن اصول الدیانة ص۲۳۔
(۳۷)وسائل الشیعة ج۵، ص۳۷۲ حدیث۹۔
( ۳۸)اموی خلفاء اور ان کے عمال کا دین سے بے گانہ ہونے اور دوری کا اندازہ اس نمونہ سے ہوسکتا ہے: بعض اموی خلفاء کی جانب سے طارق مدینہ کا حاکم تھا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے کھانا منگوایا اور اسے منبر رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم پر تناول کیا، اس کے کھانے میں ایک مغزدار ہڈی تھی، وہ ان ہڈیوں کو منبر رسول پر توڑتا اور اس کے مغز کو کھاتا۔ عیون الاخبار ج۲، ص۴۶۔ جب مدینہ کے حاکم کا یہ حال ہے تو پھر دوسرے شہروں میں منصوب والیوں اور حکام کا کیا حال ہوسکتا ہے۔
(۳۹)یہ شرکت نہ تنہا حاکم کی مشروعیت کو قبول کرنے کے معنی میں تھی بلکہ حاکم سے مربوط تمام امور کو قانونی قبول کرنے کے معنی میں بھی تھی۔ بطور نمونہ ''مدینہ کے حاکم سعید ابن مسیب کے نظریہ کو وفیات الاعیان ج۲، ص۱۱۷ پر ملاحظہ کریں۔
(۴۰)المصنف، ج۲، ص۱۴۸۔
(۴۱)السیاسة الشریعة ص۴۲۔
(۴۲)آپ اسی سلسلہ میں دین کے بھیس میں دنیا طلبی اور مفاد پرستی کے نمونہ مشاہدہ کرسکتے ہیں جو صدر اعظم سلطان سلیمان قانونی، لطفی پاشا کو امامت و خلافت کے درجہ تک لے جانا چاہتا تھا: وہ اپنے رسالہ خلاص الامة فی معرفة الائمة میں سلطان سلیمان کو ان القاب سے نوازتا ہے: امام زمان ِ، رسول خدا کا جانشین، اسلام کا مدافع، دین خدا کا قدرت مند حامی، مسلمانوں کا سلطان، کافروں کے منھ میں لگام لگانے والا، عادل پیش نماز، شریعت کے قوانین برقرار کرنے والا، نیز ایسا شخص جو برکت الہی اور اسکی سعادت سے بہرہ مند ہے اور خدا کے الطاف اور اس کی بے کراں عنایتیں اسکے ساتھ ساتھ ہیں، یہ تمام باتیں اس دنیاوی موقعیت کی تقویت تحکیم کے لئے دین سے فائدہ اُٹھانے کے عنوان سے ہے۔ ''مجلہ دانشگاہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشھد، شمارہ مسلسل ۵۷، ۲۵۸، ص۷۔۸۔
(۴۳)الاسلام بین العلماء و الحکام، ص۱۳۳، ۱۳۸۔
(۴۴)المحلی، ج۴، ص۲۱۴۔
(۴۵)۔فقہ السنة، ج۱، ص۲۰۹، ۲۱۰۔
(۴۶)المحلی، ج۴، ص۲۱۴۔
(۴۷)وسائل الشیعة، ج۵، ص۳۸۳ ،حدیث۹۔
اس مطلب کی تائید مستدرک وسائل الشیعة ج۶، ص۴۵۶۔ اور العواصم والقواصم ج۳، ص۴۲، ۲۴۴۔ جس میں اہل سنت کے تمام اسناد ذکر کئے گئے ہیں دریافت کریں۔
(۴۸)من العقیدة الی الثورة۔ ج۱، ص۲۶۔
(۴۹)الانتفاضات الشیعة عبر التاریخ، ہاشم معروف الحسینی، ص۸۰۱و ۱۰۹، جو کتاب وعاظ السلاطین سے منقول ہے۔ جس میں سنیوں کی پائداری اور باقی رہنے کو بدون تعصب بیان کیا گیا ہے رجوع کریں، ۱۰۹و ۱۱۰۔
(۵۰)بطور نمونہ کنزالعمال، ج۷، ص۵۹۱، ۵۹۷ ملاحظہ ہو۔
(۵۱)الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۱۹۷، ۲۰۶ نیز فاتحة العلوم ص۱۱ اسی کتاب سے ملاحظہ ہو۔
(۵۲)السیاسة الشرعیة، ص۲۳۔
(۵۳)ادب الدنیا والدین، ماوردی، ص۱۱۵۔
(۵۴)مقدمہ ابن خلدون، ص۱۸۰۔
(۵۵)طول تاریخ میں مسلمانوں اور عیسائیوں اوران کی ایک دوسرے کے دین کی تفسیر کے سلسلہ میں رقابت جو آج تک باقی ہے، اطلاع کی خاطر ''نقد تؤطئہ کتاب آیات شیطانی اور مخصوصا The Legacy Islam pp,۹-۶۲ اس کشمکش کا آج تک باقی رہنا اور مسلمانوں کی تفسیر کی بہ نسبت انتقادکے لئے ملاحظہ ہو ''پیامبر و فرعون ص۱۸۵، ۲۰۲۰ ''اسلام در جہان معاصر'' ص۱۰۶۔ ۱۲۰۔
(۵۶)الامام زید محمد ابوھرہ، ص۱۰۹، ۱۰۸۔
(۵۷)چونکہ عیسائیت اسلام کو گذشتہ ایام میں ایک الہی مذہب کے عنوان سے قبول نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافروں کے زمرہ میں سمجھتے تھیاور ان کے لئے دینی اور غیر دینی کسی بھی قسم کے حقوق کے قائل بھی نہیں تھے۔ ایک اندلس کے عیسائی کے بقول جو مسلمان ہوا تھا کہ اس نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جو کہ، ۸۲۳، ق، ۱۴۲۰، میں لکھی تھی یوں بیان کرتا ہے کہ: اندلس کے بنونیہ نامی شہر میں ایک مسلمان جو اپنی جان بچانے اور اپنے وطن میں رہنے پر مجبور ہوگیا لہٰذا اس نے اپنے اسلام کو مخفی رکھا اور پادریوں کی جماعت میں شامل ہوگیا تھا اور خود کو نیقولا اور مرتیل کہتا تھا۔ ''مجلہ دانشگاہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشہد، شمارہ مسلسل ۵۷، ۵۸، ص۹
مسیحیت نے جب ۱۹۵۰ء کے درمیان اپنا دوسرا اجلاس رکھا تو اس میں اسلام کو ایک الہی مذہب کے عنوان سے قبول کرلیا
The Conciliar and Post Conciliar Documents,PP,۷۳۸-۴۲
Ziauddin Sardar, Islamic Futures
لیکن آج بھی اسلام کے خلاف اپنی کینہ توزیوں سے دست بردار نہیں ہوئے ہیں، بطور نمونہ، جوزف کراف کے مقالہ کی طرف جو واشنگٹن پوسٹ ۱۹مئی ۱۹۸۱ میں ''کون پاپ کو قتل کرناچاہ رہاتھا'' کے عنوان کے تحت شائع ہوا تھا ملاحظہ ہو۔
اسی طرح JohnLoffin, The Dagger of Islam اس دشمنی کا سبب معلوم کرنے کے لئے آپ رجوع کریںاس کی طرف
Daniel; Islam and the west:The Making of an Image ,
ملاحظہ ہو PP,۱-۱۴
(۵۸)اسی مجلہ کا شمارہ، ۵۶، ص۷۵۳ ملاحظہ ہو۔
(۵۹)سابق حوالہ، ص۷۵۳۔
(۶۰)سابق مجلہ، شمارہ، ۵۷۔ ۵۸ ص۱۰ اور ۱۱۔
(۶۱)واقعیت تو یہ ہے کہ شہروں اور مخصوصا سرحدوں کی امنیت خلیفہ یا سلطان کی قدرت و طاقت کے ذریعہ پہلے زمانہ میں ایک اہم مسئلہ تھا جو بہت سے اہل سنت علما کو ان کی حمایت اور ان کی قدرت کو بڑھانے اور اسے قوت پہونچانے کے لئے ایک دینی وظیفہ کے عنوان سے اُبھارا۔ اس لئے ان کی نظر میں سلطان کی قدرت اور اس کی شان وشوکت اسلام اور مسلمین کی قدرت تھی جو اسلام کے دشمنوں غیروں اور کفار کے دخل و تصرف کرنے سے مانع تھی۔
ہارون جیسے فرد کی موقعیت اور شان و شوکت کا سبب یہی ایک عامل تھا اگرچہ وہ ایک ظالم اور جابر شخص تھا کہ جس کے ظلم کی داستان کا ہزار و یک شب والی کتاب میں ایک گوشہ ہے بیان کی گئی ہے، بلکہ بہت سارے علما اہل سنت کی نظر میں وہ مسلمانوںکی عظمت و قدرت اور قہر و سطوت کا مظہر تھا، جس کی وجہ سے ہر ایک اس کا احترام کرتا تھا اور اس کی تکریم بجالاتا تھا۔ وہ شہنشاہ روم سے مقابلہ کی طاقت رکھتا تھا۔ اور اسے اطاعت کے لئے مجبور کرسکتا تھا۔ اس واقعیت کو درج ذیل داستان سے بخوبی معلوم کیا جاسکتا ہے۔
۱۸۷ ق میں شہنشاہ روم نے ہارون کے نام ایک خط لکھا اور جو عہد نامہ روم اور ہارون کے درمیان منعقد ہوا تھا اسے فسخ کردیا، یہ عہدنامہ گذشتہ حاکم جو کہ ایک عورت تھی اس نے باندھا تھا، اس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ اس عہدنامہ کے مطابق جو اسکے سلف کے ضعف و حماقت بلکہ عورتوں کی خصلت میں سے ہے اب تک جو کچھ بعنوان خراج دیا ہے اسے لوٹادیاجائے یا پھر جنگ کے لئے آمادہ ہوجائے۔ جب ہارون نے یہ خط پڑھا نہایت غضبناک ہوا کہ کسی میں اتنی جرأت نہ تھی جو اس کی آنکھوں کی طرف نظر اٹھاکردیکھتا یا اس سے بات کرتا، فوراً قلم و دوات منگوایا اور کہا کہ اسی خط کی پشت پر لکھو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہارون امیر المؤمنین کی جانب سے نقنور سگ روم کی نام! اے کافر عورت کے بچے! میں نے تیرا خط پڑھا، پس اس کا جواب ایسا ہوگا کہ تو اسے ضرور دیکھے گا نہ وہ ہوگا جو تو سنے گا۔ اور اسی روز اپنے لشکر کے ساتھ روم پر چڑھائی کردی اور ایک گھمسان کی جنگ کے بعد اس پر غالب آگیا اور شہنشاہ روم کو شکست دے کر اس پر اپنا خراج معین کردیا۔ تاریخ الخلفائ، ص۲۸۸۔ ذکر محاسن کے باب میں اور بلکہ اس کے فضائل کہ جو اس وقت کے علما کے تصورات کی عکاسی کرتے ہیں، اطلاع کی خاطر رجوع کریں سابق حوالہ کی طرف، ص۲۸۳، ۲۹۷۔
اسی طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک روز ہارون قرآن پڑھ رہا تھا کہ اس آیت پر پہنچا ''کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، کیا یہ نہریں میرے پیروں کے نیچے جاری نہیں ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے۔ فرعون کے یہ جملات دیکھتے ہی اس نے یہ جملہ کہ کہا اس کم ہمت اور خسیس انسان پر لعنت ہو جو ملک مصر میں خدائی کا دعوی کرتا ہے، لہذا میں اسی مصر کو ایک ایسے والی کے حوالہ کروں گا جس نے میری خدمت ہر ایک سے کم کی ہو لہذا اس نے حمام کے مالک خصیب کو بلایا اور مصر کی امارت اس کے حوالہ کردی، خلعت و منشور کے ساتھ اسے مصر کی جانب روانہ کردیا اور خصیب ایک ایسا شخص تھا جس میں مصر کی امارت کی اہلیت تھی نیز اس کے دماغ میں نخوت اور ہمیت کا غبار تھا۔ ''اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة، ص۳۲۰، مضحکہ خیز تو یہ ہے کہ مؤلف ہارون کے اس عمل کو اس کی طبیعت کی بلندی اور عظمت شان تصور کرتا ہے لہٰذا ایسے طرز تفکر کا سابقہ جس کا اثر کافی عمیق اور گہرا ہو طولانی رہا ہے۔
(۶۲)الائمة الاربعة، ج۴، ص۱۱۹۔
(۶۳)اغراض السیاسة فی اعراض السیاسة، ص۲۸۵۔
(۶۴)الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۱۹۸، ۱۹۹۔
(۶۵)المواقف فی علم الکلام، ۳۹۶، ۳۹۷۔
(۶۶)اس مطلب کی وضاحت کے لئے رجوع کیا جائے مصطفی شکری کی صریح تنقیدوں کی طرف جسے کتاب ''پیغمبر و فرعون'' میں ذکر کیا ہے، ص۸۷، ۹۰۔ نیز عالمانہ تنقید کے لئے مراجعہ کریں حسن حنفی کی کتاب من العقیدة الی الثورة کے مقدمہ کی طرف، ج۱، ص۲۰، ۳۲۔
(۶۷)الاحکام السلطانیة ابویعلی، ص۲۱؛ الخلافة والامامة، ص۳۰۰۔
(۶۸)ایام المحنة میں امام حنبل اور ان کے ہم فکر ساتھیوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں، ان کے متعلق معلومات کے لئے الائمة الاربعة ج۴، ص۱۴۰۔ ۱۸۰ نیز الخلافة والامامة، ۳۰۰۔ ۳۰۹ کی طرف رجوع کریں بلکہ حکام کی طرف سے علما نے جو سختیاں جھیلی ہیں ان کے متعلق معلومات کے لئے ہر ایک سے بہتر یہ ہے کہ کتاب الاسلام بین العلماء والحکام ص۱۲۹، ۲۱۴، نیز کتاب مناقب امام احمد ابن حنبل ابن جوزی، ص۳۹۷، ۴۲۰ کی طرف رجوع کریں۔
(۶۹)اگر یہ مان لیا جائے کہ نظام کی حفاظت در اصل حاکم کی حفاظت تنہا مصالح و مفاسد کی تشخیص دینے کا ضابطہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کی حفاظت کے بہانہ دین اور عدالت سے انحراف اس درجہ بڑھ جائے کہ دختر رسولصلىاللهعليهوآلهوسلم کی بے حرمتی بھی کی جائے ''حضرت زہراء علیہا السلام کے مکان پر حملہ کیا گیا اور آپ کی بے حرمتی کی گئی، یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ نظام اسلام باقی رہے اور امر خلافت میں کوئی خلل واقع نہ ہو نیز کسی میں خلیفہ کی مخالفت کی جرأت نہ رہے اور مسلمانوں کے اتحاد کو ٹھیس نہ پہنچے۔'' شرح ابن ابی الحدید، ج۲۰، ص۱۶، اس نمونہ کے علاوہ دوسرے نمونے بھی بعد والے صفحات میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں، ان خلفاء کی تنقید کے باب میں جو خلق قرآن کے قائل تھے، العواصم من القواصم، ۲۴۹، ۲۵۱ ملاحظہ ہو۔
(۷۰)الخلافة والامامة، ص۳۰۱۔
(۷۱)یزید اور اس کے درباری علمائے سوء نیز ان کے اخلاف نے بعد کے زمانے میں امام حسین اور ان کے چاہنے والوں کو نے یہ کہہ کر متہم کیا کہ یہ لوگ دین سے خارج ہوگئے ہیں اور امام و خلیفہ کی مخالفت کے لئے قیام کیا ہے، لہذا ان سے جنگ کرنا چاہئے اور ان کا صفایا کردینا چاہئے۔ تاریخ طبری ص۳۴۲ پر ملاحظہ ہو
(۷۲)اعلام الموقعین، ج۳، ص۳ اور ۴۔
(۷۳)بطور نمونہ کتاب ''ہند و پاکستان'' ص۳۸، ۳۷ ملاحظہ ہو۔
(۷۴)بطور نمونہ رشید رضا کا مشہور و معروف خطبہ غرا ملاحظہ ہو جو کہ میدان منی میں شریف حسین کی خلافت سے متعلق ثورة العرب ضد الاتراک ص۳۲۰۔ ۳۲۶ نیز اسی جگہ رشید رضا کی تقریر کے بعد شریف حسین کی تقریر کا مطالعہ کریں، ص۳۴۲، نیز کتاب العواصم من القواصم پر محب الدین الخطیب کے مقدمہ کو ملاحظہ کریں جس میں اس نے اموی خلفاء کی صرف اس وجہ سے تعریف کی ہے کہ انھوں نے اپنی قدرت اور شأن و شوکت کے سہارے اسلام کی حکومت کو پھیلانے میں کوششیں کی تھیں (ص۳) اور کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ۲۹۹، ۳۱۹۔
(۷۵)بہترین نمونوں میں سے ایک نمونہ وہ خط ہے جسے مصر کے مشہور مجاہد اور مصنف زینب الغزالی نے یاسر عرفات کے نام لکھا تھا، اس وقت کہ جب تونس میں اسرائیلی جہازوں نے فلسطین کی آزادی بخش گروہ کے کیمپ پر حمل کیا تھا۔
(۷۶)اسلام میں مختلف فرقوںکے درمیان خونین جنگوں کی فہرست بڑی طولانی ہے،اور اس میدان میں حنابلہ کا کردار ہر ایک سے زیادہ رہا ہے،یہ صرف اس وجہ سے تھاکہ ان کے اعتقادات عوام پسند، خشک اور ایسے تشدد آمیز ذہنی دباؤ اور دفاع کرنے والے جس نے ان عقائد کو جنم دیا یہاں تک کہ اشاعرہ جو اپنے تعصب میں مشہور و معروف ہیں وہ بھی ان لوگوں کی شیطنت، خشک مزاجی اور قساوت و سنگدلی سے گلہ مند رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک زمانہ میں چند اشعری علما اپنے زمانہ کے فرقہ اشعری کے رئیس ابو القاسم قشیری کی حمایت میں خواجہ نظام الملک کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں حنابلہ کی شرارتوں کی شکایت کرتے ہیں اور اس سے اشاعرہ کی بہ نسبت حمایت کی خواہش کرتے ہیں،لیکن تعجب تو یہ ہے کہ یہ خط اس وقت لکھا گیا ہے کہ جب اشاعرہ اور شافعی کا بول بالا تھا۔ اس خط کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کس حد تک حنا بلہ اپنے علاوہ مذہب والوں پر سختی کرتے تھے۔''
بغداد میں عوام الناس اور کچھ حشویہ گروہ کے لوگ اور چند اوباش اور پست فطرت لوگوں نے جو اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے ایسی ایسی بدعتیں اور ایسی بدکرداریاں انجام دیں کہ جسے ایک ملحد بھی انجام نہیں دے سکتا تھا چہ جائیکہ کوئی موحد انجام دے اور خدا کی طرف ہر اس چیز کی نسبت دی کہ جس سے وہ عاری ہے خواہ وہ نقص ہو یا حدوث و تشبیہات۔ ان لوگوں نے گذشتہ اماموں کی بے حرمتی کی، دینداروں اور اہل حق کو طعنہ دیئے۔ مساجد، بازار، محافل اور خلوت و جلوت میں ان پر لعنت کی۔''
الملل النحل، استاد سبحانی، ص۲۷۹۔ ۲۸۲ ایسی سیکڑوں داستانوں کو طبقات الحنابلہ نامی کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے جسے خود انھوں نے لکھا ہے اور جس میں انھوں نے اپنے علما کی سوانح حیات اور عظمت و شان بیان کی ہیاور یہ داستان ان کی شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کا ایک نمونہ ہے: طبرستان سے بغداد کی طرف طبری کے دوسرے سفر میں ایک روز طبری مسجد جامع میں پہنچ گئے، وہاں حنبلیوں نے امام احمد ابن حنبل اور خد ا کے عرش پر بیٹھنے کے سلسلہ میں وارد ہونے والی روایت کے بارے میں طبری سے سوال کرلیا تو ا س نے جواب دیا کہ احمد ابن حنبل کی مخالفت کو اہمیت نہیں دی جاسکتی اور مشابہ بھی نہیں ہے تو حنبل نے کہا: لیکن علما نے اپنے اختلافات ہیں اسے بیان کیا ہے، تو طبری نے کہا کہ نہ میں نے اسے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے اصحاب میں کسی سے سنا ہے جو کہ معتمد شخص رہاہو، لیکن خدا کا عرش پر بیٹھنا محال ہے۔
حنبلی اور اہل حدیث نے جیسے ہی طبری کا نظریہ سنا، اس پر حملہ آور ہوئے اور اپنے قلم و دوات اس کی طرف پھینک دیئے، طبری نے بھاگ کر اپنے گھر میں پناہ لی، چونکہ حنبلیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی لہذا ان لوگوں نے اس کے گھرکے سامنے اس قدر پتھر برسائے کہ پتھروں کا ایک ٹیلہ ہوگیا ہے۔ بغداد کے پولیس افسر نازوک نے اسی وقت ہزاروں کی فوج لیکر وہاں پہنچ گیا اور طبری کو حنبلیوں کے شر سے نجات دی اور پورے دن وہیں ٹھہرا رہا، اس کے گھر سے پتھروں کو اٹھانے کا حکم دیا، وہابیان، ص۲۷ اسی طرح آپ ملاحظہ کریں، ساتویں صدی کے مشہور مجاہد اورعظیم شخصیت عز ابن عبدالسلام کی مصیبتوں کو کہ جسے حنبلیوں کی جانب سے متحمل ہوئے تھے الاسلام بین العلماء و الحکام ص۱۹۲۔
(۷۷)یہ بالکل شیعوں کے آئمہ کی ضد میں اپنایا گیا ہے، ا ن لوگوں کی نظر میں عوام کو فاسد بنانے میں نظام حاکم کا کوئی نقش نہیں ہے اسی وجہ سے وہ لوگ جس طرح اجتماع کی اصلاح کے قائل تھے اسی طرح ہر فرد کی اصلاح کے قائل تھے۔ یہا ں تک کہ وہ موارد جس میںمسیر حق سے انحراف ہیں ذاتی شیطنت کے علاوہ دوسرے عوامل دخیل تھے اور ایسی خصوصیت کے ساتھ قدرت کسی فرد یا نظام کے ہاتھ میں تھی ایسے افراد سے مقابلہ کے لئے کوئی خاص عکس العمل کا اظہار نہیں کرتے جیساکہ امام علیـ نے اپنے بعد خوارج کے سلسلہ میں یہ وصیت کی: میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا اس لئے کہ جو حق کی جستجو میں ہو اور بھٹک جائے، اس شخص کے جیسا نہیں ہے کہ جو باطل کی تلاش میں ہو اور اسے حاصل کرلے۔ خطبہ، ۶۱ نہج البلاغة، تصحیح صبحی صالحی۔
دین اسلام اپنی ابتداء سے ہی لوگوںکو اپنی خدمت میں لینے مخصوصا جوانوں کو اپنی خدمت میں لینے میں کامیاب رہا ہے، کسی بھی دین کا ایسی خصوصیات سے سرفراز ہونا انسانی خصوصیات سے ہم آہنگی انسان کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا اثر اور جاذبہ ہے جو ابھی تک باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اس سلسلہ میں حجازیوں کے سامنے ابوحمزہ خارجی کی تقریر ملاحظہ کی جاسکتی ہے کہ جس پر اس کے چاہنے والوں کے جوان ہونے کی وجہ سے تنقید کی گئی تھی۔ ''... اے اہل حجاز! کیا تم میرے چاہنے والوں کے جوان ہونے پر مجھے ملامت کرتے ہو، کیا ایسا نہیں تھا کہ آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت کے اصحاب جوان تھے۔ خدا کی قسم یہ اپنی جوانی میں بھی بزرگ ہیں، جن کی آنکھیں شر سے محفوظ اور کان امر باطل کے سننے سے سنگین ہیں، جو شدت عبادت اور زندہ داری کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہوچکے ہیں، خدا رات کی تاریکیوں میں ان پر نظر کرتا ہے اس حال میں کہ ان کی پشت قرآن کی طرف جھکی ہوئی ہے، جب ان کی نگاہیں قرآن کی ان آیات پر پڑتی ہیں کہ جن میں بہشت کی خبر دی گئی ہے تو شدت شوق سے ان کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔ اور جب ان آیتوں سے گذرتے ہیں کہ جن میں جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے تو شدت خوف سے چیخ مارتے ہیں گویا وہ جہنم کی وحشتناک آواز کو سن رہے ہوں... جنگ کے ہولناک ترین لحظات میں لشکر میں پیش پیش افراد جب موت کے خوف سینہ سپر شمشیر کی چمکاور نیزہ کی کھنک دیکھ کر خوفزدہ ہوجاتے ہیں تو دشمن کے خوف کو خدا کے ترس کے مقابلہ میں اسے اپنا کھلونا بنا لیتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے حالات میں برابر آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اپنے ہی خون سے اپنی داڑھیوں میں خضاب لگا لیتے ہیں، درندے ان کی جسموں کی طرف دوڑتے ہیں اور پرندے ان کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں، کتنی آنکھیں ہیں جو شب کی تاریکیوں میں خوف خدا میں گریاں ہوئیں وہ پرندوں کی چونچ کا نشانہ بن گئیں؟ اور وہ ہاتھ جو رات کی تاریکی میں سجدوں کے طولانی ہونے کہ وجہ سے زمین پر پڑے رہے، وہ گٹے سے جدا ہوگئے؟...'' البیان والتبیین، ج۲، ۱۰۲، ۱۰۳، اس نے اپنے جوان پیروکاروں کی جو تعریف کی ہے کہ وہ دین کی سربلندی کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتے اور جان و دل سے اس کی راہ میں فداکاری کے لئے آمادہ ہیں، یہ توصیفات ہر زمانہ میں صحیح ہیں۔ بطور نمونہ مجلہ النذیر عضو اخوان لمسلمین سوریہ کے مختلف شماروں کی طرف نیز ان کتابوں کا بھی مطالعہ کریں کہ جن میں اسلام کے فدائیوں کے حالات زندگی بیان کئے گئے ہیں اسی طرح ''پیغمبر و فرعون۔'' نامی کتاب بھی ملاحظہ ہو
(۷۸)مزید وضاحت کے لئے On Being a Christian : مخصوصا ص۳۱۔ ۳۴ ملاحظہ ہو
(۸۹)گیب ان خصوصیات کی درستگی کا سرچشمہ اسلام کو جانتا ہے ''اسلام کا اعتقادی نظام محکم، مثبت اور مؤکد ایک مجموعہ ہے اور یہ تمام خصوصیات قرآن، حدیثاور سنت و شریعت کی مرہون منت ہیں
(۸۰)سعودی اخوان کی اخلاقی اور دینی اور ذہنی خصوصیات اور ان کے اقدام کے سلسلہ میں تحقیق کرنا بہتر ہے جو ایک بہترین نمونہ ہے لہذا رجوع کریں کتان ''وہابیان'' ص۴۴۶۔ ۴۵۹ مثلا حافظ وھبہ جو خود نزدیک سے انھیں جانتا ہے اور ان کی جنگوں کا چشم دید گواہ ہے وہ ان کے سلسلہ میں کہتا ہے: اخوان موت سے نہیں ڈرتے۔ شہادت اور خدا سے ملاقات کے لئے موت کے منھ میں پہنچ جاتے ہیں اور جب ایک ماں اپنے بیٹے کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے جاؤ کہ خدا ہم دونوں کو بہشت میں ایک دوسرے سے دوبارہ ملاقات کا موقع دے، جب وہ اپنے دشمن کی طرف حملہ کرتے ہیں تو ان کا شعار (ایاک نعبد وایاک نستعین) ہوتا ہے، میں خود ان کی بعض جنگوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں، میں نے خود دیکھا کہ وہ کس طرح میدان جنگ کی طرف جاتے تھے، دشمن کی صفوف کو درہم برہم کرتے ہوئے انھیں شکست دینے اور انھیں قتل کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتے، ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی شفقت و مہربانی کا نرم گوشہ نہیں ہے ان کے ہاتھوں سے کوئی بچ نہیں سکتا جہاں بھی وہ پہنچ جائیں موت کے قاصد ہیں'' ''وہابیان'' ص۴۵۲ جو کتاب العرب فی القرن العشرین ص۳۱۴، سے منقول ہے اور جان فیلبی ان کے سلسلہ میں اس طرح بیان کرتا ہے: اخوان نے قبائل عرب سے قتل و غارت گری، عیاشی اور رہزنی کو ختم کردیا اور وہ لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی آخرت کے لئے کرتے تھے۔ اپنے علاوہ ہر ایک کو بلکہ بقیہ تمام اسلامی فرقوں کو مشرک اور بت پرست سمجھتے تھے۔ ''وہابیان'' ص۴۴۹ جو تاریخ نجد کے ص۳۰۵۔ ۳۰۸ سے منقول ہے۔
(۸۱)حنفیوں اور شافعیوں کے درمیان رقابت جو خونین جنگوں کا باعث بنی، درج ذیل داستان کو پڑھیں: جسے ہندو شاہ نقل کرتا ہے: امام اعظم شافعی کے مذہب کا پابند تھا اور سلطان ملک شاہ نے اصفہان کے محلہ کران میں ایک علمی مدرسہ کی بنیاد رکھی، جب دستور لکھنا چاہا کہ اس مدرسہ میں کون رہے گا تو سلطان سے سوال کیاتو اس نے جواب دیا کہ اگرچہ میں ایک حنفی ہوں لیکن میں نے اسے خدا کے لئے بنایا ہے لہذا کسی ایک فرقہ سے مخصوص نہیں کرسکتا۔ کسی قوم سے مخصوص کرنا اور کسی کو محروم کردینا معقول نہیں ہے لہذا لکھ دو کہ اس میں دونوں امام کے اصحاب رہیں اور جب لکھنا چاہا تو چونکہ سلطان حنفی تھا لہذا امام حنیفہ کا نام امام شافعی کے نام سے پہلے لکھنا چاہا تو خواجہ نے منع کردیا اور ایک مدت تک حالت ایسی ہی رہی آخرکار یہ طے پایا وقف علی اصحاب الامامین الائمة صدری الاسلام مجلہ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشہد، شمارہ، ۵۶ ص۷۴۲ جو کتاب تجارب السلف ص۲۷۷۔ ۲۷۸ سے منقول ہے۔
(۸۲)شافعیوں اور حنفیوں، ماتردیوں اور اشعریوں، اہل سنت اور شیعہ و معتزلی کے درمیان شدید تعصب مسلمانوں کی کمزوری کا ایک عظیم سبب ہے۔ جو بھی مقدسی کے سفرنامہ اور یاقوت کی معجم البلدان کا مطالعہ کرے گا اسے معلوم ہوجائے گا کہ یہ تعصبات کس قدر قتل و غارتگری، فتنہ و فساد، ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ کا باعث بنے ہیں۔ ظہر الاسلام، ۴، ص۱۰۲
۳۵۰ھ میں ایک طرف اہل سنت اور سوڈانی سپاہیوں میں تو دوسری طرف شیعوں میں ایک عظیم اختلاف اور کشمکش پیدا ہوئی۔ سوڈانی سپاہی سڑکوں پر جسے بھی پاتے اس سے سوال کرتے کہ تمھارا ماموں کون ہے اگر وہ جواب میں معاویہ نہیں کہتا تو اس کی بری طرح ناقابل تحمل پٹائی کرتے اور اسے گالم گلوج سے نوازتے بلکہ کبھی کبھی یہی چیز اس کی موت کا سبب بن جاتی تھی۔ اسی طرح ۴۰۸، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۹ ق، میں وحشتناک فتنہ اٹھے اور دونوں گروہوں سے ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ الفکر السیاسی الشیعی، ص۲۸۰، اس کے مزید نمونوں کے حصول کے لئے اسی کتاب کا ص۲۷۹، ۳۸۱ نیز کتاب اسلام بلا مذاہب ص۲۸۵۔ ۲۸۸ ملاحظہ ہو۔
(۸۳)تمام اسلامی فرقوں میں شیعہ ہر ایک سے زیادہ اپنے دشمنوں کی جانب سے حملوں کا شکار رہا۔ اور اس کے بھی مختلف اسباب تھے منجملہ یہ کہ ابتداء اسلام میں مسلمان ائمہ اطہار کی جانب اہل بیت پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم ہونے کی وجہ سے ان سے نزدیک اور انھیں اپنا محبوب بنائے ہوئے تھے جو عباسیوں اور امویوں کے اقتدار کے لئے ایک خطرہ تھا جس کی بنیاد پر وہ کسی بھی آزار و اذیت سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ کتاب اسلام بلامذاہب' ص۲۸۵۔
(۸۴)اکثر وہ لوگ جو ہندوستان، افریقا اور دور دراز شرقی ممالک میں شیعوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے اور اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ اسی فکر کے زیراثر ہیں۔ وہ اپنی گردنوں پر اسلام کی نسبت ذمہ داری کو پورا کرنے کی فکر میں ہیں لہذا جان کی حد تک اسلام اور اس کی سربلندی کی خاطر سعی و تلاش کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے پاس اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے نیز جہالت کی وجہ سے وہابیوں کی زہریلی اور جھوٹ و فساد سے مملو شیعوں کے خلاف تبلیغ کی زد میں ہیں لہذا شیعوں سے مقابلہ کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان سے جنگ کو اپنا ہدف اور اسے بطور صحیح انجام دینے کی کوشش میں ہیں پس انھیں ان وہابیوں سے جدا کرنا ہوگا جو اپنے منافع کی خاطر ایسا اقدام کرتے ہیں، ''افریقا: میراث گذشتہ و موقعیت آئندہ'' نامی کتاب ص۱۱۲، ۱۱۴ ملاحظہ ہو۔
(۸۵)۱۴۳ھ میں علماء اسلام نے حدیث و فقہ اور تفسیر کی کتابیں لکھنا شروع کیں، اسی دور میں ابن جریح نے مکہ میں لکھا، مالک نے مدینہ میں موطأ تحریر کی اور اوزاعی نے شام میں اسی طرح ابن ابی عروبہ اور حماد ابن سلمہ اور دوسروں نے بصرہ میں لکھنا شروع کیا، معمر یمن میں، شفیان ثوری کوفہ میں، ابن اسحاق نے کتاب مغازی تحریر کیاور ابوحنیفہ نے فقہ و رأی نامی کتابیں لکھیں اور مختلف علوم کی تدوین اور نشر و اشاعت عام ہوگئی اس طرح مختلف کتابیں عربی علوم، لغت، تاریخ، وغیرہ کے سلسلہ میں بے شمار وجود میں آئیں۔ اس دور سے پہلے علما اپنے حافظہ کے سہارے مطالب بیان فرماتے تھے اور غیر تدوین شدہ صحیح صحیفوں سے نقل کرتے تھے۔ تاریخ خلفائ، ص۲۶۱۔
اس بات کی تحقیق کرنے کے لئے کہ صدر اسلام میں احادیث بنوی کے نہ لکھنے میں کن عوامل کا ہاتھ تھا، کتاب الملل والنحل ص۵۱۔ ۷۱ نیز کتاب اضواء علی السنة المحمدیة ص۲۶۱، ملاحظہ کرسکتے ہیں اور جب یہ دور ختم ہوگیا تو اس کے بعد کے علما کتابیں لکھنے پر چندان مائل نہیں تھے لیکن جب ہشام نے زہری کو لکھنے پر مجبور کیا تو اس کے بعد سے علما نے قلم سنبھا لا اور لکھنا شروع کیا۔ سابق حوالہ ص۲۶۲۔
(۸۶)مقدمہ وسائل الشیعہ ج۱، ص۳۵، ۴۹ اور عباسیوں کی دینی سیاست کے سلسلہ میں مؤسسہ آل البیت سے چھپی کتاب کی طرف رجوع کریں۔
Goldziher ,Muslim Studies , pp ۷۵-۷۷
(۸۷)اوائل اسلام میں عباسیوں کے ابتدائی ادوار میں غیر عرب مخصوصا ایرانیوں کے نفوذ کا اس روایت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے.. منصور نے عید نوروز کے دن امام موسی بن جعفر ـ سے تقاضا کیا. کہ عمومی ملاقات کے لئے تشریف رکھیں اور زیارت کرنے والوں کے تحفوں کو قبول فرمائیں، لیکن امام نے انکار کردیا تو منصور نے جواب میں کہا کہ یہ رسم سیاسی مصلحت اور لشکریوں کو خوش آمد کہنے کے لئے ہے۔ جواہر الکلام ج۵، ص۴۲
(۸۸)اس آخری صدی میں اہل سنت کے تفکرات بالخصوص وہ تفکر جو علما اور سلاطین و خلفاء سے مربوط تھے، شدت سے تنقید کا نشانہ بنے ہیں اور تنقید کرنے والے مختلف گروہوں اور جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف اسباب کی بنیاد پر انھیں اپنی تنقیدوں کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض دینی علما ہیں جیسے شیخ کُشک، خالد محمد خالداور اخوان المسلمین سے وابستہ دوسرے علما دین مخصوصا ًسید قطب،ان لوگوں کے علاوہ بقیہ مخالف جماعتیں اور آزاد فکر حضرات ہیں، ان میں سے بعض کی تنقیدوں جو پہلے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اصلاحی، سنوارنے والی اور ہمدردانہ ہیں۔ لیکن دورے گروہ کی تنقیدیں تباہ کن، نقصان دہ، فتنہ انگیز اور بزدلانہ ہیں شیخ کشک کے نظریات کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کرسکتے ہیں ''پیامبر و فرعون'' ص۲۱۹۔ ۲۲۰۔ خالد محمد خالد کے نظریات معلوم کرنے کے لئے رجوع کریں الشیعہ فی المیزان ص۳۷۵، ص۳۷۸ اخوان المسلمین کے طرفدار علما کے نظریات کے لئے رجوع کریں الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامیة ص۲۶۲۔ ۲۷۰۔ دوسرے گروہ کے نظریات معلوم کرنے کے لئے الاسلام والخلافة فی العصر الحدیث ص۹۔ ۳۴ مخصوصا ً، ص۱۸۔ ۲۳ اور کتاب الاسلام واصول الحکم میں محمد عمارہ کا مقدمہ ملاحظہ ہو۔
(۸۹)۔چوتھی صدی کی ابتدا میں حکومت عباسی کی اکثر سرزمینیںمحلی حکومتوںکے تابع تھیں، ان سرزمینوں میں ظاہری رابطہ بس اتنا ہی تھا کہ صرف خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اور اس کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رابطہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے عباسی حکومت بغداد اور اس کے اطراف میں محدود ہوکر رہ گئی تھی نظام الوزارة فی الدولة العباسیة ص۱۹۔
(۹۰)مثلا آپ سلجوقی بادشاہوں کا دینی سیاست کو اپنانے اور اسے اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لئے ایک وسیلہ قرار دینے کے سلسلہ میں معلومات کے لئے نظام الوزارة فی الدولة العباسیة ص۴۷۔ ۵۰ ملاحظہ ہو، ا بن اثیر ان لوگوں کی دینی سیاست کے سلسلہ میں اس طرح کہتا ہے: جب حکومت کی باگ ڈور سلجوقیوں کے ہاتھ میں آئی، اس وقت عظمت خلافت کا رنگ پھیکا پڑچکا تھا، انھوں نے اسے دوبارہ وہ عظمت بخشی مخصوصا نظام الملک نے اپنی وزارت کے دوارن اسے ایک خاص شکل میں جلوہ دیا جو التاریخ الباہر فی الدولة الاتابکیة ' ص۵۱، سے منقول ہے۔ نیز النقص ص۴۸۔ ۴۷،
اس کتاب میں ان مثبت نظریات کے ساتھ ان کے اقدامات کو نقل کرتا ہے
یہی سیاست خود عباسیوں نے بھی اپنائی تھی۔ البنداری کہتا ہے: یہاں اس کی مراد چھٹی صدی ہجری ہے، عباسیوں نے اس حد تک خلافت کی ہیبت بڑھادی کہ ''بغداد کو فتح کرنا اس کے دشمنوں کے لئے ناممکن ہوگیا جس کی وجہ سے کسی بادشاہ نے اسے فتح کرنے کے لئے اقدام نہیں کیا'' نظام الوزارة فی الدولة العباسیة، ص۶۴ جو کتاب آل سلجوقی ص۳۶۸ سے منقول ہے اور مزید وضاحت کے لئے اسی کتاب کا ص۶۲، ۶۷ بھی ملاحظہ کرسکتے ہیں،
(۹۱)اعلام الموقعین، ج۱، ص۴۸، ۴۷۔ اسلامی حکومت کی عمارت کی اصلی خصوصیات کے نام پر گروی ہونے اور دینی اور اخلاقی اقدار کی حفاظت میں اس کے کردار کی اس طرح وضاحت کرتا ہے: (۱)انسان کی خلقت کا ہدف عبادت ہے۔ (۲)کامل عبادت مؤمنین کے اجتماع کی محتاج ہے۔ (۳)ایسی امت ایک حکومت کی محتاج ہے۔ (۴) حکومت کا پہلا وظیفہ عبادت کی راہ ہموار کرنا ہے۔
G. E.Von Grunebaun Islam ۱۹۶۹,p,۱۲۷
(۹۲)اجماع کی قدر اور قیمت اور اہمیت مخصوصاً صحابہ اور خلفاء راشدین کا اجماع کہ جو صبحی صالحی کی تعبیر کے مطابق تشریع اسلامی کے مصادر میں سے تیسرا مصدر ہے اور یہ کہ کیسے بہت سارے مسائل کا مستند حکومت اور خلافت بن گیا ہے ایک سند کی شکل اختیار کرگئی۔ النظم الاسلامیة ص۲۸۱۔ مؤلف کے اعتقاد کے مطابق خلافت کی ایک دلیل خود اجماع بھی ہے اور اس باب میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ اس مطلب کو ثابت کرتی اور تائید ہیں جو اجماع کے ذریعہ ثابت ہوچکی ہیں۔
(۹۳)ابن تیمیہ کے اس کلام کی طرف توجہ کریں: احمد ابن حنبل اپنی مسند میں عبد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں: آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت نے فرمایا: کسی بھی انسان کے لئے حلال نہیں ہے مگر یہ کہ زمین کے کسی حصہ میں کسی کو امامت کے لئے انتخاب کرلیا جائے.. آنحضرصلىاللهعليهوآلهوسلم ت نے ایک شخص کی امارت اور حاکمیت کو اس چھوٹے سماج اور معاشرہ میں واجب قرار دیا تاکہ آئندہ برقرار ہونے والے بڑے بڑے اجتماع کے لئے بیداری کا باعث ہو، خدا نے امر بہ معروف اور نہی از منکر کو واجب قرار دیا اور یہ امر بغیر امامت اور قدرت کے انجام نہیں پاسکتا۔ اسی طرح تمام واجبات جیسے جہاد، اقامہ عدل، حج و جمعہ، اعیاد، مظلوم کی نصرت، اس وقت تک حدود بھی جاری نہیں ہوسکتے جب تک کہ قدرت و حکومت برقرار نہ ہوجائے۔ اسی وجہ سے یہ نقل ہوا ہے کہ بادشاہ زمین پرخدا کا سایہ ہوتاہے۔ یا یہ جملہ جو نقل ہوا ہے کہ ساٹھ سال ظالم بادشاہ کے ساتھ زندگی گذارنا ایک رات بادشاہ کے بغیر گذارنے سے بہتر ہے۔ اور تجربہ نے بھی اس بات کو ثابت کردیا ہے۔ اور پھر اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: اسی وجہ سے سلف صالح فضیل ابن عیاض اور احمد ابن حنبل اور دیگر افراد کہا کرتے تھے اگر ہمارے لئے کوئی مستجاب دعا ہوتی تو ہم سلطان کے لئے دعا کرتے۔ السیاسة الشرعیة ص۱۳۸ ۱۳۹ و نیز طبقات الحنابلہ، ۲ ص۳۶۔
(۹۴)حقیقت تو یہ ہے کہ آل بویہ اور فاطمیوں کی سیاست شیعوں کے عقائد کو بیا ن کرنے والی نہیںہے وہ اپنے ہی دور کی ایک حکومتیں تھیں الشیعة و الحاکمون ص۷۔
''... اسی وجہ سے وہ سلاطین جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے ان کا شیعوں کے عقائد سے کوئی ربط نہیں ہے اور شیعہ بھی اپنے اور سلاطین کے درمیا ن کوئی ربط نہیں دیکھتے۔ پس جو تصرفات بھی واقع ہوتے ہیںخود ان کی ذات سے مربوط ہیں، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو صحیح وگرنہ وہ گنہگار ہیں۔ اسی وجہ سے شیعہ اپنے آپ کو شیعہ سلاطین کے تصرفات سے بری سمجھتے ہیں اور چونکہ سیاست دین کے ساتھ ساتھ ہے اور ائمہ اطہار کی سیرت کے علاوہ کہیں اور مجسم نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا شیعوں کی کوئی بھی سیاسی فکر کبھی ائمہ علیہم السلام کے نظریات سے خارج نہیں ہوسکتی۔ اور اصولی طورپر شیعوں کی سیاسی فکر کو سیاسی مسائل سے جوڑکر ان کے آراء و خیالات میں معلوم کیا جاسکتا ہے، پس ایک شیعہ کی جانب سے سرزد ہونے والا عمل یا عقیدہ اگر ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت کے مطابق ہو تو وہ شیعوں کی سیاسی تفکر کا ایک حصہ ہے وگرنہ اس کا شیعوں کی سیاست سے کوئی ربط نہیں ہے۔'' الفکر السیاسی الشیعی ص۲۸۰ اور مزید وضاحت کے لئے اسی کتاب کا ص۲۶۸، ۲۷۱ ملاحظہ ہو۔
(۹۵)مصر میں جہادی تنظیم کی بنیاد رکھنے والے اہل سنت کے چار اماموں کی نسبت مصطفی شکری کی شدیداللحن تنقید کا مطالعہ کریں جو بعد میں گرفتار ہو کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ وہ دراصل اپنے کہ در واقع وہ اپنے اور اپنے بعد کے زمانے فقہا کو عدالت میں لاتا اور سلاطین کی مدد سے انھیں متہم کرتا ہے۔ وہ اس سوال کے جواب میں کہ کیوں ان چار اماموں نے باب اجتہاد کو بند کردیا تھا؟ تو جواب میں کہتا ہے: تاکہ وہ اور ان کے آثار کی تعریف کی جائے اور مشرکوں کے بتوں کی طرح وہ بھی پرستش کے قابل ہوجائیں، انھوں نے آپنے آپ کو خدا اور مومنین کے درمیان قرار دیا تھا اور اپنے آپ کو اسلام سے خارج کردیا تھا بلکہ وہ زیادہ تر جاہلیت اور وحشیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر اس طرح اپنے سلسلۂ بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کیا وہ لوگ جنھوں نے باب اجتہاد کو بند کرنے کے درپئے تھے آیا انھوں نے بھی ایسا ہی کیا؟ نہیں۔ انھوں نے عوام اور باقی مسلمانوں کے لئے باب اجتہاد کو بند کردیا لیکن طول تاریخ میں کسی بھی سلطان کے لئے درباری فقہا نے دوبارہ حاکمیت سے متعلق احکام کو صادر کرنے لئے باب اجتہاد کی طرف رجوع کیا اور اس طرح انھوں نے اسلام کے نام پر حرام کو حلال اور فساد کو ہوادینے کے موجب بنے۔ اگرہم حال و گذشتہ سے ایسی مثالیں پیش کردیں تو کسی میں اسے انکار کرنے کی جرأت پیدا نہیںہوسکتی۔اس لئے کہ زنا کی فقہا کی جانب سے تجویز، ربا خواری، قانون الہی کے برخلاف نامشروع قوانین کے تحت حکومتوں کو مشروعیت عطا کرنا،حتی کہ اسلام کے نام پر فحشا، شرابخواری کوتجویز کرنا واضح ہے اور پھر اپنے زمانہ میں اسی قسم کے صادر کئے فتووں کو بطور نمونہ پیش کرتا ہے۔ ''پیغمبر و فرعون'' ص۸۸، ۸۹۔
(۹۶)''نخستین رویا روئیھا ی اندیشہ گران ایران، ص۳۲۳، ۳۶۶۔
(۹۷)اہل سنت کے فقہا میں سے بعض اس حاکم کے سامنے قیام کی اجازت دیتے ہیں جسے راہ راست پر لانا شمشیر کے بغیر ممکن نہ ہو۔ اس مطلب کے لئے ابن حزم کے نظریات جسے اس نے امر بہ معروف اور نہی از منکر کے باب میںبیان کیاہے کتاب الفصل، ۴ ص۱۷۳، ۱۷۴۔ اسی طرح اما م حرمین جوینی کے نظریات شرح المقاصد نامی کتاب ج، ص۲۷۱، ۲۷۵ پر ملا حظہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے فقہا ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں جیسا کہ پہلے بھی کہا جاچکا ہے۔
(۹۸)ابن جوزی اپنی معروف کتاب تلبیس ابلیس، میں ابلیس کے ان تمام راستوں کو بیان کرتے ہیں کہ جس کی ذریعہ فقہا کو وسوسہ کرنے کاامکان ہے، انھیں میں سے ایک راستہ سلاطین کا تقرب ذکر کرتے ہیں اور اس باب میں اس طرح تفصیل بیان کرتے ہیں: فی الجملہ سلاطین کے دربار میں وارد ہونا ایک خطرناک فعل ہے۔ دربار میں تکریم اور انعامات، طمع اور حرص اور امر بہ معروف اور نہی از منکر سے کوتاہی شروع ہوجاتی ہے، ثفیان ثوری کہتے تھے: مجھے جس قدر سلاطین کی تکریم سے ڈر ہے اس قدران کی اہانتوں سے خوف نہیں ہے۔ اس لئے ان کے اس عمل سے میرا دل ان کی طرف مائل ہوجائے گا، گذشتہ علما ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے دوری اختیار کرتے تھے لیکن وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے ان کے فتاوی کے ذریعہ مدد طلب کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا ایک ایسا گروہ وجود میں آیا جو زبردست دنیا پرست تھا اور ایسے علوم سیکھے جو صرف امیروں کے کام آسکتے ہیں...۔ تلبیس ابلیس ص۱۱۸و ۱۱۹۔ اس طرح کی تنقیدیںحدیث، اخلاق اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔
مثلا خود غزالی سلاطین کے مقابلہ میں علما کے اس موقف روش کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اور یہ تھی امر بہ معروف اور نہی از منکر کے سلسلہ میں علما کی روش اور عادت نیز سلاطین سے ان کا خوف نہ کھانا۔ اور ان کا خدا پر بھروسہ کرنا خدا انھیں حفظ کرے خدا کے حکم پر راضی تھے تاکہ خدا انھیں شہادت نصیب کرے، اس لئے کہ ان کی نیتیں خالص اور دلوں میں ان کی باتیں زیادہ مؤثر واقع ہوتی تھیں اور انھیں نرم بنادیتی تھیں، لیکن اس دور میں طمع حرص نے علما کی زبانوں کو بند کردیا ہے اور انھیں خاموش رہنے پر مجبور کردیا ہیاور جب کوئی بات کہتے ہیں تو چونکہ وہ ان کے فعل کے مخالف ہوتی ہے لہذا مؤثر واقع نہیں ہوتی، اگر وہ اپنے قول میں سچے ہوں اور ان کی نیتیں خالص ہوں تو وہ بھی ضرور کامیاب ہوں گے، عوام کا فاسد ہونا سلطان کے فساد کی وجہ سے ہے اور سلاطین کا فاسد ہونا علما کے فساد کی وجہ سے ہے اور خود علما کا فاسد ہونا جاہ و مقام کی ہوس کے غلبہ کی وجہ سے ہے، جسے دنیا کی محبت اپنا اسیر بنالے، تو وہ ایک اوباش اور پست کو راہ راست نہیں لاسکتا تو پھر ایک سلطان اور صاحبان مناصب کو کیسے راہ راست پر لاسکتا ہے۔ احیاء علوم الدین، ۷ ص۹۲۔
قابل توجہ یہاں ہے کہ غزالی صرف دو مقام پر علما کو سلاطین کے دربار میںوارد ہونے کو جائز قرار دیتا ہے جو دین میں سیاست کے ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے: سلاطین کے پاس جانا سوائے دو امر کے جائز نہیں ہے اول یہ کہ سلطان عالم کو اکرام کے بدلہ الزام کے لئے طلب کرے اور اسے معلوم ہو کہ اگر وہ انکار کرے گا تو اسے شکنجہ کیا جائے گا یا سلطان کے پاس نہ جانے کی وجہ سے عوام کی سرکشی کا باعث ہو اور امررعیت اختلاف کا شکار ہو جائے گا ایسی صورت میں جانا واجب ہے۔ سلطان کی اطاعت کی غرض سے نہیں بلکہ لوگوں کی مصلحت اور حکومت میں فساد واقع نہ ہونے لئے سلطان کے پاس جائے۔ دوم یہ کہ کسی مسلمان یا اپنے سے ظلم کو دفع کرنے لئے جائے...، احیاء علوم الدین، چھٹا باب فیما یحل من مخالطہ السلاطین الظلمة جو کتاب الاسلام بین العلماء والحکام ص۱۱۲ سے منقول ہے نیز کتاب الفوائد ابن قیم ص۱۴۹۔ ۱۵۳ نیز،
Goldziher The Zahiris ,P,۱۶۵. Gibb, Studies on The Civlization of Islam, P. ۱۴۵ کی طرف رجوع کیا جاسکتاہے۔
(۹۹)اسی سیاست کے نمونہ عثمانی خلافت کے آخری ایام میں مسجد ایا صوفیہ کے امام جمعہ شیخ عبد اللہ کے خطبہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ''... یہاں اسی مطلب کو بیان کروں گا کہ جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، ان میں فقرا اور اپاہج لوگوں کے علاوہ وہ لوگ کہ جو اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم کے وارث ہیں، اساتید، مفتی، قضاةاور دراویش، تجار، صنعتی لوگ، بلکہ تمام لوگ قرآن کے حکم کے مطابق کافر ہوچکے ہیں اور منافقوں کے زمرہ میں ہیں لہٰذا انکا قتل کرنا واجب ہے، اس لئے کہ انھوں نے جہاد کو ہزاروں آیات و شواہد کے باوجود جان و مال سے جہاد کرنا ترک کردیا ہے، واجب ہے۔ ان لوگوں کے ایمان کی تجدید دوامر پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ جنگ میں حاضر ہوں اور دوم یہ کہ اگر صاحب مال ہیں تو نصف مال ترکی کے دارخلافہ کے حوالہ کردیں تاکہ وہ (ترک) اپنے داخلی اور خارجی دشمنوں سے انتقام لے سکیںاور اگر وہ اپنا نصف مال دارالخلافہ کے حوالہ نہ کریں تو ان کا دوبا رہ ایمان لانا کفایت نہیں کرے گا اور روز قیامت مرتد اور کفار کے ساتھ محشور کئے جائیں گے اور جہنم میں جھونک دئے جائیں گے...'' ثورة العرب ضدالاتراک ص۲۲۴ جو ''قوم جدید'' نامی کتاب کے ص۲۵ سے منقول ہے۔
(۱۰۰)معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی،ص۱۱۔ اس داستان کی تفصیل، عرب کا مشہور ناسیونالیسم ساطع حصری نے اپنی کتاب البلاد العربیة والدولة العثمانیة میں درج کیا ہے۔ کتاب الفکر السیاسی الشیعی ص۳۰۰ اور ۳۰۱، میں اس داستان کا ایک مختصر خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ ''سلطان سلیم نے اہل سنت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور خود فروش علما سے شیعوں کے کفر اور ان کے قتل کے وجوب کے سلسلہ میں فتوا حاصل کیا،۔ اور پھر یہ فرمان جاری کردیا کہ اس کی حکومت میں جہاں بھی شیعہ ہوں ان کی گردن مار دی جائے۔'' ص۳۸، حائری ساندرس کے بقول سلطان سلیم کے اقدامات کے سلسلہ میں اس طرح توضیح دیتے ہیں: سلطان سلیم جس نے آٹھ سال ۹۱۸ سے ۹۲۷ تک حکومت کی، اس مدت میں اس نے ایران پر حملہ کیا اور ۹۲۰ ق، کے بعد کردستان اور آذربائیجان کو فتح کیا اور اس کی حکومت میں جوبھی شیعہ تھا یا اسے قتل کردیا یازندان میں ڈال دیا۔ اور سنی علما نے یہ اعلان کردیا تھا کہ ایک شیعہ کو قتل کرنا ستر عیسائیوں کے قتل کرنے سے بہتر ہے اور ایک قول کے مطابق چالیس ہزار شیعہ مارے گئے۔ مجلہ دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشہد،شمارہ ۵۷۔ ۵۸ ص۵و۶۔
(۱۰۱)جیسے کہ سلجوقی حکام مختلف بہانوں سے شیعہ مخالف سیاست کو اپنائے ہوئے تھے نظام الوزارة فی الدولة العباسیة، ص۴۷ اور خواجہ نظام الملک شیعوں کو کافر قرار دیتے ہوئے کہتا ہے: جہاں بھی انھیں پاؤ قتل کردو یا جہاں بھی رافضی ملیں انھیں منبروں پر لے جاکر سربرہنہ کیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ تم دین کے دشمن ہو، لیکن اس کے باوجود اس دور کے جلیل القدر شیعہ متکلم عبدالجلیل قزوینی سلجوقی حکام کے دین کو وسعت بخشنے کے سلسلہ میں اس طرح کہتے ہیں: حقیقت تو یہ ہے کہ اس عالم میں زمین کے تمام حصوں میں مسلمانوں کے درمیان جو مدارس، مساجد، خانقاہیں، منابر، احیاء سنت اور بدعتوں کا قلع قمع آل سلجوق کی برکتوں اور ان کی شمشیر براں کی وجہ سے ہے۔ مجلہ دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ مشہد، شمارہ ۵۶، ۷۴۴، ۷۴۵۔ جو کتاب النقض و سیاستنامة سے منقول ہے۔ تاریخ تشیع میں ایسے ہزاروں نمونہ موجود ہیں اگرچہ اسکے برخلاف نمونہ کم پائے جاتے ہیں۔
جیسے کہ، نادرشاہ نے، ۱۷۴۱، میں سلطان عثمانی کو قانع کرنا چاہا کہ وہ شیعیت کو پانچواں مذہب قبول کرلے یہاں تک کہ اپنی بات منوانے کے لئے اسے خلیفہ اسلام لقب دینے پر راضی ہوگیا لیکن سلطان عثمانی نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔
(۱۰۲)۔اکثر مقامات پر شیعہ حکام کے علاوہ دوسرے گروہوں کی جانب سے آزار و اذیت اور لوٹ مار کا شکار رہا کرتے تھے اور ان میں ہر ایک سے زیادہ خود فروش علما کا نقش رہاہے، یہ لوگ عوام کو بہکاتے تھے اور دین سے دفاع کے نام پر شیعوں کے خلاف دوسرے فرقوں کو ابھارتے تھے۔ ابو محمد حسن بن علی بن خلف بر بہاری، بغداد کے حنبلیوں کے رئیس اور صاحب نظر تھا اور جو بھی اس کے نظریات کا مخالف ہوتا اس سے شدت کے ساتھ مقابلہ کرتا اور اپنے چاہنے والوںکو عوام کے ساتھ شدید مقابلہ کا حکم دیتا بلکہ بعض مواقع پر لوگوں کے گھروں کو غارت اور ان کی خرید و فروش میں مزاحمت کا حکم دیتا اور جو بھی اس کی باتوں کا انکار کرتا تو اسے ڈرانے اور دھمکانے کا حکم دیتا تھا۔
اسی کی حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ بھی ہے کہ اُس نے امام حسینـپر رونااور آپ کی زیارت کے قصد سے کربلا کا سفر کرنا ممنوع قرار دے دیا بلکہ نوحہ کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دور میں ایک نوحہ خوان تھا جو نہایت مشہور اور خوش آوازتھا اسی کے قصائد میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ (ایھا العینان فیضا۔۔ واستھلا لا تفیضا) جسے امام حسینـ کے مرثیہ میں پڑھا کرتا تھا اور ہم نے اسے بغداد کے ایک رئیس کے مکان میں سنا تھا، اس وقت کسی میں کھلم کھلا نوحہ کرنے کی جرأت نہیں تھی مگر یہ پوشیدہ طور پر یا پھر اسے سلطان کی پناہ حاصل ہو، جب کہ نوحہ مرثیہ کے علاوہ کچھ اور نہ تھا اور سلف کے خلاف کوئی اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود جب بر بہاری کو اس کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ اسے جہاں پاؤ قتل کردو۔ ''وہابیان'' ص۲۶۔ اس سلسلہ میں بربہاری اور اسکے چاہنے والوں کی کارستانیوں سے زیادہ آگاہی کے لئے رجوع کیا جاسکتاہے، سابق حوالہ ص۲۶۔ ۳۳ نیز ابو الحسن اشعری کے ساتھ مناقشہ،اور اسکے عقائد و انجام کی معلومات کے لئے رجوع کرسکتے ہیں طبقات الحنابلہ ج۲، ص۱۸، ۴۵۔
(۱۰۳)حقیقت تو یہ ہے کہ ذکر کئے گئے عوامل کے علاوہ مذہبی عوامل بھی تھے کہ جس کی وجہ سے علما صفوی بادشاہوں سے نزدیک رہا کرتے تھے، اس لئے کہ صفوی خود صوفی مسلک تھے اور انھیں صوفیوں کی مدد سے قدرت کی باگ ڈور سنبھالی تھی اور یہی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے خاندان پیغمبرصلىاللهعليهوآلهوسلم کے عقیدتمند تھے، اس دور میں شیعہ علما نے اسی عقیدت سے فائدہ اٹھایا اور انھیں شیعیت سے نزدیک کیا، اسی مہم کی غرض سے شیخ بہائی اور انکے والد بزرگوار صفویوں سے نزدیک ہوئے۔
(۱۰۴)اس فتوی پر اصرار اور اسکے انجام سے آگاہی کیلئے مجلہ تراثنا، شمارہ ۳۸، ۴۱، نیز الفصول المہمة فی تالیف الامة ص۱۴۳، ۱۴۷ ملاحظہ ہو اور دوسرے شواہد کے لئے اسی مجلہ کی طرف رجوع کریں ص۳۲، ۶۱۔
(۱۰۵)تراثنا۔ شمارہ، ۶، ص۴۰۔
(۱۰۶)تحول اثبات، ص۱۶۱، ۱۶۵۔
(۱۰۷)علماء دین کا اس دور کے روشن فکروں سے مقابلہ جو ان کی واقعیت کی حکایت کرتا ہے، اس سلسلہ میں سید جمال سر فہرست ہیں: یہ دہریے یورپ کے دہریوں جیسے نہیںہیں اس لئے جو مغربی ممالک میں دین کو ترک کرتا ہے۔ اس میں وطن دوستی اور دشمنوں سے اپنے وطن کی حفاظت کی حمیت و غیرت باقی رہتی ہے۔ اوروہ وطن کی مصالح کی خاطر جانفشانی کرنے کے لئے آمادہ رہتا ہے۔لیکن احمد خان اور اس کے پیروکار دین کی حفاظت کی خاطر اپنے وطن کی مصلحت سے غافل اور انھیں اجنبیوں کے تسلط کے لئے آمادہ کر رہے ہیں... ان کا یہ عمل عظیم اجر اور کسی شرف کی خاطر نہیں ہے بلکہ ایک پست زندگی اور ناچیز منفعت کے لئے ہے اور اس طرح یہ مشرقی دہریے غربی دہریوں کے مقابلہ میں الحاد و کفر کے بعد پست و حقیر ہونے کے ذریعہ پہچان لئے جاتے ہیں۔ العروة الوثقی ص۵۷۲۔ ۵۷۵ جو کتاب الفکر الاسلامی الحدیث و صلتہ بالاستعمار الغربی ص۴۳ سے منقول ہے۔ المنار شمارہ ۱۳، اپریل ۱۹۲۵، ص۳۱ جو کتاب الاسلام و اصول الحکم ص۸، ۹ سے منقول ہے۔ خلافت کے سقوط کے اسباب اور مجمع کی جانب سے ہونے والی حمایتوں سے آگاہی کے لئے سابق حوالہ ص۷، ۱۴ ملاحظہ ہو.
(۱۰۸)آئیڈیالوجی وانقلاب، ص۱۵، ۱۶۴۔
(۱۰۹)سابق حوالہ ص۱۶۹، ۱۸۴۔
(۱۱۰)شیعوں کی تاریخ میں سیاسی اور معاشرتی تحولات اور انقلابات میں حماسہ عاشوراء ہمیشہ سے ممتاز رہا ہے ۔یہ بات ہمارے دور میں ایک عنوان کے تحت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ شیعی دنیا اور بالخصوص ایران میں تاریخ معاصر کے دوران افکار کی ضرورت سیاسی سرنوشت کو بدلنے کے لئے انقلابی راہ حل کی ضرورت ہمیشہ باقی رہی ہے۔
مثال کے طورپر مالک ابن انس کا موقف محمد نفس زکیہ کی بہ نسبت مجمل اور غیر واضح رہا اور قوی احتمال کی بنا پراسی نکتہ کے سبب وجود میں آیا تھا، مدینہ والے محمد کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ پہلے منصور سے بیعت کر چکے تھے لہذا مالک ابن انس نے کہا کہ مجبوری میں بیعت منعقد نہیں ہوتی۔ جس کے بعد مدینہ والے محمد کے اطراف میں جمع ہوگئے، مالک کی یہ طرفداری باعث بنی کہ حاکم مدینہ کے حکم سے انھیں اس حد تک مارا گیا کہ اس کی وجہ سے ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن جب اسی مالک ابن انس سے حاکم کے خلاف خروج کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب میںکہا: اگر یہ قیام عمر ابن عبد العزیز جیسے حاکم کے خلاف ہو تو جائز نہیںہے اور دوسری روایت کے مطابق جائز نہیں کے بجائے: خدا انھیں قتل کرے کا جملہ پایا جاتا ہے اور اگریہ قیام اسکے علاوہ کسی دوسرے حاکم کے خلاف ہو تو اسے اسی کے حال پر چھوڑدو، تاکہ خدا ایک ظالم سے ایک دوسرے ظالم کے ذریعہ انتقام لے پھر اس کے بعد دونوں ہی سے انتقام لے الفکر السیاسی الشیعی ص۳۲۱۔ علما کے حکام کے خلاف قیا م سے متعلق دوسرے شواہد کے لئے الاسلام بین العلماء والحکام، ص۱۰۴، ۲۲۲ ملاحظہ کرسکتے ہیں۔
جن لوگوں کا مؤلف موصوف تعارف کراتے ہیں انھیں میں سے سعید بن مسیب ہے: جب عبدالملک نے سعید سے ایک ہی وقت میں اپنے دو بیٹوں ولید اور سلیمان سے بیعت لینا چاہی تو انھوں نے بیعت کرنے سے انکار کردیا اور کہا: رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم نے ایک ہی وقت میں دولوگوں کی بیعت کے لئے نہی فرمائی ہے۔ عبدالملک نے سعید کو بڑے بڑے شکنجے دیئے لیکن سعید تسلیم نہیں ہوئے سلاطین کے مقابلہ میں اس طرح ڈٹے رہنا امام حسینـکا یزید کے مقابلہ میں یا جناب زید کا ہشام کے مقابلہ میں قیام کرنے میںبہت فرق ہے۔ تقریبا اہلسنت کے تمام علما ان حکام کے مقابلہ میںکہ جس کے سامنے قیام کرتے تھے اس کی حاکمیت کے نامشروع ہونے کا فتوا نہیں دیتے بس اتنا تھا کہ اس کے تقاضوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔
(۱۱۱)بطور نمونہ الاسلام بین العلماء والحکام ص۱۱۵۔ ۱۳۲ ملاحظہ ہو لیکن اس مقام پر اہم یہ ہے کہ شیعہ اور سنی علما دینی وظیفہ کو دو دو جدا معانی میں تفسیر کرتے ہیں۔ اور ان کی تفسیروں کا یہ فرق بھی حکام سے تعلق اور اس کے ظلم و جور کے مقابلہ میں خاموش نہ رہنے سے متعلق ہے مثلا آپ امام حسینـ کے کلام میں جودینی علما کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں انھیں۔ تحف العقول ص۱۷۱، ۱۷۲۔ وہ بھی اس طرح کہ جو ابن حنبل نے وظائف بیان کئے ہیں ان سے موازنہ کریں اعلام الموقعین ۱، ص۹ جو کتاب الرد علی الزنادقة والجھمیة ابن حنبل سے ماخوذ ہے۔
(۱۱۲)الائمة الاربعة، ص۱۴۰، ۱۸۰اور مناقب الامام احمد ابن حنبل، ص۳۹۷، ۴۳۷۔
(۱۱۳)اہل سنت کے فقہاے کے درمیان یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حاکم کے مقابلہ میں قیام نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کے ظلم پر صبر کرنا چاہئے۔ شافعی اور ابن حنبل اسی قول کے قائل تھے الانتفاضات الشیعة عبر التاریخ ص۹۸، نسفی اپنی کتاب شرح العقائد میں اسی نظریہ کو ابوحنیفہ سے منسوب کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں: خلفاء راشدین کے بعد حکام کے درمیان فسق و فجور ظاہر ہوگیا اور سلف صالح نے بھی ان کی اطاعت کرلی اور ان کے ساتھ نماز جمعہ و جماعت پڑھی لیکن ان کے خلاف خروج نہیں کیا۔ سابق حوالہ ص۹۹ جن فقہا نے خروج کو حرام قرار دیا ہے تقریبا ہر ایک نے اسی ایک نکتہ کو اپنی دلیل بنائی ہے۔ مزید وضاحت کے لئے سابق حوالہ ص۹۷۔ ۱۰۷ نیز طبقات الحنابلہ ج۲، ص۲۲ ملاحظ ہو۔
(۱۱۴)جوانوں میں ایک انقلابی فکر کی شدت کو معلوم کرنے کے لئے مجلات النذیر۔ الثورة الاسلامیة، المنطلق۔ الدعوةاور وہ تمام مجلات جو جوانوں اور مجاہدین کی جانب سے شائع ہوتے ہیں ملاحظہ ہوں۔
(۱۱۵)ظالم حکام کی نسبت اہل سنت کے مجاہد جوانوں کے نظریا ت کو معلوم کرنے کے لئے عتیبی کی تنقیدوںکی طرف رجوع کرسکتے ہیں، کہ جس نے اول محرم ۱۴۰۰ میں خانہ کعبہ پر قبضہ کرلیا اور آل سعود کو نکال باہر کردیا تھا اور ۱۹۷۸ میں عبد العزیزین کے ذریعہ قید خانہ سے آزاد ہوا
Faith and Power.PP. ۱۸۰-۱۸۵
(۱۱۶)اسلامی معاشروں کے متمدن ہوجانے کی وجہ سے جوانوں پر جو اثر ظاہر ہوا اسے معلوم کرنے کے لئے ''پیامبر وفرعون'' ص۲۷۳، ۲۹۵ نیز اسی سلسلہ میں سعدالدین کی تحقیق بنام ایدئولوژی و انقلاب، ص۱۶۹، ۱۷۸۔ کی طرف رجوع کرسکتے ہیں۔
(۱۱۷)پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں اسلام نے جو پوری دنیا بالخصوص مصر اور عرب کی مشکلات سے روبرو ہوا اس کا اندازہ لگانے اور کیفیت معلوم کرنے کے لئے الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعمار الغربی ملاحظہ کرسکتے ہیں۔
(۱۱۸)اس دو دور کے آپسی فرق کو معلوم کرنے کے لئے دوران معاصر کے روشن فکر مسلمان کی فکری وعقیدتی داستان کی طرف رجوع کرسکتے ہیں جنھوں نے صداقت اور صراحت کے ساتھ اسے روشن کیا ہے العقیدة الی الثورة ص۴۶، ۴۸۔
(۱۱۹)عبد الرزاق کے استدلالی مباحث کتاب الاسلام واصول الحکم میں رجوع کرسکتے ہیں کہ جہاں اس نے خلافت کو اس عنوان کے تحت باطل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دین کے اصول میں سے ایک اصل اور اس کے امور میں سے ایک امر ہے۔ وہ اس سلسلہ میں علما کے اجماع بالواسطہ اصل اجماع کا انکار کرتا ہے، چنانچہ اور اس کے تمام نقادوں نے اسی ایک نکتہ کو مورد توجہ قرار دیااور اس زاویہ کے تحت اس کے نظریات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ بطور نمونہ مراجعہ کریں، علماء ازہر کے ان سات اشکالات کی طرف کہ جسے انھوںنے اس کے نظریہ کے خلاف بیان کیا ہیاور پھر انھیں اشکالات کی بنیاد پر محاکمہ کیا اور جامعہ ازہر سے نکال دیا۔ کتاب الاسلام و اصول الحکم ص۱۲ پر محمد عمارہ کے مقدمہ کی طرف رجوع کریں۔ نیز کتاب سد باب الاجتہاد وماترتب علیہ عبدالکریم خطیب کی طرف رجوع کریں کہ جنھوں نے ایک دوسرے زاویہ سے عبدالرزاق ہی کے نظریات کو دہرایا ہے ان کا اصلی ہدف باب اجتہاد کو کھولنا اور اس کی مدد سے دینی بحران کو ختم کرنا اور مسلمانوں میں دینی شعور بیدار کرنا اور اسلامی سماج کو زیادہ اسلامی بنانے میں مدد کرنا تھا، سابق حوالہ، ص۷۔
(۱۲۰)عتیبی کے نظریات کے باب میں الحرکة الاسلامیة فی الجزیرة العربیة ص۱۱۹، ۱۳۰۔
(۱۲۱)بطور نمونہ یوسف قرضاوی کی دلسوز نصیحتو ں کی طرف رجوع کیاجائے جسے انھوں نے
جوانوں کے نام اپنی کتاب الصحوة الاسلایة بین الجمود والتطرف لکھی ہیاور انھیں پیغام دیا ہے کہ وہ دین کی غلط تفسیر اور اس میں زیادہ روی کو ترک کردیں اور اس کے اصول سے تجاوز نہ کریں۔
(۱۲۲)تاریخ خلفائ، ص۷۷
(۱۲۳)الاسلام و اصول الحکم، محمد عمارہ کے مقدمہ کے ہمراہ ص۹ جو المنار شمارہ ۲۳ اپریل سال ۱۹۵۲۔ ۲۹ رمضان ۱۳۴۳ق، ص۱۳۔
(۱۲۴)مجلہ دانشکدہ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاہ مشہد، شمارہ، ۵۷، ۵۸، ص۴،۸۔
(۱۲۵) احمد شوقی جومصرکا ملک الشعراء تھا اسے عثمانیوں بلکہ ترکوں سے اسلام و اسلامیت کے پرچمدار ہونے کی وجہ سے ایک خاص ارادت تھی، اس کے دیوان''الشوقیات'' میں مختلف مناسبتوں کے تحت ترکوں اور عثمانیوں کی تعریف و تمجید ملے گی بلکہ احساسات اور جذبات سے لبریز اشعار کہے ہیں۔ مثلا اسی میں ترکوں کی تعریف کرتے ہوئے انھیں اشرف امت کا لقب دیاہے اور انھیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: وہ نہ ہی (ترک جوانوں) کے افکار کی تلاش میں جائیں اور نہ ہی نفس کے مقابلہ میں ذلیل و خوار بلکہ ایک متحرک اور ثابت قدم انسان رہیں، ص۱۰۶، ۲۰۷، اسی طرح ایک مقام پر دریائی فوج کو دیکھتے ہوئے کہ جن کی کشتیوں پر اسلام کا پرچم لہرارہا تھا، وجد میں آجاتاہے اور اشعار کہتا ہے (۲۰۸، ۲۱۱) یونانیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ترکوں کی بڑی تعریف کرتا ہے اور اس لشکر کے سردار مصطفی کمال کو ''خالد ترک ' ' کا لقب دیتا ہے (ص۴۴، ۲۵۸،) یہاں تک کہ جب شریف حسین نے خلافت کا دعوی کردیا تو اس نے سلطان عبدالمجید کے لئے ایک طولانی شعر لکھ کر روانہ کیا (سال ۴، ۱۱۹) چونکہ اسے مکہ و مدینہ کا اصلی مالک سمجھتاہے لہذا اس سے درخواست کرتاہے کہ وہاں سے شریف حسین کا خاتمہ کردے۔ (ص۱۹۴) جب اتاترک کے ذریعہ خلافت کو ساقط کردیا گیا تو اس نے اس وقت نہایت غمگین اشعار کہے جس کا مضمون اس طرح ہے ''شادی کے نغمہ نوحہ میں بدل گئے اور خوشی کے شادیانے موت کا پیغام لائے ہیں۔'' اور پھر انھیں اشعار کے ضمن میں مسلمانوں سے درخواست کرتاہے کہ اسے نصیحت کریں تاکہ وہ اپنی نیت سے منصرف ہوجائے۔ (ص۹۰۔ ۹۳) ان اشعار کو شریف حسین کی مدح میں اور ترک اور عثمانیوں کی مذمت میں کہے اشعار سے موازنہ کریں۔ ثورة العرب ضد الاتراک، ص۴۵۳ کے بعد
(۱۲۶)الاسلام و اصول الحکم، محمد عمارہ کے مقدمہ کے ہمراہ، ص۸۔
(۱۲۷)الاسلام و اصول الحکم، ص۹، جو اخبار الاہرام شمارہ ۱۲، مئی سال ۱۹۲۵، مجلہ المنار شمارہ ۲۳ اپریل ۱۹۲۵، ص۳۱ سے منقول ہے، خلافت کے ساقط ہونے کی وجہ سے جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور پھر مذکورہ مجمع کی جانب سے حمایتوں کے نعرے بلند ہوئے، رجوع کریںسابق حوالہ کی طرف، ص۷ اور ۱۴۔
(۱۲۸)سابق حوالہ، ص۱۷ جو المنار ج۲، شمارہ ۲۱جنوری ۱۹۲۵، ص۱۰۰ سے منقول ہے۔
(۱۲۹)سابق حوالہ، ص۱۳ جو اخبار السیاسة شمارہ ۲۲ جنوری سال ۲۵ ۱۹ سے منقول ہے۔
(۱۳۰)رجوع کریں Charles D. Smiths, Islam and The Search of
Social Order in Modern Egypt. p. ۱
(۱۳۱)ان ایام میں خلافت کے منصب کے لئے بعض مسلمان حکام جیسے بادشاہ مصر ملک فؤاد کے دل میں وسوسہ ہوا۔ مقدمہ الاسلام و اصول الحکم، ص۸اور اس داستان کی تفصیل کو کتاب اسلام والخلافة فی العصر الحدیث ص۳۵،۱۴۵، کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اور قابل توجہ تو یہ ہے کہ رشید رضا اور اس کے ہمفکر افراد نے یمن کے امام کو جامع الشرائط ہونے کی وجہ سے خلافت کے لئے انتخاب کرلیا تھا۔ ''اندیشہ ہای سیاسی در اسلام معاصر، ص۱۳۷۔
(۱۳۲)لفظ خلافت کے مطلق ہونے سے حکومت اسلامی کی ریاست سمجھ میں آتی ہے بلکہ یہ بھی کہا جاسکتاہے کہ خلافت حکومت اسلامی کے معنی میں ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ حکومت کے رئیس کو خلیفہ مانا جاسکتا ہے۔ معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی، ص۳۰۔
(۱۳۳)بطور نمونہ مراجعہ کریں الفکر الاسلامی الحدیث فی مواجھة الافکار الغربی ص۷، ۲۴۔
(۱۳۴)حسن البناء کے اس جواب کی طرف رجوع کریں کہ جو اُس نے کیا چاہتے ہو؟ کے جواب میں لکھا ہے من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ص۱۱۔
حکومت اسلامی کے مفہوم کے معین ہونے کی پہلی علامتیں اور اس کا آرزو میں تبدیل ہوجانا اس کے جواب میں مل سکتا ہے۔
(۱۳۵)اسلامی ممالک مخصوصا مصر اور ہند میں مغربی قوانین کے نفوذ کی تاریخ کے لئے
Islamic Surveys , A History of Islamic Law , PP. ۱۴۹-۱۶۲
(۱۳۶)۱۲۶. H.A. Gibb and HarebdBrown , Isramic sacitg amd the Weet , vmr ۱rst. pp , Islamic Society and the West, vol,۱
(۱۳۸)بطور نمونہ مرزا ملک خان کی طرف سے جتنے بھی ملاحظہ قانون اخبار میں شائع ہوئے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔
(۱۳۹)عبد العزیز البدری، عثمانی حکومت میں نئے قوانین کے نفوذ کو اس طرح توضیح دیتے ہیں۔ ''...۱۸۵۷م میں نئے قوانین منجملہ قوانین جزا، تجارت، حقوق مدنی، آہستہ آہستہ نفوذ کرنا شروع ہوگئے۔ لیکن جب تک شیخ الاسلام نے اس کے لئے شیریعت سے مخالف نہ ہونے کا فتوا نہ دے دیا اس وقت تک جاری نہ ہوسکے۔ علماء اسلامی حکومت میں قوانین مدنی کے ورود کو جائز نہیں سمجھتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے معاملات کے سلسلہ میں ایک مجلہ کا شائع کرنا شروع کیا جو ان قوانین بنانے والوں کی فہم کے مطابق احکار شرعیہ سے مستند تھے۔ الاسلام بین العلماء والحکام ص۱۷۔ نیز تحریر المجلة ج۱، کی طرف رجوع کریں۔
(۱۴۰) William Shepard, The Faith of a Modern, Intellectual( Muslim
(۱۴۱)سابق حوالہ، ص۴۔
(۱۴۲)اہل سنت کے درمیان تحریک اخوان المسلمین کے مؤسس حسن البنا ء ہیں جنھوںنے پہلی مرتبہ ایک سیاسی اور انقلابی تحریک کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو اس طرح تعلیم دیتے ہیں اگر کوئی تم سے پوچھے کہ لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ تو جواب دینا کہ اس اسلام کی طرف کہ جو رسول اللہصلىاللهعليهوآلهوسلم پر نازل ہوا تھا اور حکومت اس کا ایک جزء اور آزادی اس کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ یہ تو سیاست ہے تو جواب دینا کہ یہ اسلام ہے اور ہم ایسی کوئی تقسیم نہیں جانتے۔ اگر وہ کہے کہ تم انقلاب کے منادی ہو تو جواب دینا کہ ہم حق و حقیقت اور صلح کے طالب ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے اور وہ ہمارا فخر ہے پس اگر ہمارے مقابلہ میں کھڑے ہوئے اور ہماری تبلیغ میں مانع ہوئے تو یہ یاد رہے کہ خدا نے ہمیں دفاع کی اجازت دی ہے اور پھر اس صورت میں تم لوگ ظالم ٹھہرو گے۔'' من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ص۱۱ جو بین الامس والیوم۔ حسن البناء کی کتاب سے منقول ہے۔
(۱۴۳)معالم فی الطریق، ۸، ۱۱۔
(۱۴۴)یہاں تک کہ ایک آزاد انساناور ایک ذمہ دار دانش ورکتاب معالم الخلافة الاسلامیة نامی کتاب کے مؤلف جس نے اس کے سلسلہ میں سلف کے نظریاتاور اس کے شرائط نیز، اس کی اطاعت اور عدم مخالفت کے تحت تنقید کرتے ہیں، وہ بھی زیادہ اس بات کے حامی نہیں ہیں کہ کوئی نظام حاکم کے سامنے قیام کرے۔ جبکہ جو اس نے خلافت کی تعریف کی ہے اس کے اسلاف اور ہمعصروں کے مقابل زیادہ منطقی اور معقول اور ترقی یافتہ ہے۔ ''شریعت کے قوانین کو پورے جہان میں جاری کرنا اور اسلام کی تبلیغ کے لئے تمام مسلمانوں پر ایک عمومی ریاست'' سابق حوالہ، ص۳۰۔ یا ایک دوسرے مقام پربھی اس طرح کہتاہے ''امت صاحب قدر ت ہیاور جب وہ خلیفہ سے بیعت کرتی ہے تاکہ وہ حکومت کی ریاست کو سنبھالے اور اسلام کی زندگی کو عملی جامہ پہنائے، تو ایسا فرد اس کی قدرت میں اس امت کا نائب ہوگا، اس لئے کہ یہ امت احکام کے جاری ہونے اور اس کے نافذ ہونے کی خواہاں ہے اور خلیفہ امت کی نیابت میں ایسا ہی کرتا ہے پس وہ شخص خلیفہ نہیں ہوسکتا جس کی بیعت لوگوں نے اپنی رضایت اور اپنے اختیار سے نہ کی ہو اور بیعت امت کی جانب سے خلیفہ کے نائب ہونے کی علامت ہے۔'' سابق حوالہ ص۳۸۔وہی مؤلف ایک دوسرے مقام پر حاکم کے خلاف خروج سے متلعق کہتا ہے: اگر قیام مسلمانوں میں خونریزی کا باعث ہو تو یہ قیام جائز نہیں ہے اس لئے کہ ملک میں فتنہ ایجاد کرنا شرعی طورپر حرام ہے۔ اور جو حرام کا موجب بنے تو اس قاعدہ کی رو سے (وسیلہ حرام حرام ہوتا ہے) حرام ہے۔ اس صورت میں اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے ساتھ فتنہ کو دبانے کے لئے جہاد واجب ہے۔ اور ایسی صورت میں وہ امیر ہوگا خلیفہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ مسلمان اپنے ارادہ و اختیار سے اس کی بیعت کریں۔ سابق حوالہ، ص۱۲۶۔
(۱۴۵)ہمارے زمانے کے ایک ممتاز اہل سنت عالم دین شیخ اسعد بیوض التمیمی کہتے ہیں: حکومت اسلامی سے مراد شریعت کی تطبیق اور اسے جاری کرنا ہے۔ اس کلام کو بارہا اسی عالم سے نقل کیا گیا ہے نیز رجوع کریں کتاب تحول وثبات ص۱۲۰، ۱۲۱۔
(۱۴۶)مزید توضیح کے لئے کتاب، پیغمبر و فرعون'' ص۷۵، ۱۹۲ ملاحظہ ہو۔
(۱۴۷)اس طرح کی بہت ساری تنقیدوں کا ضمنی جواب جو کہ جدید امیدوں کا نتیجہ ہیں کہ جس نے معاشرتی، اقتصادی ،فکری وسیاسی حالات نے ان کو جنم دیا ہے، اہل سنت کے وارستہ عالموں میں سے ایک عالم دین، محمد ضیاء الدین الریس نے، اس وقت ان تنقیدوں کے جوابات دئے تھے جب یہ (اعتراضات) اس درجہ شدید نہ تھے،بڑے ہی متواضعانہ انداز میں دیا ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان جوابات کے مخاطب غیر مسلمان یا بد عقیدہ مسلمان ہیں۔ لیکن بہر حال اس کا جواب ان تمام لوگوں کیلئے ہے جنھوں نے پوری تاریخ میں علماء اہلسنت پر ان کے سیاسی موقف کی وجہ سے تنقیدوں کی بارش کی ہے۔ وہ خواہ مسلمان اور وفادار ہوں یا غیر مسلمان اورغیرذمہ دار ہوں۔ ''بعض مؤرخین بالخصوص مستشرقین علماء اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے متعلق ایسی باتوں کی نسبت دیتے ہیں کہ نہ ہی ان کی کوئی واقعیت ہے اور نہ ہی انھیں پسند ہے۔ اس کو پیش کرتے ہیں معترضین یہ کہتے ہیں کہ وہ حکام کی جانب مائل تھے، ان کی سیاست اور راہ و روش کے موافق اور ان کے درباری امور میں ان کے مدد گار تھے۔ مثلا امویوں کے زمانہ میں حسن بصری، شعبی سعید ابن جبیر اور سعید ابن مسیب اور عباسیوں کے دور میں ابوحینفہ، مالک اور احمد ابن حنبل تھے جنھوں نے اپنے دور کے حکام اور امراء کے خلاف آواز بلند کی یہاں تک کہ وہ اصول و قواعد جن کی بنیاد پر وہ حکام صاحب قدرت بن گئے تھے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا تھا'' النظریات السیاسیة الاسلامیة، ص۷۱ ،پر اور ایک دوسرے مقام پر سیاسی مسائل میں عدم توجہ کے اسباب بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں ''اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد تھا کہ حاکم کے خلاف ایسا قیام جس کی کامیابی کا امکان نہ ہو تو ایسا قیام فتنہ کا باعث، قتل وغارتگریاور ہرج و مرج کا موجب ہے، لہٰذا سیاست سے کنارہ کشی کو پسند کرتے تھے اور علمی مشغولیت کو ترجیح دیتے تھے جس کافائدہ زیادہ اور پایدار تھا'' سابق حوالہ ص۷۱۔ اسی مطلب کی مزید وضاحت میں کہتے ہیں ''اہلسنت نے امامت اور اس سے متعلق تمام مسائل کو خوارج، شیعہ، معتزلہ اور مرجئہ کے لئے چھوڑ دیا کہ جو اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ انھوںنے اپنا وقت اس مسئلہ کے متعلق نظریات اور عقائد کو درست کرنے سے محفوظ رکھا اور اس وقت ان مسائل کو حل کیا جب وہ اس مسئلہ سے فارغ ہوگئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست میں وہ بالکل ہی بیگانہ تھے یا اموی و عباسی سیاست سے راضی تھے'' سابق حوالہ ص۷۰ وضاحت کے لئے رجوع کریں ص۶۹، ۷۵۔
(۱۴۸)اس نکتہ بلکہ ا س لا ینحل مشکل کو ''گب'' بخوبی بیان کرتا ہے: '' اس طرح سے یہ نکتہ کھل کر سامنے آجاتا ہے کہ حالاںکہ خلیفہ کو بھی قانون کی رو سے معزول کیا جاسکتا ہے لیکن جس قانون کے تحت خلیفہ کو برطرف کیا جائے اس کا کوئی وسیلہ موجود نہیںہے۔ مشکل تنہا ماوردی کی نہیں تھی بلکہ اس کے دور تک تمام اہلسنت کے درمیان فکراور تدبر کی مشکل تھی۔ اور یہ نکتہ اس مطلب کی تائید کرتا ہے کہ سنیوں کی سیاسی فکر اور اعتقادی نظریہ پردازی درحقیقت تاریخ امت اسلامی کو عقلانی بنانے کیلے ہے اور اس کے بغیر کوئی نظریہ پردازی اور اندیشہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ مزید وضاحت کے لئے رجوع کریں نظریة الامامة عند الشیعة الامامیة ص۱۶۳۔
(۱۴۹)الفکر السیاسی الشیعی، ص۱۱۶، ۲۶۶۔
(۱۵۰)رجوع کریں سد باب الاجتہاد وما ترتب علیھا ص۵، ۸، یہ اس کتاب کا مؤلف خود علما کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اس کتاب میں حقیقت کو بیان کیا ہے کہ علماء اہل سنت میں فکری و اجتہادی تحرک کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔ نیز باب اجتہاد کے دوبارہ کھلنے کے سلسلہ میںامین کے نظریات۔ ملاحظہ ہوں.
William Shepard The Faith of a Modern
Muslim Intellectual
(۱۵۱)دینی تعلیمی نظام کو جدید قوانین کے قالب میں دھالنے اور اس کے نتائج کے سلسلہ میں الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعمار الغربی نامی کتاب کے ص۱۷۶۔ ۱۸۱، میں عبدہ کے نظریات ملاحظہ ہوں اس قابل توجہ توصیف جس کے مطالعہ سے علماء ازہر کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، اگر ان علما کے ہاتھوں میں کوئی کتاب آجائے اور اس میں ایسے مطالب ہوں جس کا وہ لوگ مطلب نہیں جانتے اور مصنف کی مراد کو سمجھ نہیں پاتے اور اگر اس کے کچھ مطلب کوسمجھ بھی جائیں تو اسے رد کر دیتے اور قبول نہیں کرتے ہیں اور اگر اسے قبول بھی کرلیں تو اسے اپنے علم اور خواست کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں۔بلکہ اس میں تحریف کردیتے ہیں۔ اور خالد محمد خالد کے نظریات کا کتاب الشیعہ فی المیزان ص۳۷۵۔ ۳۷۸ میں مطالعہ کریں۔ نیز کتاب وعاظ السلاطین، ص۲۹۱، ۳۰۲ اور بالخصوص اس کے نتیجہ کو معلوم کرنے کے لئے ''پیامبر و فرعون'' نامی کتاب کا ص۱۰۲، ۱۱۵۔ ملاحظہ ہو
نیز Order in Charles D. Smith Islam and The Search of Social Modern Egypt , PP ۱۰۹-۱۱۳
Fazlur Rahman Islam and Modernity, PP, ۶۳-۷۰
(۱۵۲)کتاب ''پیغمبر و فرعون'' ص۲۷۳، ۲۹۵، میں اس موضوع کے تحت بہترین نمونہ کیلئے النذیر مجلہ کے شماروں کی طرف بالخصوص، ۱۹۸۱، ۱۹۸۵، میں شائع ہوئے مجلوں کی طرف رجوع کریں۔
کتاب کے عربی اور فارسی منابع اور مآخذ کا تعارف
آل کاشف الغطائ، الشیخ محمد حسین: اصل الشیعة و اصولھا، ط۴، بیروت مؤسسہ الاعلامی للمطبوعات، ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲
آل کاشف الغطائ، الشیخ محمد حسین: تحریر المجلة، النجف الاشرف المکتبة المرتضویہ ومطبعتھا الحیدریہ، ۱۳۵۹۔
آیتی، عبد المحمد: ترجمة معلقّات سبع، طبع دوم، تہران، ناشر اشرفی، ۱۳۵۷۔
افغانی، جمال الدین مع الشیخ محمد عبدہ: العروة الوثقی، ط۳، بیروت دارالکتاب العربی، ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳۔
احمد ابن حنبل: مسند، منتخب کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، بدون ناشر، بدون تاریخ۔
کتاب فضائل الصحابہ، تحقیق وصی اللہ بن محمد عباس، ط۱، مرکز البحث العلمی و احیاء التراث اسلامی لجامعہ ام القری ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳۔
کتاب الزھد، تحقیق محمد جلال شریف، دار النھضة العربیة السنة، تحقیق محمد السعید بسیونی زغلول، ط۱، دار الکتب العلمیہ ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵،
ابن الحداد، محمد بن منصور:الجوھر النفیس فی سیاسة الرئیس، تحقیق رضوان السید،ط۱، دارالطیعہ، ۱۹۸۳۔
اسمیت، ویلفرد، کنت ول: اسلا م در جہان امروز، تہران، انتشارات دانشگاہ تہران، ۱۳۵۶۔
ابن جوزی، ابی فرج عبدالرحمن: مناقب الامام احمد بن حنبل، تحقیق عبدالہ بن عبد الحسن الترکی، ط۱، قاہرہ، مکتبة النحانجی، ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹
ابو الفرج الجوزی: کتاب الرد علی المتعصب العنید، تحقیق محمد کاظم المحمودی،۱۴۰۳/۱۹۸۳۔
ابن العربی، ابی بکر:العواصم من القواصم، فی تحقیق موافق الصحابة بعد وفاة النبیصلىاللهعليهوآلهوسلم ، تحقیق محب الدین الخطیب،بیروت المکتبة العلمیة ۱۴۰۵/۱۹۸۵۔
ابو الفرج الصفہانی، علی بن حسین:الاغانی دار احیاء الترات العربی۔
امین، احمد: ضحی الاسلام، ط۷، مکتبة النھضة المصریة، بدون تاریخ
فجر الاسلام، الطبعة الحادیة عشرة، دارالکتاب العربی، ۱۹۷۹۔
ظہر الاسلام، ط۴،مکتبة النہضة المصریة، ۱۹۶۶۔
الامینی النجفی، عبد الحسین احمد: الغدیر فی الکتاب و السنة، ط ۳، دار الکتاب العربی، ۱۳۸۷/ ۱۹۶۷۔
ابن ابی الحدید: شرح نھج البلاغہ، تحقیق ابو الفضل ابراھیم،ط۲، بیروت دار احیاء الکتب العربیہ،۱۳۸۵/ ۱۹۶۵۔
ابن با بویہ، ابی جعفر محمد بن علی: معانی الاخبار، تصحیح علی اکبر غفاری، دار المعرفة،۱۳۹۹/ ۱۹۷۹۔
ابن الاثیر: الکامل فی تاریخ، دارصادر ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲۔
ابن احمد، قاضی عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة، تحقیق عبد الکریم عثمان، ط۱، مکتبہ وھبة، ۱۳۸۴/ ۱۹۶۵۔
ابن قتیبہ الدینوری، ابو محمد عبداللہ بن مسلم: عیون الاخبار، بیروت دارالکتب العلمیة، ط۱، ۱۴۰۶/۱۹۸۶۔
تاویل مختلف الحدیث، تصحیح محمد زھری النجار، بیروت دار الجیل ۱۳۹۳/ ۱۹۷۲۔
الامامة وسیاسة ہو المعروف بتاریخ الخلفائ،مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الجلی واولادہ، ۱۳۸۸/۱۹۶۹۔
ابن قیم الجوزیة: اعلام الموقعین عن رب العالمین، تخقیق طہ عبد الرؤف سعد، دارالجیل، ۱۹۷۳۔
ابن ہشام: السیرة النبوة،تحقیق مصطفی السقائ، دار احیاء التراث العربی۔
الایجی،قاضی عبد الرحمن بن احمد:الموافق فی علم الکلام، عالم الکتب
افندی،قاضی بہلول بہجت: تشریع و محاکمہ در تاریخ آل محمد، ترجمہ میرزا مہدی ادیب، مشہد انتشارات فردوسی، بدون تاریخ۔
الامین الانطاکی، محمد مرعی: رحلتی من الضلال الی الہدی، بدون ناشر بدون تاریخ۔
لماذ اخترت مذہب الشیعة، بیروت، مؤسسہ الاعلامی للمطبوعات، بدون تاریخ۔
ایزوتسو، توشی ھیکو: ساختمان معنایی مفاھیم اخلاقی، دینی درقرآن، ترجمہ فریدون بدوہ ای، تھران، انتشارات قلم،۱۳۶۰۔
ایزوتسو، توشی ھیکو: خدا و انسان در قرآن، ترجمہ احمد آرام، چاپ دوم دفتر نشر و فرہنگ اسلامی، ۱۳۶۸۔
الافغانی، سعید: من الحاضر اللغة العربیة، ط۲، بیروت دار الفکر، ۱۹۷۱
ابو یوسف، قاضی: الخراج دارالمعرفة للطباعة والنشر، ۱۳۹۹، ۱۹۷۹
ارموی، میر جلال الدین حسین (محدث): تعلیقات نقض، تہران، انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۵۸۔
ابن جُزَّی: القوانین الفقھیة، دار الفکر، بدون تاریخ۔
ابن خلدون، عبدالرحمن: مقدمة ابن خلدون، ترجمہ پروین گنا بادی، شرکت انتشارات علمی و فرہنگی، ۱۳۶۶۔
الب تکین، عیسی یوسف: قضیة ترکستان الشرقیة، ترجمہ اسماعیل حقی شن کولر مؤسسہ مکة للطباعة والاعلام، ۱۳۹۸/۱۹۸۷۔
اطغیش، محمد یوسف: ازالة الاعتراض عن محقی آل اباض، مسقط یوزارة التراث القومی والثقافة، لسلطنة عمان، ۱۹۸۲۔
ابن رشید القرطبی، محمد بن احمد: بدایة المجتھد و نھایة المقتصد، قم منشورات الشریف الرضی، ۱۴۰۶۔
ابن تیمیة، ابو العباس احمد: منھاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة والقدریة، مطبعة الکبری الامیریة، ط۱، ۱۳۲۱۔
اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم، تحقیق محمد حامد الفقی، بیروت دارالمعرفة، بدون تاریخ۔
السیاسة الشرعیة فی اصلاح الراعی والرعیة، تحقیق لجنة احیاء التراث العربی، بیروت دارالجیل، ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸۔
ابن الشعبة الحرانی، ابو محمد: تحف العقول، بیروت مؤسسہ اعلامی للمطبوعات، ۱۳۹۴/۱۹۷۴۔
ابن حزم، ابی محمد علی بن احمد: الملّی، تحقیق لجنة احیاء التراث العربی، دارالدقاق الجدیدة۔
ابن حزم، ابی محمد علی بن احمد: الفصل فی الملل والاھواء والنحل، تحقیق محمد ابراھیم نصر دار الجیل، ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵۔
الاشعری، ابی الحسن علی بن اسمعیل: الابانة عن اصول الدیانة دار الکتاب العربی، ۱۴۰۵/۱۹۸۵۔
ابن الجوزی البغدادی:ابی الفرج عبد الرحمن: تلبیس ابلیس، بیروت دار القلم، ۱۴۰۳۔
محمد بن ابو یعلی، قاضی ابوالحسن طبقات الحنابلة، تحقیق محمد حامد الفقی، قاہرہ، مطبعة السنتہ المحمدیة۱۳۷۱/۱۹۵۲۔
احداعضاء ماجمعیات السّریة العربیة: ثورة العرب ضد الاتراک، مقدماتھا اسبابھا، نتایجھا: تحقیق عصام محمد شبارو، بیروت دار مصباح الفکر، ۱۹۸۷۔
البنائ، حسن: خاطرات زندگی حسن البنائ، ترجمہ ایرج کرمانی، تہران دفتر نشر و فرہنگ اسلامی ۱۳۶۶۔
بار تولد: خلیفہ و سلطان مختصری دربارہ برمکیان، ترجمہ سیروس ایزدی، تہران انتشارات امیر کبیر ۱۳۵۸۔
البدری، عبدالعزیز، الاسلام بین العلماء و الحکام، المدینہ المنورة، الکتبة العلمیة ۱۹۶۶۔
البھی، محمد: الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعمار الغربی، ط۵، بیروت دارالفکر، ۱۹۷۰۔
بغدادی، محمد بن نعمان عکبری: امالی شیخ مفید، ترجمہ حسن استاد ولی، مشھد بنیاد پژوہشھای اسلامی، ۱۳۶۴۔
تافلر الوین: موج سوم، ترجمہ شھیندخت خوارزمی، تہران نشر نو، ۱۳۶۲۔
التیجانی السماوی، محمد: ثم اہتدیت، لندن، مؤسسہ الفجر ۱۹۸۸۔
التونسوی، عبد الستار: مناقب الخلفاء الاربعة فی مؤلفات الشیعة تعریب محمد سلیم شاہ، فیض آبادی دار النشر الاسلامیة العلمیة، ۱۴۰۳۔
الجندی، انور: العالم الاسلامی والاستعمار السیاسی والاجتماعی والثقافتی، ط۲، دارالکتاب اللبنانی، ۱۹۸۳۔
مؤلفات فی المیزان، وزارة الشئون الاسلامیة والاوقاف لدولة الامارات العربیة المتحدة، بدون تاریخ۔
الجرجانی، السید الشریف علی بن محمد، مع حاشیتین من عبد الکریم السیالکوتی و مولی حسن چلبی، شرح المواقف، تصحیح السید بدرالدین النعنانی، مطبعة السعادة، ۱۳۲۵۔
الجزیری، عبدالرحمن: کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعة، استامبول دار الدعوة، ۱۹۸۷۔
الجاحظ، ابی عثمان عمر و بن بحر بن محبوب: البیان والتبین، تحقیق حسن السندوبی، ط۱، مطبعة التجاریة الکبری، ۱۳۴۵/۱۹۲۶۔
حائری، عبد الھادی نخستین رویا روئیھای اندیشہ گران ایران بادو رویہ تمدن بورژوازی غرب، تھران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۷۔
حنفی، حسن: من العقیدة الی الثورة، ط۱، بیروت دار التنویر للطباعة والنشر والمرکزالثقافی العرب للطباعة وللنشر، ۱۹۸۸۔
الحسنی، ھاشم معروف: الانتفاضات الشیعة عبر التاریخ، قم، منشورات الرضی، ۱۴۰۴۔
الحرالعاملی، شیخ محمد بن حسن: وسائل الشیعة الی تحصیل المسائل الشریعة، تحقیق و نشر مؤسسہ آل بیت(ع) لاحیاء تراث، قم، ۱۴۰۹۔
حسن، حسن عباس: الفکر السیاسی الشیعی، الاصول و المبادی، ط۱، بیروت دارالعلمیة للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۹۸۸۔
حسین، طہ: الاسلامیات، ط۴، بیروت دار العلم للملایین، ۱۹۸۴۔
حسین، طہ: آن روزھا، ترجمہ حسین خدیوجم، تہران، انتشارات سروش، ۱۳۶۳۔
خالد، خالد محمد: رجال حول الرسول، ط۲، دار الکتاب العربی۱۹۷۳۔
خلیفات، عوض محمد: الاصول التاریخیة للفرقة الاباضیة، ط۲، مسقط وزارة التراث القومی والثقافة لسلطنة عمان، بدون تاریخ۔
الخالدی، محمود: معالم الخلافة فی الفکر السیاسی الاسلامی، ط۱، عمان مکتبة المتحسب، ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴۔
الخبّاص، عبداللہ عوض: سید قطب الادیب الناقد، ط۱، امان، مکتبة المنار، ۱۹۸۳۔
الخوانساری، السید احمد: جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ط۲، مکتبة الصدوق، ۱۳۵۵۔
الخطیب، عبدالکریم: الخلافة و الامامة، دیانتہ و سیاستہ، دارسة مقارنة للحکم والحکومة فی الاسلام، ط۲، دار المعرفة، ۱۳۹۵/ ۱۹۷۵۔
عمر بن الخطاب، الوثیقة الخالدة للدین الخالد، ط۱، دار الفکر العربی ۱۹۷۸۔
سد باب الاجتھاد و ماترتّب علیہ ط۱، بیروت مؤسسہ الرسالة، ۱۴۰۵ ۱۹۸۵۔
الدرینی، محمد فتحی: خصاص التشریع الاسلامی فی السیاسة و الحکم، ط۱، بیروت مؤسسہ الرسالة، ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲۔
دومان، ھانری: فرانسوی مارکسیسم، ترجمہ منو چھربیات مختاری، تھران، انتشارات دانشگاہ تھران، ۱۳۵۵۔
الدزفولی، الشیخ حیدر بن المولی: صلوة الجمعة، دزفول، مکتبة الشیخ الانصاری، ۱۴۰۷۔
دانکوس، ھلن کار: امپراطوری فروپاشیدہ، ترجمہ عباس آگاھی، معاونت فرہنگی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۶۔
ریوکین، مایکل: حکومت مسکوو مسئلہ مسلمانان آسیای مرکزی شوروی، مترجم محمود رمضان زادہ، مشھد بنیاد پژو ھشھای اسلامی، ۱۳۶۶۔
الرئیس، محمد ضیاء الدین: الاسلام والخلافة فی عصر الحدیث، نقد کتاب الاسلام و اصول الحکم، ط ا، منشورات العھد الحدیث، ۱۳۹۳/ ۱۹۷۳
الزھرانی، محمد مسفر: نظام الوزارة فی الدولة العباسیة: العھدان البویھی و السلجوقی، مؤسسہ الرسالة، ۱۴۰۰/ ۱۹۸۰۔
السبحانی، الشیخ جعفر: الملل والنحل: محاضرات، قم، مرکز مدیریت حوزہ علمیہ قم، ۱۴۰۸۔
السیوطی، جلال الدین: تاریخ الخلفائ، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، ط۱، مطبعة السعادة، ۱۳۷۱/ ۱۹۵۲۔
سلیمان معروف، احمد: قرائة جدیدة فی موقف الخوارج وفکرھم و ادبھم، ط۱، دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمہ والنشر، ۱۹۸۸۔
الشھرستانی، عبد الکریم: الملل و النحل، تحقیق محمد سید کیلانی، دار المعرفة، ۱۴۰۲ /۱۹۸۲۔
شرف الدین الموسوی، عبد الحسین: المراجعات، تھران، مؤسسہ البکئہ بدون تاریخ۔
النص والاجتھاد، تحقیق ابو مجتبی، ط۱، قم، مطبعة سید الشھدا ۱۴۰۴
شمس الدین، محمد مھدی: ثورة الحسین، ظروفھا الاجتماعیة و آثارھا الانسانیة، ط۵، قم، دار المثقف المسلم، ۱۹۷۸۔
الشاطبی الغرناطی، ابن اسحق ابرایم بن موسی: الاعتصام، دار الفکر۔
الشکعة، مصطفی: الائمة الاربعة، ط۱، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، ۱۴۰۲/۱۹۸۳۔
الصالح، صبحی: النظم الاسلامیة، نشاتھا و تطورھا، ط۲، دار العلم للملایین، ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸۔
صبحی، احمد محمود: نظریة الامامیة لدی الشیعة الاثنی عشریة، تحلیل فلسفی للعقیدة، قاھرہ، دار المعارف بمصر۔
طہرانی، الشیخ آقا بزرگ: تاریخ حظر الاجتہاد، خوانسار، مدرسہ الامام المہدی، ۱۴۰۱۔
طبری، ابی جعفر محمد بن جریر: تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم و الملوک، ط۴، بیروت مؤسسہ الاعلامی للمطبوعات، ۱۹۸۳۔
الطوسی ابی جعفر محمد بن محمد بن الحسن نصیرالدین: تجرید العقائد، تحقیق محمد جواد حسینی الجلالی، ط۱، مرکز النشر مکتب الاعلامی الاسلامی، ۱۴۰۷۔
الظھیری، السمر قندی، محمد بن علی: اغراض السیاسة فی اعراض الریاسة، تصحیخ جعفر شعار، تہران، انتشارات دانشگاہ تھران، ۱۳۴۹۔
عثمان، محمد فتحی: من اصول الفکر السیاسی الاسلامی، ط۱، مؤسسہ الرسالة، ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹۔
عسکری، سید مرتضی: نقش عایشہ در تاریخ اسلام، ترجمہ عطاء اللہ سردار نیا ودیگر افراد، نشر کوکب، ۱۳۶۷۔
عطیہ، عزت علی: البدعة، تحدیدھا و موقف الاسلام منھا، ط۲، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰/ ۱۹۸۰۔
العامر، عبد الطیف: الحرکة الاسلامیة فی الجزیرة العربیة، ط۱، منظمة الثورة الاسلامیة فی الجزیرة العربیة، ۱۴۰۶۔
عبدالرزاق، علی: الاسلام و اصول الحکم، دراسة، ووثاق بقلم محمد عمارہ، ط۱، بیروت المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ۱۹۷۲۔
عنایت، حمید: اندیشہ سیاسی در اسلام معاصر، ترجمہ بھاء الدین خرمشاھی، چ۱، تھران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۲۔
عطوان، حسین: الزندقة والشعوبیة فی العصر العباسی الاول، بیروت دار الجیل، ۱۹۸۴۔
الامویون والخلافة، ط۱، بیروت دارالجیل، ۱۹۸۶۔
غزالی، امام محمد: ایھا الولد، ترجمہ باقر نجاری، بخش فرہنگی دفتر مرکزی جھاد دانشگاہی، ۱۳۶۴۔
الغزالی، ابی حامد بن محمد: احیاء علوم الدین، ط۱، بیروت دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۶/۱۹۸۶۔
الغزالی، ابی حامد بن محمد: الاقتصاد فی الاعتقاد، تحقیق محمد مصطفی ابوالعلائ، قاہرہ، مکتبة الجندی، ۱۳۹۳/۱۹۷۲۔
الغزالی، محمد: السنة النبویة بین اھل الفقہ و اہل الحدیث، ط۱، دار الشروق، ۱۴۰۹/۱۹۸۹۔
فقیھی، علی اصغر: وھابیان، برسی و تحقیق گونہ ای دربارہ عقائد و تاریخ فرقہ وھابی، تھران، انتشارات اسماعلیان، ۱۳۶۴۔
قطب، سید: معالم فی الطریق، دار الشرق، بدون تاریخ۔
قدامة، احمد بن محمد: المغنی ویلیہ الشرح الکبیر لشمس الدین ابی الفرج، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۳/۱۹۸۳۔
قزوینی رازی، عبد الجیل: نقض معروف بہ بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض، تصحیح میر جلال الدین محدث، تھران انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۵۸۔
الکرکی، شیخ علی بن الحسین: رسائل المحقق الکرکی، قم مکتبة السید المرعشی النجفی، ۱۴۰۹۔
جامع المقاصد فی شرح القواعد، تحقیق و نشر مؤسسہ آل بیت(ع)الاحیاء التراث، ۱۴۰۸۔
کوپل، ژیل: پیامبر و فرعون، جنبشھای نوین اسلامی در مصر، ترجمہ حمید احمدی، طبع اول، تھران، انتشارات کیھان، ۱۳۶۶۔
گوکالب، ضیائ: ناسسیو نالیسم ترک و تمدن باختر، ترجمہ فریدون بازرگان، تھران مؤسسہ فرھنگی منطقہ ای، ۱۳۵۱۔
المنقری، نصری مزاحم: وقعة صفین، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، قم، مکتبہ بصیرتی، ط۲، ۱۳۸۲۔
الموسوی المقرم، عبد الرزاق: مقتل الحسین او حدیث کربلا، ط۵، قم، مکتبہ بصیرتی، ۱۳۹۴۔
المسعودی، ابن الحسن علی بن الحسین: التنبیہ و الاشراف، تصحیح عبداللہ اسمعیل الصاوی قاھرہ، دارالصاوی للطبع والنشر والتالیف، بدون تاریخ
المظفر، الشیخ محمد حسین: دلائل الصدق فی الجواب عن (ابطال الباطل) الذی وضعہ الفضل بن روزبھان للرد علی (نھج الحق) للآیة ۱۔۔۔
العلامة الحلی (قدہ) فی المسائل الخلافیة بین فرقتی الاسلام الشیعة والسنة، ط۱، مکتبہ بصیرتی، ۱۳۹۵۔
الماوردی: ادب الدنیا والدین، تحقیق مصطفی السقائ، ط۴، دار الکتب العلمیہ، ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸۔
الماوردی (البصری البغدادی)، ابی الحسن علی بن محمد: الکلام السلطانیہ والولایات الدینیہ، قم، مرکز النشر مکتب الاعام الاسلامی، ۱۴۰۶۔
المرتضی، احمد بن یحیی: طبقات المعتزلة، تحقیق سنوسنہ دیفلد، فلرز، فیسبادن، فراتر ستانیر، ۱۹۸۷۔
الموسوی، عبد الحسین شرف الدین: الفصول المھمة فی تالیف الامة، ط۳، قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۴۔
المسعودی، ابی الحسن علی بن الحسین: مروج الذھب و معادن الجوھر، تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، دار المعرفة، ۱۴۰۴/ ۱۹۸۴۔
المبارک، محمد: الفکر الاسلامی، الحدیث فی مواجھة الافکار الغربی، بیروت ۱۹۷۱۔
محمد مسجد جامعی: سیر تحویلی وھابیت، وھابیت در عربستان امروز، تھران ۱۳۶۴۔
آفریقا، میراث گذشتہ و موقعیت آیندہ، تھران، انتشارات الھدی ۱۳۶۸
تحول و ثبات، تھران، انتشارات الھدی، ۱۳۶۸۔
ایدئولوژی و انقلاب، بی جا، بی نا، ۱۳۶۱۔
محمصانی، صبحی: تراث الخلفاء الراشدین فی الفقہ و القضائ، ط۱، بیروت دار العلم للملایین، ۱۹۸۴
منتظری، حسین علی: البدر الزاھر فی صلوة الجمعة و المسافر، قم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۲۔
النجفی، الشیخ محمد حسن: جواہر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تحقیق الشیخ عباس قو چانی، ط۷، دار الاحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱۔
الندوی، ابر الحسن: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، ط۱۰، کویت دارالقلم، ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷۔
نائینی، شیخ محمد حسین: تنبیہ الامة و تنزیة الملة، تو ضیحات از سید محمود طالقانی، چھٹا ایڈیشن، تھران، شرکت سھامی انتشار، ۱۳۵۹۔
النوری الطبرسی، مرزا حسین: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق مؤسسہ آل بیت(ع) الاحیاء التراث، ۱۴۰۷۔
الوزیر الیمانی، محمد بن ابراھیم: العواصم والقواصم فی الذّب عن سنة ابی القاسم، تحقیق شعیب الارنؤوط، الجز الثالث، عمان، دارالبشیر ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷۔ھالیدی، فرد: دیکتاتوری و توسعہ، ترجمہ محسن یلفانی و علی طلوع، تھران، انتشارات علم، ۱۳۵۸۔
الھندی، علی المتقی بن حسام الدین: کنزالعمال فی الاقوال و الافعال، تحقیق الشیخ بکری حیاّنی، ط۵، مؤسسہ الرسالة، ۱۴۰۵۔
کتاب کے مغربی(انگریزی )منابع اورمآخذ کاتعارف
Asaf. Hussain: Islamic movements in Eygpt, Palistian and Iran: an Annotated Bibliogrophy, London, Mansell Pulishing Co, ۱۹۸۳ ,
Cole, J.R.I: Roots of North Indian Shi'sm in Iran and Iraq, Religion and state in
Awadh, ۱۷۲۲ _۱۸۵۹, Oxford University Press, ۱۹۸۶
Coulson, N. J.: Islamic Surveys, A History of Islamic Law, Edinburgh, Edinburgh University Press, ۱۹۷۱
deutschmann, David: Che Guevara and the Cuban Revolution, Writings and Speeches of Ernest CheGuevare, Sydney, Path Finder, ۱۹۸۷
Daniel, Dorman: Islam and the west. The Making of an Image, Edinburgh, Edinburgh University Press, ۱۹۸۰
Gibb ,Sir Hamilton and Harold Bowen: Islamic Socity and the West, London, Oxford University Press, ۱۹۶۳
Gibb, H.A.R.: Mohammedansim, Oxford, Oxford University Press, ۱۹۵۳
Goldziher, Ignaz: The Zahiris, Their Doctorine and their history, Acontribution to the History of Islamic theology, Leiden, E.J.Brill, ۱۹۷۱
Grunebaum.G.E.Von: Islam, Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition, London, Routledge, Kegan Paul LTD, ۱۹۶۹
Grunebaum,G.E.Von: Medieval Islam, A Study in Cultural Orientation, Chicago, the University of Chicago Press, ۱۹۶۹
Ibrahim, SaadEddin: The New Arab Social Order ,A Study of the Social Impact to oil welth, west view Press, ۱۹۸۲
Jafri ,S.H.M.: The Original of Early Development of Shi'a Islam, London, Lonndon Group, LTD, ۱۹۷۹
kung Hang: On Being a Christian, translated by Edward Quinn, Collins London, ۱۹۷۷
Laffin, John: The Dagger of Islam, Sphere books, LTD, ۱۹۷۹
Muri, Sir William, K.C.S.I.: The Caliphate, its Rise, Decline, and fall, London, Darf
Publishers,LTD, ۱۹۸۴
Morimer, Edward: Faith and power, The Politics of Islam, london, Faber and Fabr, ۱۹۸۲
Stemple, John D.: Inside the Iranian Revolution, Bloomington, Indiana niversity Press,۱۹۸۱
Sardar, Ziauddin: Islamic Futures, The Shape of Ideas to Come, Mansell, Publishing Limited, ۱۹۸۵
Smith, Charls D: Islam and the Search for Social Order in Modern Eygpt, A Biography of Muhammad Hussain Haykal, N. Y.State University of NewYork Press, ۱۹۸۳
Sheppard William,: The Faith of a Modern Muslim Intellctual, the Religious AS pects and Implication of the Writings of Ahmad Amin, New Delhi, Vihas Publishing House,۱۹۸۲
Saddiqi, Amir. H. : Caliphate and Kingship in Medieval Persian, Philadelphia, Porcupine Press, Inc,۱۹۷۷
Flahnery, Austin, O. P.(Ed), Vatican Council ۲nd, The Conciliar and Post concilar Documents, Dullin, Duminican Publications, ۱۹۷۵
فہرست
مقدمہ ناشر ۴
مقدمہ مؤلف ۶
پہلی فصل ۱۰
دور حاضر کی دینی تحریکیں ۱۰
شیعہ اور سنی حضرات کے سیاسی افکار کے سرچشمے ۱۲
مختلف نظریات ۱۴
دینی قیادت ۱۷
شخصیات اور دانشوروں کی حکومت ۲۰
جو ا نوں کا میدان میں وا رد ہو نا ۲۴
مشر قی سیاسی محاذ (( Bloc میں تبدیلیاں ۲۷
توسیع اور ترقی کا بر ابر اور خلّا ق نہ ہو نا ۲۹
قدیمی وراثتوں کے بارے میں حساسیت ۳۱
گذشتہ حقائق کی تلاش ۳۳
اسلام، عیسا ئیت اور تمدن جدید ۳۴
دو با رہ پلٹنا ۳۸
عقید تی اختلا فات کی جڑیں (بنیادیں) ۴۱
پہلی فصل کے حوالے ۴۳
دوسری فصل ۵۲
فہم تاریخی ۵۲
صدر اسلام کی تاریخ پر ایک نظر ۵۲
ابوبکر کا انتخاب ۵۳
نیا رنگ اختیار کرنا ۵۵
خاندانی چپلقش ۵۸
عمر کی سیاسی جد و جہد ۶۰
بیرونی دھمکیاں ۶۱
ایک نئی موقعیت ۶۵
عثمان کا اقتدار حاصل کرنا ۶۶
عمیق اور تیز بدلاؤ ۶۷
ایک عظیم بحران ۷۰
ایک عمومی نظریہ ۷۱
حضرت علیـ اور قبولِ خلافت ۷۳
روحی پریشانیاں ۷۴
معاشرہ اور سماج کا درہم برہم ہونا ۷۷
مشکلات کا سرچشمہ ۷۹
حقیقت کی بدلتی ہوئی تصویر ۸۱
حضرت علیـ سے مقابلہ آرائی ۸۳
مقام صحابہ کا اتنا اہم ہوجانا ۸۷
دین فہمی میں بدلاؤ ۸۸
دوسرے تنقید کرنے والے ۹۱
فکری اوراعتقادی نتائج ۹۲
دوسری فصل کے حوالے ۹۷
تیسری فصل ۱۱۳
حکومت اور حاکم ۱۱۳
خلافت کی اہمیت ۱۱۴
صدر اسلام کا تقدس پانا ۱۱۷
جدید مسائل ۱۱۹
نفسیاتی جاذبے و قلبی کشش ۱۲۱
صریح اور واضح فیصلہ کی قدرت کا نہ ہونا ۱۲۵
واقعۂ عاشورا کے بالمقابل سکوت اختیار کرنا ۱۲۷
نئے تجربہ کی روشنی میں نیا ادراک ۱۳۲
سید قطب کی راہ گشائی ۱۳۳
سید قطب کے افکار کی اہمیت ۱۳۶
تاریخی تنقیدوں کی خطا ۱۳۸
عبد الرزاق کا تاریخی تصور ۱۴۱
حاکم کی بہ نسبت اہل سنت کا نظریہ ۱۴۶
حکومت اور حاکم ۱۴۸
شیعوں کا موقف ۱۵۰
دو نظریئے ۱۵۳
قضا اور قدر کا مسئلہ ۱۵۶
قدیم ایام میں اعراب کی خداشناسی ۱۶۰
جبر کے رجحان کی تبلیغ ۱۶۳
تاریخی شواہد (نمونے) ۱۶۶
جعل حدیث ۱۶۸
مرجئہ کی فکر ۱۷۱
تیسری فصل کے حوالے ۱۷۴
چوتھی فصل ۱۸۹
قدرت اور عدالت ۱۸۹
مفہوم عدالت ۱۹۰
دو مختلف تفسیروں کے نتائج ۱۹۱
عدالت کا فقہی مفہوم ۱۹۳
شرط عدالت کا انکار ۱۹۷
شرطِ عدالت کے انکار کی اہمیت ۱۹۸
عمل اور اس کے شرائط ۲۰۲
حکومت کی ذمہ داریاں ۲۰۷
دارالاسلام کی وسعت ۲۰۹
عیسائی طاقتوں کی دھمکی ۲۱۱
قدرت اور امنیت ۲۱۳
غزالی کا نظریہ ۲۱۴
حفظ نظام ۲۱۶
ابن قیم کا نظریہ ۲۱۸
عدالت خواہی اور قدرت طلبی ۲۲۰
انقلابی پوشیدہ توانائیوں کے مقامات ۲۲۱
انسان میںفداکاری کا جذبہ ۲۲۲
حاکم نظام کا طرز تفکر ۲۲۵
جدید اعتراضات ۲۲۶
شیعہ کا موقف ۲۲۸
شیعہ علما اور صفوی سلاطین ۲۳۱
شیعوں کی گوشہ نشینی اور اس کے نتائج ۲۳۲
دباؤ اور نئی ضرورتیں ۲۳۴
اسلامی حکومت کی فکر ۲۳۸
خلافت کا خاتمہ ۲۳۹
مغربی قوانین کا نفوذ ۲۴۲
شریعت کی مطابقت ۲۴۴
چوتھی فصل کے حوالے ۲۴۸
کتاب کے عربی اور فارسی منابع اور مآخذ کا تعارف ۲۶۷
کتاب کے مغربی(انگریزی )منابع اورمآخذ کاتعارف ۲۷۴