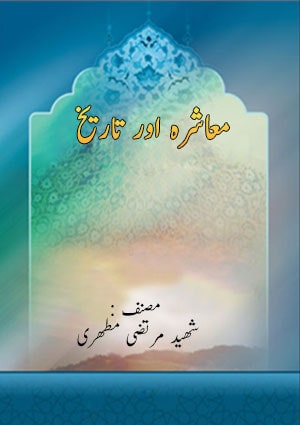یہ کتاب برقی شکل میں نشرہوئی ہے اور شبکہ الامامین الحسنین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں تنظیم ہوئی ہے
معاشرہ اور تاريخ
مؤلف : مطہرى، مرتضيٰ (آیۃ اللہ شهید)
پيش لفظ
كوئي مكتب معاشرے اور تاريخ كے بارے ميں كيا نظريہ ركھتا ہے اور ان دونوں سے كيا اخذ كرتا ہے، يہ امر اس مكتب كے تصور كائنات ميں فيصلہ كن كردار ادا كرتا ہے ۔ لہٰذا ضروري ہے كہ اسلامي تصور كائنات كو پيش نظر ركھتے ہوئے يہ واضح ہو كہ معاشرے اور تاريخ كو اسلام كس انداز سے ديكھتا ہے ۔
يہ امر واضح ہے كہ اسلام عمرانيات ( Socialogy ) كا كوئي مكتب ( School Of Thought ) ہے، نہ فلسفہ تاريخ ہے ۔ اسلام كي آسماني كتاب ميں معاشرے يا تاريخ سے متعلق كوئي ايسي گفتگو نہيں جو عمرانيات اور فلسفہ تاريخ كي مروجہ زبان ميں ہو، يہ بالكل اسي طرح ہے جس طرح اس ميں اخلاقى، فقہى، فلسفي اور ديگر علوم سے متعلق مفاہيم رائج زبان اور ان كي اصطلاحات ميں بيان نہيں ہوئے جو ان علوم كا خاصہ ہيں ۔ تاہم ان علوم سے وابستہ بہت سے مسائل كامل طور پر اس سے اخذ كئے جا سكتے ہيں اور قابل استنباط ہيں ۔
معاشرہ تاريخ چونكہ باہم مربوط موضوع ہيں، علاوہ ازيں ہم ان كے بارے ميں اختصار سے گفتگو كرنا چاہتے ہيں، لہٰذا ہم نے انہيں ايك ہي فصل ميں قرار ديا ہے ۔ ان دونوں كے بارے ميں اسلامي نقطہ نظر خاص اہميت كا حامل ہے، جسے مطالعے اور تحقيق كا عنوان قرار ديا جانا چاہيے، البتہ ہم معاشرے اور تاريخ سے مربوط مسائل كو اسي قدر اٹھائيں گے جس قدر ہمارے خيال ميں مكتب اسلام كي شناخت كے لئے ضروري ہے ۔
پہلے ہم معاشرے پر گفتگو كريں گے اور پھر تاريخ كو موضوع بحث بنائيں گے ۔ معاشرے كے مسائل يہ ہيں ۔
۱۔ معاشرہ كيا ہے؟
۲۔ كيا انسان مدني الطبع ہے؟
۳۔ كيا فرد كو اصليت حاصل ہے اور معاشرے كي حيثيت انتزاعي اور ضمني ہے يا اس كے برعكس معاشرہ اصليت ركھتا ہے اور فرد كي حيثيت انتزاعي اور ضمني ہے يا پھر كوئي تيسري صورت ہے؟
۴۔ معاشرہ اور اس كے قوانين و آداب ۔
۵۔ كيا فرد معاشرے اور اجتماعي ماحول كے آگے بے بس ہے يا مختار؟
۶۔ اپني ابتدائي تقسيم كے اعتبار سے معاشرہ كن شعبوں، سمتوں اور كن گروہوں ميں تقسيم ہوتا ہے؟
۷۔ كيا انساني معاشرے ہميشہ ايك ہي ماہيت اور ايك ہي نوعيت كے ہوتے ہيں اور ان كے درميان اختلاف كي صورت ايسي ہے جيسي ايك ہي نوع (يہاں پر لفظ ”نوع“ علم منطق كے اصطلاحي مفہوم ميں آيا ہے ۔ ايك ہي نوع كے افراد ماہيت كے اعتبار سے بالكل ايك جيسے ہوتے ہيں ۔ مترجم) سے تعلق ركھنے والے افراد كے مابين ہوتي ہے يا پھر جغرافيہ اور زمان و مكان كے فرق كے اعتبار سے نيز ثقافت و تمدن ميں تغير كے لحاظ سے معاشرے مختلف النوع ہوتے ہيں، يوں ان كي عمرانيات بھي مختلف ہوجائے گي ۔ پھر ہر نوع كا اپنا خاص دوسروں سے مختلف مكتب بھي ہو سكتا ہے ۔ دوسرے لفظوں ميں كيا جس طرح تمام انسان علاقائى، نسلي اور تاريخي اختلافات كے باوجود جسم كے اعتبار سے واحد نوعيت كے حامل ہيں اور ان پر ايك ہي طرح كے فزيالوجيكل اور طبي قوانين حكم فرما ہيں، اجتماعي لحاظ سے بھي واحد نوعيت كے حامل ہيں اور ايك ہي اخلاقي و اجتماعي نظام ان پر لاگو كيا جا سكتا ہے اور بشريت پر ايك ہي مكتب حاكم ہو سكتا ہے يا ہر معاشرہ خاص جغرافيائى، ثقافتي اور تاريخي حالات كے تحت اپني خاص عمرانيات ركھتا ہے اور ايك خاص مكتب كا متقاضي ہے؟
۸۔ كيا انساني معاشرے ابتدائے تاريخ سے عصر حاضر تك پراگندہ صورت ميں اور ايك دوسرے سے جدا حيثيت كے ساتھ موجود رہے ہيں اور ان پر كثرت و اختلاف حكم فرما رہا ہے، (نوعي اختلاف نہ ہو تو كم از كم انفرادي اختلاف رہا ہے) اور وحدت و يكتائي كي طرف بڑھ رہے ہيں اور بشريت كا مستقبل واحد معاشرہ، ايك تمدن، ايك ثقافت اور آخر كار بشريت كے يك رنگ و يك شكل ہوجانے سے عبارت ہے اور تضاد و تراجم تو ايك طرف اصلاً دوئي ختم ہوجائے گي يا پھر بشريت مجبور ہے كہ اس كے متعدد رنگ رہيں، مختلف صورتيں رہيں، ثقافت و تمدن اور جن امور پر انسان كا وجود اجتماعي قائم ہے ان ميں اختلاف رہے؟
يہ وہ مسائل ہيں جن كے بارے ميں ہمارے نزديك اسلامي نقطہ نظر پيش كرنا انتہائي ضروري اور اہم ہے ۔ ذيل ميں ہم ترتيب كے ساتھ اختصار كو ملحوظ ركھتے ہوئے ان امور پر گفتگو كريں گے ۔
معاشرہ كيا ہے؟
انسانوں پر مشتمل وہ جماعت جو خاص قوانين، خاص آداب و رسوم اور خاص نظام كي حامل ہو اور انہي خصوصيات كے باعث ايك دوسرے سے منسلك اور ايك ساتھ زندگي گذارتي ہو، معاشرہ تشكيل ديتي ہے ۔ ايك ساتھ زندگي گذارنے كا صرف يہ مطلب نہيں كہ انسانوں كي كوئي جماعت كسي علاقے ميں باہم مشترك زندگي گذارنے اور ايك ہي آب وہوا اور ايك جيسي غذا سے يكساں استفادہ كرے ۔ يوں تو ايك باغ كے درخت بھي ايك دوسرے كے ساتھ پہلو بہ پہلو زندگي بسر كرتے ہيں اور ايك ہي آب و ہوا اور ايك جيسي غذا سے استفادہ كرتے ہيں ۔ يہي حال ايك ہي گلے كے ہر جانور كا بھي ہوتا ہے جو ايك دوسرے كے ساتھ مل كر چرتے ہيں اور باہم مل كر نقل مكاني بھي كرتے ہيں ليكن ان ميں سے كوئي بھي اجتماعي اور مدني زندگي نہيں ركھتا، نہ معاشرہ تشكيل ديتا ہے ۔
انسان كي زندگي اجتماعي يا معاشرتي اس معني ميں ہے كہ وہ ايك ”اجتماعي ماہيت“ كي حامل ہے ۔ ايك طرف تو اس كے مفادات، اس كے تعلقات اس كے كام كاج ”اجتماعي ماہيت“ ركھتے ہيں اور اپنے رسم و رواج كے دائرے ميں تقسيم كار، تقسيم مفادات اور ايك دوسرے كي مدد كے بغير اس كا گذارہ نہيں، دوسري طرف كچھ ايسے افكار، نظريات اور مزاج بھي لوگوں پر حاكم ہيں جو انہيں وحدت و يگانگت بخشتے ہيں ۔ دوسرے لفظوں ميں معاشرہ انسانوں كے اس مجموعے كا نام ہے جو ضروتوں كے جبري سلسلے ميں اور عقائد نظريات اور خواہشات كے زير اثر ايك دوسرے ميں مدغم ہيں اور مشترك زندگي گذار رہے ہيں ۔
مشترك معاشرتي ضرورتوں اور زندگي سے متعلق خصوصي تعلقات نے نوع انساني كو اس طرح ايك دوسرے سے منسلك كر ديا ہے اور زندگي كو اس طرح وحدت اور يكتائي بخشي ہے جيسے حالت سفر ميں كسي گاڑي يا جہاز كے مسافر ہوا كرتے ہيں جو ايك مقصد كي سمت آگے بڑھتے ہيں، ايك ساتھ منزل پر پہنچتے ہيں يا ايك ساتھ رہ جاتے ہيں، ايك ساتھ خطرے ميں گھرتے ہيں اور ان سب كي تقدير ايك جيسي ہو جاتي ہے ۔
رسول اللہ صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہي عن المنكر كا فلسفہ بيان كرتے ہوئے كتني اچھي مثال پيش كى، فرمايا:
”چند لوگ ايك بحري جہاز ميں سوار ہوئے، جہاز سمندر كا سينہ چيرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، ہر مسافر اپني نشست پر بيٹھا تھا ۔ اتنے ميں ايك شخص اس عذر سے كہ جس جگہ وہ بيٹھا ہے اس كي اپني جگہ ہے اور وہ اپني جگہ جو چاہے سو كرے، كسي چيز سے اس جگہ سوراخ كرنے لگا ۔ اگر تمام مسافر وہيں اس كا ہاتھ پكڑ ليتے اور اسے اس كام سے باز ركھتے تو نہ خود غرق ہوتے اور نہ اسے غرق ہونے ديتے ۔“
كيا انسان مدني الطبع ہے؟
يہ سوال بہت پرانا ہے كہ انسان كي اجتماعي زندگي كن عوامل كے زير اثر وجود ميں آئي ہے ۔ كيا انسان اجتماعي طبيعت ليكر وجود ميں آيا ہے يعني طبعاً اس كي تخليق ”كل“ كے ايك حصے كے طور پر كي گئي ہے اور اس كے وجود ميں اپنے ”كل“ سے وابستہ ہونے كا رجحان موجود ہے يا اس كي تخليق اجتماعي طبيعت پر نہيں ہوئى، بيروني جبر و اضطرار نے اسے اجتماعي زندگي بسر كرنے پر مجبور كر ديا ہے؟ يعني كيا انسان طبع اولي كے مطابق آزاد رہنا چاہتا ہے اور ان پاپنديوں كو قبول نہيں كرنا چاہتا جو اجتماعي زندگي كا لازمہ ہيں ليكن تجربے نے اسے بتا ديا ہے كہ وہ تنہا زندگي نہيں گذار سكتا لہٰذا بحالت مجبوري اس نے اجتماعي زندگي كي پاپنديوں كو گلے لگا ليا ہے؟ يا يہ كہ انسان اجتماعي ميلان لے كر پيدا نہيں ہوا، ليكن جو چيز اسے اجتماعي زندگي پر آمادہ كرتي ہے ۔ وہ اضطرار نہيں ہے يا كم از كم تنہا اضطرار نہيں ہے بلكہ انسان اپني فطري عقل كے فيصلے اور محاسبے كي طاقت سے اس نتيجے پر پہنچا ہے كہ وہ مشاركت، تعاون اور اجتماعي زندگي كے ذريعے ہي خلقت كے انعامات سے بہتر استفادہ كر سكتا ہے اور اسي لئے اس نے اس ”شركت“ كو ”انتخاب“ كيا ہے؟ پس مسئلے كي تين صورتيں ہيں:
۱۔ كيا انسان كي اجتماعي زندگي طبيعي ہے؟ يا
۲۔ اضطراري ہے؟ يا
۳۔ پھر انتخاب شدہ ہے ۔
#۔ پہلے نظريے كے مطابق نوع بشر كي اجتماعي زندگى، عورت اور مرد كي گھريلو زندگي كي طرح ہے كہ زوجين ميں سے ہر ايك آغاز خلقت سے”كل“ كا ايك حصہ بن كر آيا ہے اور دونوں كي سرنوشت ميں اپنے”كل“ سے ملحق ہونے كا رجحان موجود ہے۔
#۔ دوسرے نظريے كے مطابق اجتماعي زندگي كي مثال ايسے دو ملكوں كے تعاون اور باہمي سمجھوتے كي سي ہے جو وہ مشترك دشمن كے مقابلے ميں اپنے آپ كو ناتواں محسوس كرتے ہوئے اس راہ كو اختيار كر ليتے ہيں ۔
#۔ تيسرے نظريے كے مطابق اجتماعي زندگي ان دو سرمايہ داروں كي ايك كمپني كي طرح ہے جو زيادہ منافع كمانے كے لئے ايك تجارتى، زرعي يا صنعتي يونٹ قائم كرتے ہيں ۔
پہلے نظريے كے مطابق اصلي سبب انسان كي اندروني طبيعت ہے ۔ دوسرے نظريے كے مطابق انساني وجود سے باہر ايك بيروني عنصر اس ميں كارفرما ہے اور تيسرے نظريے كے مطابق اصلي سبب انسان كي عقلي قوت اور اس كي حساب كتاب كي صلاحيت ہے ۔
پہلے نظريے كي بنياد پرا جتماعي ہونا ايك كلي اور عمومي مقصد ہے اور انسان بالطبع اس كي سمت رواں ہے ۔ دوسرے نظريے كي بنياد پر ايك اتفاق اور حادثاتي امر ہے اور فلسفے كي اصطلاح ميں ”غايت اولي“ نہيں ”غايت ثانوي“ ہے اور تيسرے نظريے كے مطابق اس كي غايت فطري نہيں بلكہ فكري ہے ۔
قرآن كريم كي آيتوں سے يہ بات سامنے آتي ہے كہ انسان كے اجتماعي ہونے كو اس كي خلقت ميں ركھ ديا گيا ہے ۔ سورہ حجرات ميں ارشاد ہوتا ہے:
( يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثي و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقكم ) (حجرات ۔۱۳)
”اے انسانو! ہم نے تمہاري تخليق مرد اور عورت سے كي ہے اور تمہيں قوموں اور قبيلوں ميں بانٹ ديا تاكہ تمہارے درميان شناخت كي راہ نكل سكے (نہ يہ كہ اس كے ذريعے تم ايك دوسرے پر فخر و مباہات كرنے لگو) بے شك اللہ كے نزديك وہي زيادہ لائق تكريم ہے، جو تم ميں سے زيادہ پرہيز گار ہے ۔“
اس آيہ كريمہ ميں ايك اخلاقي حكم ديتے ہوئے انسان كي خاص خلقت كے اجتماعي فلسفے كي طرف بھي اشارہ كيا گيا ہے كہ انسان كو اس طرح سے پيدا كيا گيا ہے كہ وہ مختلف قوموں اور مختلف قبيلوں كي صورت اختيار كرے ۔ قوموں اور قبيلوں كے ساتھ منسوب ہونے كي وجہ سے ايك دوسرے كي شناخت ممكن ہو جاتي ہے، جو اجتماعي زندگي كا جزو لاينفك ہے يعني يہ نسبتيں جو ايك طرف سے وجہ اشتراك اور دوسري طرف سے اختراق بشر كا سبب ہيں، نہ ہوتيں تو ايك دوسرے كي شناخت ناممكن تھي اور اس صورت ميں ايك دوسرے كے ساتھ باہمي تعلقات پر مبني اجتماعي زندگي كا وجود غير ممكن تھا ۔ يہ اور ايسے ديگر امور مثلاً رنگ، شكل اور قد پر مبني اختلاف در اصل وہ پہچان ہے جو ہر شخص كو اس كي شناخت كي بنياد فراہم كرتي ہے ۔ بالفرض اگر ہر كوئي ايك ہي رنگ، ايك ہي شكل اور ايك ہي قالب ميں ڈھلا ہوتا اور اگر ان كے درميان كوئي باہم اور كوئي انتساب نہ ہوتا تو تمام افراد كسي كارخانے ميں ڈھلي ہوئي ايك شكل كي جنس كي طرح ہوتے اور ان كے درميان تميز مشكل ہوتي اور بالآخر يہي نتيجہ نكلتا كہ روابط، تبادلہ خيال، كام اور صنعتوں كے مبادلے كي بنياد پر قائم انسان كي اجتماعي زندگي ناممكن ہوجاتي ۔ پس قوموں اور قبيلوں كے ساتھ منسوب ہونے كي غايت اور حكمت طبيعي ہے اور وہ ہے لوگوں كا ايك دوسرے سے مختلف ہونا اور ان كے درميان شناخت كي صورت كا پيدا ہونا جو اجتماعي زندگي كا جزو لاينفك ہے نہ يہ ہے كہ اس بنياد پر ہم اپني بڑائى، برتري اور تفاخر كا اظہار كريں جب كہ شرف و كرامت كي بنياد تو تقويٰ ہے ۔
سورہ فرقان كي آيت(۵۴)ميں ارشاد ہوتا ہے:
( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا )
”تمہارا رب وہ ہے جس نے پاني سے بشر كي تخليق كي اور پھر اسے نسلي رشتے (نسبي رابطے) والا قرار ديا ۔“
اس آيہ كريمہ ميں بھي نسبي اور سببي روابط كو جو افراد كو ايك دوسرے سے ملانے اور ان ميں پہچان كي علامت بننے كا سبب ہيں، ايك ايسے عنوان سے پيش كيا گيا ہے كہ يہ اصل خلقت كي غايت كلي اور حكمت ہے ۔
سورہ مبارك زخرف كي آيت(۲۲)ميں ارشاد ہوتا ہے:
( لهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون )
”كيا يہ لوگ تيرے رب كي رحمت كو تقسيم كرتے ہيں؟ (كيا خلق سے متعلق امور انہيں سونپ ديئے گئے ہيں كہ جسے چاہيں ديں اور جسے چاہيں نہ ديں) ہم نے (استعداد پر مبني) وسائل اور ذرائع معاش كو دنياوي زندگي ميں ان كے درميان بانٹ ديا ہے اور بعض كو بعض پر صلاحيتوں اور وسائل كے اعتبار سے برتري دي ہے تاكہ اس ذريعے سے بعض، بعض كو مسخر كريں (اور اس طرح طبيعي طور پر ہر ايك سے دوسرے كي تسخير ہو) اور يقينا تيرے پروردگار كي رحمت (نعمت نبوت) اس چيز سے بہتر ہے جسے وہ جمع كر رہے ہيں ۔“
ہم نے ”الٰہي تصور كائنات“ ميں توحيد پر گفتگو كرتے ہوئے اس آيہ مباركہ كا مقصود واضح كيا تھا جسے يہاں ہم تكرار نہيں كريں گے ۔ تاہم بطور خلاصہ عرض كريں گے كہ اس آيت سے معلوم ہوتا ہے كہ انسان سب كے سب يكساں صلاحيت اور يكساں وسائل كے ساتھ خلق نہيں كئے گئے اور اگر ايسا ہوتا تو ہر كوئي وہي كچھ ركھتا جو دوسرے كے پاس ہے، ہر كوئي اسي چيز سے محروم ہوتا جس سے دوسرا محروم ہوتا ۔ اس كا لازمي نتيجہ يہي ہوتا كہ كوئي متوازي احتياج، كوئي باہمي تعلق يا متبادل خدمت كي راہ نہ نكلتي ۔ اللہ تعاليٰ نے نوع بشر كو صلاحيتوں، جسمانى، روحانى، عقلي اور جذباتي وسائل كے اعتبار سے مختلف خلق كيا ہے ۔ بعض كو بعض خوبيوں ميں دوسروں پر درجے كے اعتبار سے برتري دي ہے ۔ پھر ان دوسروں كو كسي اور خوبي ميں بعض پر سبقت بخشي ہے ۔ اس طرح سب كو بالطبع ايك دوسرے كا محتاج اور ايك دوسرے سے ربط باہم كا طلب گار بنا ديا ہے اور اس طرح ايك مربوط اجتماعي زندگي كي بنياد فراہم كي ہے ۔يہ آيہ كريمہ اس بات پر بھي دلالت كرتي ہے كہ انسان كي معاشرتي زندگي نري معاہداتي (انتخاب شدہ) يا اضطراري و مسلط كردہ ( Imposed ) نہيں بلكہ طبيعي ہے ۔
كيا معاشرے كا وجود اصيل اور عيني ہے؟
معاشرہ افراد كے مجموع سے مركب ہے ۔ افراد نہ ہوں تو معاشرہ بھي نہيں ہوتا ۔ اب ہم اس بات كا جائزہ ليں گے كہ معاشرے كي افراد كي تركيب كس طرح كي ہے؟ اس سلسلے ميں كئي نظريات قابل ذكر ہيں ۔ مثلاً:
الف) معاشرے ميں افراد كي تركيب اعتباري ہے، يعني حقيقت ميں كوئي تركيب عمل ميں نہيں آئى، حقيقي تركيب تو اس صورت ميں وقوع پذير ہوتي ہے جب كچھ امور ايك دوسرے پر اپنا رنگ جمائيں اور ايك دوسرے پر اثرات مرتب كريں ۔ اثر گذاري اور اثر پذيري كا عمل ہو، عمل اور رد عمل كے نتيجے ميں ايك نئي چيز اپني خاص خوبيوں كے ساتھ وجود ميں آئے، جيسے كيميائي تركيبيں ہوتيں ہيں، مثلاً آكسيجن اور ہائيڈروجن كے خاص انداز سے باہم ملنے سے پاني معرض وجود ميں آتا ہے ۔ پاني ايك بالكل نئي چيز ہوتي ہے جس كي ماہيت بھي نئي اور خواص و آثار بھي اپنے ہي ہوتے ہيں ۔ حقيقي تركيب كا لازمہ يہ ہے كہ اجزاء ايك دوسرے ميں مدغم ہوكر اپنے خواص و آثار كھو ديں اور ”مركب“ كے وجود ميں حل ہوجائيں ۔
انسان اپني اجتماعي زندگي ميں ہرگز يوں ايك دوسرے كے ساتھ مدغم نہيں ہوتا اور لوگ معاشرے ميں ”انسان الكل“ كي حيثيت سے حل نہيں ہوتے ۔ يہي وجہ ہے كہ معاشرہ كوئي اصيل، عيني اور حقيقي وجود نہيں ركھتا بلكہ اس كا وجود اعتباري اور انتزاعي ہوتا ہے ۔ اصيل عيني اور حقيقي وجود ركھنے والي چيز فرد ہے اور بس ۔ لہٰذا انساني زندگي اگرچہ معاشرے ميں ايك اجتماعي شكل اور اجتماعي ماہيت كي حامل ہے ليكن معاشرے كے افراد معاشرے كے عنوان سے ايك حقيقي مركب كي صورت اختيار نہيں كرتے ۔
ب) معاشرہ طبيعي مركبات كي طرح حقيقي مركب نہيں ہے ليكن صناعي مركب ضرور ہے ۔ صناعي مركب اگرچہ طبيعي نہيں ہے ليكن مركب حقيقي ہي كي ايك قسم ہے ۔ صناعي مركب كي مثال ايك مرتبط الاجزاء مشين كي سي ہے ۔ طبيعي مركب ميں اجزاء ايك تو اپني ہويت كھو كر كل ميں جذب ہوجاتے ہيں، دوسرے ان كا اپنا جداگانہ اثر بھي بالتبع اور بالجبر جاتا رہتا ہے، ليكن صناعي مركب ميں ان كي ہويت باقي رہتي ہے ليكن جداگانہ اثر باقي نہيں رہتا۔ اجزاء ايك خاص تركيب كے ساتھ ايك دوسرے سے مربوط ہوجاتے ہيں اور ان كے اثرات بھي آپس ميں پيوستگي اختيار كر ليتے ہيں ۔ اس كے نتيجے ميں ايسے اثرات مرتب ہوتے ہيں، جو عليحدہ حيثيت ميں اجزاء كے مجموعي آثار نہيں ہوتے ۔ مثلاً ايك گاڑي سامان يا افراد كو ايك معين رفتار سے ايك جگہ سے دوسري جگہ لے جاتي ہے حالانكہ يہ كام اس كا كوئي ايك جزو نہيں كر سكتا اور نہ اس كے اجزاء جب جدا جدا تھے تو مربوط ہونے سے پہلے مجموعي طور پر ايسا كر سكتے تھے ۔ موٹر گاڑي كي تركيب ميں اجزاء كے درميان جبري ارتباط اور جبري تعاون كار فرما ہے ليكن ہويت كل ميں ہويت اجزاء كے جذب كا يہ مقام نہيں بلكہ يہاں كل ، جزو سے ہٹ كر كوئي مقام نہيں ركھتا، كل اجزاء كے مجموعے اور ان كے درميان ايك خاص رابطے سے عبارت ہے ۔
معاشرہ بھي يوں ہي ہے ۔ معاشرہ بنيادي اور فرعي شعبوں اور پہلوؤں سے تشكيل پاتا ہے ۔ يہ شعبے اور وہ افراد جو ان شعبوں سے وابستہ ہيں سب ايك دوسرے سے وابستہ ہيں اور سب ايك دوسرے ميں پيوستہ ہيں ۔ ثقافتى، مذہبى، اقتصادى، سياسى، عدالتي يا تربيتي غرض جس شعبے ميں بھي كوئي تغير و تبديل ہو، اس كا اثر دوسرے شعبوں پر پڑتا ہے ۔ اجتماعي زندگي يوں معرض وجود ميں آتي ہے جيسے ايك پوري گاڑي ہوتي ہے بغير اس كے كہ معاشرے يا شعبوں كے افراد معاشرے كي اجتماعي شكل ميں اپني ہويت و حيثيت كھو ديں ۔
ج) معاشرہ طبيعي مركبات جيسا ہي ايك حقيقي مركب ہے، ليكن يہ قلبي تعلقات، افكار، عواطف ارادوں اور چاہتوں كي تركيب سے بنتا ہے يعني يہ تمدني تركيب ہے، جسموں اور بدنوں كي تركيب نہيں، جس طرح مادي عناصر ايك دوسرے پر اثرات قائم كر كے ايك نئي چيز ظہور ميں لانے كي بنياد فراہم كرتے ہيں اور يہ اصطلاح اہل فلسفہ مادہ كے اجزاء كا ايك دوسرے ميں اور ايك دوسرے پر تاثير و تاثر اور عمل اور رد عمل قائم كر كے ايك نئي شكل كي استعداد حاصل كرتے ہيں اور اس ترتيب سے ايك نيا مركب ظہور ميں آتا ہے اور اجزاء ايك نئي ہويت كے ساتھ اپني زندگي كو جاري ركھتے ہيں، اسي طرح انسان بھي فطري اور عالم طبيعت سے حاصل كي ہوئي دولت كے ساتھ معاشرتي زندگي ميں قدم ركھتا ہے اور روحانى طور پر ايك دوسرے ميں مدغم ہوجاتا ہے اور اس طرح وہ ايك جديد روحانى ہويت كے ساتھ گويا اجتماعي حيات كي صورت پاتا ہے اور يہ تركيب خود اپنے طور پر ايك طرح كي طبيعي تركيب ہے كہ جس كے لئے كوئي مثل و نظير ڈھونڈنا مشكل ہے ۔ يہ تركيب اس اعتبار سے كہ اجزاء ايك دوسرے پر عيني اثرات مرتب كرتے ہيں اور ايك دوسرے كے عيني تغير كا سبب بنتے ہيں اور ايك نئي ہويت اختيار كرتے ہيں ۔ ايك طبيعي اور عيني تركيب ہے، ليكن اس اعتبار سے كہ ”كل“ اور مركب ايك ”حقيقي اكائي“ كے عنوان سے وجود پذير نہيں، يہ ديگر طبيعي مركبات سے مختلف ہے يعني باقي تمام طبيعي مركبات ميں تركيب، تركيب حقيقي اس لئے ہے كہ ان ميں اجزاء ايك دوسرے پر حقيقي اثرات قائم كرتے ہيں اور افراد كي ہويت كچھ اورطرح كي ہويت ہوجاتي ہے نيز خود مركب ايك حقيقي ”اكائي“ ہوتا ہے يعني يہاں خالصتاً يگانہ ہويت موجود ہے اور كثرت اجزاء نے وحدت كل كي صورت اختيار كر لي ہے۔ جب كہ افراد اور معاشرے كي تركيب، حقيقي تركيب اس لئے ہے كہ يہ اثر اندازي اور اثر پذيري اور عمل و رد عمل واقعي طور پر رونما ہوتے ہيں اور اجزائے مركب يعني معاشرے كے افراد نئي صورت اور نئي ہويت سے ہمكنار ہوتے ہيں، ليكن كسي طرح بھي كثرت وحدت ميں نہيں بدلتي اور ايك حقيقي اكائي كے طور پر ”انسان الكل“ وجود ميں نہيں آتا كہ كثرتيں اس ميں حل ہوجائيں بلكہ ”انسان الكل“ افراد كا مجموعہ ہي ہوتا ہے جو اعتباري اور انتزاعي وجود ركھتا ہے ۔
د) معاشرہ، طبيعي مركبات سے بالاتر ايك حقيقي مركب ہے، طبيعي مركبات ميں اجزاء تركيب سے پہلے ازخود ہويت و آثار كے حامل ہوتے ہيں اور ايك دوسرے ميں اور ايك دوسرے پر تاثير و تاثر اور عمل اور رد عمل كے نتيجے ميں نئي چيز كے پيدا ہونے كي بنياد فراہم ہوتي ہے ليكن افراد اجتماعي وجود سے پہلے كے مرحلے ميں انساني ہويت كے حامل نہيں ہوتے، خالي برتن ہوتے ہيں كہ جن ميں اجتماعي روح كے حصول كي استعداد موجود ہوتي ہے، اجتماعي وجود سے قطع نظر انسان، حيوان محض ہے اور اس ميں صرف استعداد انسانيت موجود ہے ۔ انسان كي انسانيت يعني اس كي خودى، اس كا تفكر، اس كے عواطف واحسانات، اس كے ميلانات، اس كا فكري رجحان اور وہ چاہت جو انسانيت سے متعلق ہوتي ہے، اجتماعي روح كے پرتو ميں ابھرتي ہے ۔ يہ اجتماعي روح ہے جو اس خالي برتن كو پُر كرتي ہے اور كسي شخص كو شخصيت عطا كرتي ہے ۔ اجتماعي روح ہميشہ انسان كے ساتھ رہي ہے اور آئندہ بھي اخلاق، مذہب، سائنس، فلسفہ اور آرٹ سے متعلق تجليوں كے ساتھ اس كے آثار ہميشہ باقي رہيں گے ۔ افراد كا ايك دوسرے پر روحانى اور معنوي اثرات مرتب كرنا نيز ايك دوسرے پر ايسا ہي عمل و رد عمل قائم كرنا اجتماعي روح كے ذريعے اور اس كے پرتو ميں ہوتا ہے، نہ اس سے مقدم ہوتا ہے نہ اس سے پہلے والے مرحلے ميں، درحقيقت انسان كي عمر انيات اس كي نفسيات پر سبقت ركھتي ہے اور يہ پچھلے نظريئے كے برخلاف ہے كہ جو انسان كے لئے اجتماعي وجود سے پہلے اس كي نفسيات كے ہونے كا قائل ہے اور اس كي عمرانيات كو اس كي نفسيات كے بعد دوسرے مرحلے ميں لاتا ہے ۔
زير بحث نظريے كے مطابق اگر انسان اجتماعي وجود نہ ركھتا اور اگر اس كي عمرانيات نہ ہوتي تو وہ كوئي انفرادي انساني نفسيات بھي نہ ركھتا ۔ پہلا نظريہ خالص انفرادي اصليت كا نظريہ ہے، اس لئے كہ اس نظريہ كے مطابق معاشرہ نہ كسي حقيقي وجود كا حامل ہے اور نہ ہي اس كا كوئي قانون اور رسم و رواج ہے اور نہ ہي اس كي كوئي سرنوشت ہے اور نہ ہي كوئي شناخت ہے ۔ صرف افراد ميں جو وجود عيني ركھتے ہيں وہي موضوع شناخت بنتے ہيں ۔ ہر فرد كي تقدير دوسرے سے مختلف ہوتي ہے ۔
دوسرا نظريہ بھي انفرادي اصليت كا نظريہ ہے ۔ يہ نظريہ معاشرے كے لئے ايك كل اور تركيب افراد كے لئے ايك حقيقي تركيب كے عنوان سے اصليت اور غيبت كا قائل نہيں ليكن يہ افراد كے رابطہ كو ايك فزيكل رابطے كي مانند ايك طرح كا حقيقي اور عيني رابطہ بناتا ہے ۔ اس نظريے كے مطابق معاشرہ باوجود اس كے كہ افراد سے ہٹ كر كوئي جداگانہ وجود نہيں ركھتا اور صرف افراد ہي نہيں جو وجود عيني و حقيقي ركھتے ہيں ليكن اس اعتبار سے كہ افراد اور معاشرے كے اجزاء ايك كارخانے اور ايك مشينري كے اجزاء كي طرح ايك دوسرے كے ساتھ جڑے ہوئے ہيں ۔ افراد بھي ايك مشترك تقدير ركھتے ہيں اور معاشرہ يعني يہ مرتبط الاجزاء مجموعہ اسي علت و معلول كے خاص ميكانياتي نظام كے باعث جو اس كے اجزاء كے درميان موجود ہے، اپنے اجزاء كي شناخت سے ايك الگ شناخت ركھتا ہے ۔ ليكن تيسرا نظريہ فرد اور معاشرہ، دونوں كو اصالت ديتا ہے اس اعتبار سے كہ وہ معاشرے كے اجزاء كے وجود (يعني افراد) كو معاشرے ميں حل شدہ نہيں جانتا اور معاشرے كے لئے كيميائي مركبات كي طرح الگ سے كسي وجود كا قائل نہيں۔يہ انفرادي افراد كا نظريہ ہے ليكن اس اعتبار سے كہ يہاں اس نظريے كے مطابق تركيب افراد روحانى، فكري اور عاطفي مسائل كي رو سے كيميائي تركيب جيسي ہے كہ جہاں افراد معاشرے ميں ايك نئي ہويت اختيار كرتے ہيں اور وہي ہويت معاشرے كي بھي ہے، ہر چند كہ معاشرہ يگانہ ہويت كا حامل نہيں ۔ يہ نظريہ اجتماعي اصليت كا نظريہ ہے، اس نظريہ كي بناء پر اجزاء كے تاثير اور تاثير كے زير اثر ايك زندہ اور نئي حقيقت رونما ہوتي ہے اور نئي روح، نيا شعور، نيا ضمير، نيا ارادہ اور نئي چاہت ظہور ميں آگئي ہے ۔ يہ اس شعور، اس ارادے، اس ضمير اور اس فكر كے علاوہ جو افراد كو انفرادي طور پر حاصل ہے اور اسے افراد كے اس شعور اور وجدان پر غلبہ حاصل ہے ۔
اب رہا چوتھا نظريہ تو يہ خالص اجتماعي اصليت كا نظريہ ہے، اس نظريے كے مطابق جو كچھ بھي ہے، اجتماعي روح، اجتماعي ضمير، اجتماعي شعور، اجتماعي ارادہ، اجتماعي چاہت اور اجتماعي خودي ہي ہے ۔ انفرادي ضمير، اجتماعي شعور و ضمير كا ايك مظہر ہے اور بس ۔
قرآن مجيد كي آيتيں تيسرے نظريے كي تائيد كرتي ہيں ۔ جيسا كہ ہم پہلے عرض كر چكے ہيں قرآن سائنس يا فلسفے كي كتاب كي طرح مسائل كو پيش نہيں كرتا بلكہ اس كا انداز كچھ اور ہے ۔ وہ معاشرہ اور فرد سے متعلق مسائل كو اس طرح سامنے لاتا ہے كہ جس سے تيسرے نظريے كي تائيد ہوتي ہے ۔
قرآن تمام امتوں (تمام معاشروں) كے لئے مشترك سرنوشت، مشترك نامہ عمل، فہم و شعور، عمل اور اطاعت و عصيان كا قائل ہے ۔(۱)
ظاہر ہے اگر امت وجود عيني نہ ركھتي ہو تو سرنوشت، فہم و شعور اور اطاعت و عصيان كي گفتگو بے معني ہوجاتي ہے ۔ يہ دلالت كرتي ہے كہ قرآن ايك طرح كي حيات كا قائل ہے كہ جو اجتماعي حيات ہے ۔ اجتماعي حيات محض ايك تشبيہ و تمثيل نہيں بلكہ ايك حقيقت ہے، بالكل اسي طرح جس طرح اجتماعي موت ايك حقيقت ہے ۔
سورہ اعراف كي چونتيسويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:
( ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون )
”ہر امت (ہر معاشرہ) كي ايك مدت معياد ہے، اسے موت سے ہمكنار ہونا ہے پس جب ان كا آخري وقت آتا ہے تو اس ميں نہ ايك گھڑي آگے ہوتي ہے اور نہ ايك گھڑي پيچھے ۔“
اس آيت ميں ايك حيات اور ايك ايسي زندگي كي گفتگو ہے جس كا ايك آخري لمحہ ہے اور اس ميں كوئي تبديلي نہيں ہوتى، ايك گھڑي آگے نہ پيچھے، يہ حيات افراد سے نہيں امت سے متعلق ہے اور ظاہر ہے كہ افراد امت نہ ايك ساتھ اور نہ ہي ايك لمحے ميں مرتے ہيں بلكہ ان كي موت متفرق اور متفاوت ہوتي ہے ۔
سورہ مباركہ جاثيہ كي اٹھائيسويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:
( كل امة تدعي الي كتابها ) ”ہر امت اور ہر معاشرے كو اس كے اپنے ہاتھ سے لكھي جانے والي كتاب كي سمت پڑتال كے لئے بلايا جائے گا ۔“
پس معلوم ہوتا ہے كہ نہ صرف افراد كے اپنے مخصوص اعمال نامے اور كتابيں ہيں بلكہ معاشرے بھي اس اعتبار سے كہ زندہ، باشعور، مكلف اور قابل خطاب ہيں اور ارادہ و اختيار بھي ان كے پاس ہے ۔ نامہ عمل ركھتے ہيں اور انہيں بھي نامہ عمل كي طرف بلايا جائے گا ۔
سورہ انعام كي ايك سو آٹھويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:
( زينا لكل امة عملهم )
”ہم نے ہر امت كے عمل كو ان كے لئے زينت بنا ديا ہے ۔“
يہ آيت اس بات كو ثابت كرتي ہے كہ ايك امت اپنا ايك شعور، اپنا ايك معيار اور اپنا ايك طرز تفكر ركھتي ہے اور اس كا فہم و شعور و ادراك خصوصيت كے ساتھ اس سے وابستہ ہوتا ہے ۔ ہر امت (كم از كم عملي ادراكات سے متعلق مسائل ميں) اپنے مخصوص معيار كے مطابق فيصلہ كرتي ہے ۔ ہر امت كے ادراك كا ايك خاص ذوق اور سليقہ ہوتا ہے بہت سے ايسے امور ہيں جو ايك امت كي نگاہ ميں اچھے اور دوسري كي نگاہ ميں برے ہوتے ہيں ۔ يہ امت كا معاشرتي ماحول اور اس كي معاشرتي فضاء ہے جو افراد كے ادراك سے متعلق سليقے كو ايسا بناتي ہے ۔
سورہ مومن كي پانچويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:
( وهمت كل امة برسولهم لياخذ وه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب )
”اور ہر امت نے اپنے پيغمبر كو گرفتار كرنے كا عزم كيا اور ناحق خود اس سے جھگڑتے رہے تاكہ حق زائل ہو جائے اور جب انہوں نے ايسا كيا تو ميں نے انہيں اپني گرفت ميں لے ليا ۔ پس ميرا عذاب كيسا رہا؟ “
اس آيت ميں ايك ناشائستہ اجتماعي عزم و ارادہ كے بارے ميں گفتگو ہے ۔ يہاں بات حق سے بيكار جھگڑے كے لئے اجتماعي ارادہ سے متعلق كي گئي ہے ۔ گفتگو يہ ہے كہ اس نوعيت كے اجتماعي عزم و آہنگ كي سزا عمومي اور اجتماعي عذاب ہے ۔ قرآن كريم ميں بعض مقامات پر ديكھا گيا ہے كہ معاشرے كے كسي ايك فرد كے كسي كام كر پورے معاشرے كي طرف نسبت دي گئي ہے يا كسي نسل كے كسي عمل كو بعد كي نسلوں سے منسوب كيا گيا ہے ۔(۲)
اس وقت ہو سكتا ہے جب معاشرے كے افراد، اجتماعي سوچ اور اجتماعي ارادہ ركھتے ہوں ۔ اصطلاحاً كہہ سكتے ہيں كہ اجتماعي روح كے حامل ہوں ۔ مثلاً قوم ثمود كے واقعہ ميں حضرت صالح عليہ السلام كي اونٹني كو كاٹنے كے عمل كو پوري قوم سے نسبت دي گئي ہے جب كہ اسے كاٹنے والا ايك شخص تھا ۔ قرآن كے الفاظ ميں ”فعقروھا“ يعني پوري قوم نے اس اونٹني كو كاٹا ۔ قرآن اس جرم ميں پوري قوم كو ملوث جانتا ہے اور سب كو عذاب كا مستحق قرار ديتا ہے اور كہتا ہے:
( فدمدم عليهم ربهم )
نہج البلاغہ كے خطبوں ميں سے ايك خطبے ميں حضرت علي عليہ السلام اس مطلب كي وضاحت ميں ارشاد فرماتے ہيں:
ايها الناس انما يجمع الناس الرضا والسخط
”اے لوگو! بتحقيق وہ چيز جو سب كو اپنے گرد جمع كرتي ہے، انہيں رشتہ اتحاد ميں منسلك كرتي ہے اور انہيں ايك ہي سرنوشت عطا كرتي ہے، خوشنودي اور غضب ہے ۔“
جب كبھي لوگ اجتماعي صورت ميں كسي فعل پر خوشي يا ناخوشي كا اظہار كريں خواہ وہ فعل فرد واحد نے كيوں نہ انجام ديا ہو ۔ پوري قوم ايك ہي حكم اور ايك ہي انجام كي حامل ہو گي ۔
وانما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، فقال فعقروها فاصبحوا نادمين
”يعني خداوند عالم نے اپنے عذاب كو اجتماعي صورت ميں پوري قوم ثمود پر نازل كيا ۔ اس لئے ثمود كي پوري قوم اس ايك فرد كے فيصلے پر راضي تھي اور جب يہ فيصلہ مرحلہ عمل ميں آيا تو درحقيقت تمام لوگوں كا فيصلہ تھا ۔“
خداوند عالم نے اپنے كلام ميں اونٹني كو مارنے كے عمل كو باوجود اس كے ايك شخص كے ہاتھوں انجام پايا تھا، پوري قوم كي طرف نسبت دي اور كہا پوري قوم نے مار ڈالا ، يہ نہيں كہا كہ اس قوم كے ايك فرد نے يہ عمل انجام ديا ۔
يہاں ايك نكتے كا تذكرہ مناسب ہے اور وہ يہ كہ كسي گناہ پر اظہار رضامندي اگر صرف رضامندي كي حد تك رہے اور عملاً اس گناہ ميں شركت شمار نہ ہوتا ہو تو گناہ نہيں كہلاتا، مثلاً كوئي شخص عمل گناہ انجام دے اور دوسرے كو اس فعل كے بارے ميں فعل سے پہلے يا بعد ميں آگاہي ہو جائے اور وہ اس سے خوش ہو يہاں تك كہ اگر خوشنودي عزم و ارادہ كے مرحلے ميں بھي داخل ہو جائے اور اس پر عمل نہ ہو، تب بھي گناہ نہيں ہے ۔
خوشنودي كو اس وقت گناہ كہا جائے گا جب يہ ايك فرد كے گناہ كرنے كے ارادے اور عمل ميں ايك طرح كي شركت شمار كي جائے اور ايك طرح سے اس كے ارادے اور عمل ميں موثر سمجھي جائے ۔ اجتماعي گناہوں كي يہي صورت ہے ۔
معاشرتي ماحول اور اجتماعي روح كسي گناہ كے واقع ہونے پر راضي ہو كر اس گناہ كے ارتكاب كا ارادہ كرتي ہے ۔ معاشرے ميں سے ايك فرد كي جس كي رضايت سب كي رضايت كا ايك حصہ ہوتي ہے اور جس كا ارادہ سب كے ارادے كا ايك جزو ہوتا ہے، اس گناہ كا مرتكب ہوتا ہے ۔ يہ وہ موقع ہوتا ہے جب ايك فرد كا گناہ پورے معاشرے كا گناہ كہلاتا ہے ۔ نہج البلاغہ كے خطبے ميں حضرت علي عليہ السلام نے آيت قرآن كے مقصود كي طرف اشارہ كرتے ہوئے اسي حقيقت كو اجاگر كيا ہے وگرنہ محض ايك شخص كي اپني حد تك خوشنودي يا محض اپني حد تك ناراضگي سي طرح بھي گناہگار كے عمل اور ارادے ميں شركت نہيں كہلا سكتي ۔
قرآن كہيں كہيں كسي نسل كے كام كو بعد كي نسلوں سے نسبت ديتا ہے، جيسے قوم اسرائيل كے گذشتہ كاموں كو جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كے زمانے كے لوگوں سے نسبت دي اور كہا ہے كہ يہ لوگ اس لئے ذلت و مسكنت كا استحقاق ركھتے ہيں كہ انہوں نے ناحق پيغمبروں كو قتل كيا ۔ يہ بات اس لئے ہے كہ پيغمبر اسلام صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كے زمانے كے لوگ قرآن كي نظر ميں گذشتہ لوگوں كا ہي تسلسل ہيں بلكہ اجتماعي روح كے اعتبار سے عين وہي لوگ ہيں جن كا سلسلہ اب بھي باقي ہے ۔ يہ بات جو كہي جاتي ہے كہ ”انسانيت زندوں سے زيادہ مردوں سے بني ہے“ اس كا مفہوم يہ ہے كہ بشريت كے عناصر كي تشكيل ميں ہميشہ زندوں سے زيادہ مردوں كا عمل دخل رہ ہے اور يہ گفتگو بھي كہ ”زندہ پر مردوں كي پہلے سے كہيں زيادہ حكمراني ہے“ اسي مذكورہ مفہوم كي حامل ہے ۔
تفسير الميزان ميں اس بحث كے بعد كہ جب كوئي معاشرہ ايك واحد سوچ اورايك واحد روح كا حامل ہوتا ہے تو ايك فرد جيسا ہوجاتا ہے اس كے افراد انساني اعضائے وجود بن جاتے ہيں جو ذات اور عمل كے اعتبار سے انسان كي حيثيت ميں گم ہو جاتے ہيں ۔ ان كي راحت اور تكليف عيناً انسان كي راحت اور تكليف بن جاتي ہے اور ان كي سعادت و شقاوت بھي عيناً انسان كي سعادت و شقاوت قرار پاتي ہے ۔ اس كے بعد مرقوم ہے:
”قرآن نے ان قوموں اور ان معاشروں كے بارے ميں جو مذہبى يا قومي تعصبات كي بنياد پر ايك واحد اجتماعي سوچ كے حامل تھے اس طرح فيصلہ كيا ہے كہ بعد ميں آنے والے طبقات اور نسلوں كو پہلے آنے والي نسلوں كے اعمال كي وجہ سے قابل مواخذہ قرار ديا ہے اور حاضرين كو غائبين كے اعمال كي بنياد پر مورد عتاب و ملامت قرار ديا ہے، ايسے موقع پر جب لوگ اجتماع فكر اور اجتماعي جذبات كے حامل ہوں تو صحيح فيصلہ اس كے علاوہ كچھ اور نہيں ہو سكتا ۔(۳)
معاشرہ اور اس كے قوانين و سنن
معاشرہ اگرحقيقي وجود كا حامل ہو تو لازمي طور پر اپنے سے متعلق خاص قوانين و سنن كا حامل ہوگا، اگر ہم معاشرے كي ماہيت كے بارے ميں جس پر ہم ابھي بحث كر چكے ہيں، پہلے نظريے سے متفق ہوں اور معاشرے كے عيني وجود كو تسليم نہ كريں تو ہم نے لازمي طور پر معاشرے كو قانون اور سنن سے عاري جانا ہے اور اگر دوسرے نظريے كو مانتے ہيں اور معاشرے كو صنعتي اور مشيني تركيب جيسا تسليم كرتے ہيں تو اس ميں معاشرہ قانون اور سنن كا حامل ہے، ليكن يہ قانون اور سنن صرف معاشرے كے اجزاء كے درميان ميكانياتي اثرات ہي كي حد تك رہے گے اور ايسے معاشرے ميں كسي قسم كي زندگي يا اس كے مخصوص اثرات مشاہدہ نہيں كئے جا سكيں گے، اگر ہم تيسرے نظريے كو مانتے ہيں تو سب سے پہلے معاشرہ اس اعتبار سے كہ وہ انفرادي حيات سے الگ ايك خاص طرح كي حيات كا حامل ہے، ہرچند كہ اس اجتماعي حيات كا اپنا الگ كوئي وجود نہيں بلكہ افراد نے بكھر كر انہيں ميں حلول كر گيا ہے، اپنے افراد اجزاء سے الگ قوانين و آداب كا حامل ہے اور اس كي شناخت ضروري ہے، پھر يہ كہ معاشرے كے اجزاء جو افراد سے عبارت ہيں ، مشيني نظريے كے برخلاف اپني ہويت كے استقلال كو اگرچہ نسبي طور پر كيوں نہ ہو كھر كر اعضاء كي صورت اختيار كر ليتے ہيں ۔ ليكن اس كے ساتھ ساتھ افراد كا نسبي استقلال محفوظ رہتا ہے كيونكہ انفرادي حيات، انفرادي فطرت اور طبيعت سے فرد كا اكتساب، اجتماعي حيات ميں حل نہيں ہوتا اور حقيقتاً اس نظريے كے مطابق انسان دو حيات دو روح اور دو ”ميں“ كے ساتھ زندگي بسر كرتا ہے، ايك اس كي فطري ”ميں“ روح اور حيات ہے جو طبيعت كے جوہري حركات سے وجود ميں آتي ہے اور دوسرے وہ اجتماعي ”ميں“ روح اور حيات ہے جو اجتماعي زندگي سے وجود پذير ہو كر انفرادي ”ميں“ حلول كرتي ہے ۔ پس اس اعتبار سے انسان پر نفسيات كے قوانين كے ساتھ عمراني سنن بھي حكم فرما ہيں ۔ چوتھے نظريے كے مطابق صرف ايك نوعيت كا قانون اور ايك نوعيت كي سنن انسان پر حاكم ہيں اور وہ اجتماعي سنن ہيں اور بس ۔
علمائے اسلام ميں غالباً عبد الرحمن ابن خلدون وہ پہلا شخص ہے جس نے تاريخ پر اپنے مشہور و معروف مقدمے ميں صراحت كے ساتھ معاشرے پر حاكم قوانين و آداب كو انفرادي قوانين و آداب سے الگ پيش كيا ہے اور معاشرے كے لئے ”حيثيت“، ”طبيعت“ اور واقعيت كا قائل ہوا ہے، جديد علماء و حكماء ميں اٹھارويں صدي كا فرانسيسي دانشور ”مونٹيسكيو“ وہ پہلا شخص ہے جس نے معاشروں پر حاكم سنن كو دريافت كرنے كي كوشش كي ہے ۔ ريمون آرون، ”مونٹيسكيو“ كے بارے ميں لكھتا ہے:
”اس كا مقصد تاريخ كو معقول صورت دينا ہے ۔ وہ چاہتا ہے تاريخ كے پيش كردہ واقعات كو رد كرے ۔ ہاں! تاريخ كے پيش كردہ واقعات تقريباً لامحدود تقديسي عادات، افكار، قوانين، آداب و رسوم اور معاشرتي شعبوں كي شكل ميں اس كے سامنے آتے ہيں اور يہي مختلف واقعات جو ظاہراً ہم آہنگ ہوتے ہيں اس كي تحقيق كا نقطہ آغاز بنتے ہيں۔ تحقيق كے آخر ميں كسي شعور نظم كو واقعات كے ان نامربوط سلسلوں كا جاگزيں ہونا چاہيے ۔ مونٹيسكيو ”ميكس ويبر“ كي طرح نامربوط واقعات سے گذرنا چاہتا ہے تاكہ كسي شعوري نظم كو حاصل كر سكے، ہاں يہي طريقہ عالم عمرانيات كا طريقہ ہے ۔“
اس بيان كا خلاصہ يہ ہے كہ اجتماعي واقعات كي ان ناہم آہنگيوں كے درپردہ جو انہيں ايك دوسرے سے اجنبي بنا ديتي ہيں ۔ عمرانيات كا ماہر ايك ايسي وحدت ڈھونڈ نكالتا ہے كہ يہ تمام ناہم آہنگياں اس وحدت كا مظہر بن جاتي ہيں ۔ اسي طرح اس بارے ميں كہ مشابہ اسباب كے عمل دخل سے مشابہ اجتماعي واقعات رونما ہوئے ہيں ۔ ”روميوں كے عروج و زوال كے اسباب سے متعلق ملاحظات“ نامي كتاب كا يہ اقتباس پيش كيا جاتا ہے:
”دنيا ميں اتفاق يا حادثہ حكم نہيں ہے ۔ اس نكتے كو روميوں سے پوچھا جا سكتا ہے كيونكہ جب تك فرماں روائي ميں ان كا پروگرام منظم رہا، فتح و نصرت انہيں نصيب ہوتي رہى، ليكن جب انہوں نے اپنے پروگرام ميں تبديلي پيدا كي تو مسلسل پستيوں كي طرف گئے ۔ ہر سركاري نظام ميں چكھ علل و اسباب خواہ اخلاقي ہوں يا جسمانى كا عمل دخل ہوتا ہے، جو اس نظام كو سربلندي عطا كرتے ہيں يا پھر تباہي و بربادي كي دلدل ميں دھكيل ديتے ہيں۔ واقعات انہيں اسباب كے زير اثر ہوتے ہيں۔ اگر كوئي معركہ يعني خاص ملت كسي حكومت كي بساط الٹ دے تو يقينا اس ميں ايسے كلي اسباب كار فرما ہيں، جو وجہ معركہ بن كر اس حكومت كا تختہ الٹ ديتے ہيں۔ مختصر يہ كہ كوئي حقيقي بنياد ہے جو تمام جزوي اتفاقات كا سبب بنتي ہے ۔“
قرآن كريم اس بات كي تصريح كرتا ہے كہ قوميں اور معاشرے اس اعتبار سے كہ قوم اور معاشرہ ہيں (صرف معاشرے كے افراد نہيں) قوانين و سنن اور ان قوانين و سنن كي بنياد پر عروج و زوال ركھتے ہيں ۔ معاشرے كے مشترك انجام ركھنے سے مراد يہ ہے كہ وہ قوانين و سنن كا حامل ہے ۔
قرآن حكيم ميں بني اسرائيل كے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے:
( وقضينا الي بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار و كان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال و بنين و جعلناكم اكثر نفيراً إن احسنتم أحسنتم لأنفسكم وان اساتم فلها، فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسي ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) (سورہ بني اسرائيل، آيت۴ تا۸)
”اور ہم نے (آسماني كتابوں ميں سے) ايك كتاب ميں بني اسرائيل كو يہ حكم ديا كہ تم ضرور بالضرور زمين ميں دو مرتبہ فساد اور بڑي سركشي كرو گے، پھر جب پہلي سركشي سے متعلق وقت انتقام آئے گا، تو ہم بڑے جنگ آور اور زور آزما لوگوں كو تمہارے خلاف اٹھائيں گے جو تمہارے گھروں ميں گھس آئيں گے اور يہ وعدہ پورا ہو كر رہے گا ۔ پھر ہم تمہيں (تمہاري برائيوں سے پشيماني اور صحيح راستے كي طرف لوٹ آنے كے باعث) ان پر دوبارہ غلبہ ديں گے اور مال اور افراد سے تمہاري مدد كريں گے اور تعداد ميں تمہيں ان سے بڑھا ديں گے پس كلي طور پر اگر تم نيكي كرو گے تو وہ تمہاري اپني ذات كے لئے ہوگا اور اگر بدي سے ہمكنار ہو گے تو اس ميں بھي تمہاري اپني ذات متاثر ہوگي (يعني ہمارا طريقہ اور ہمارا قانون اپني جگہ مستحكم اور اٹل ہے كہ كچھ شرائط ہيں جن ميں ہم لوگوں كو قوت و قدر و عزت و استقلال عطا كرتے ہيں اور كچھ شرائط ايسي ہيں جن ميں دوسروں كے ہاتھوں انہيں ذليل و خوار ہونا پڑتا ہے) پھر جب (برائي اور تباہي كي طرف بازگشت كے نتيجے) تم سے تمہارے دوسرے انتقام كي باري آئے گي تو (ہم دوسرے صاحبان قوت و طاقت كو تم پر مسلط كر ديں گے) تاكہ وہ تمہارا چہرہ بگاڑ ديں اور اسي طرح مسجد ميں گھس آئيں جس طرح پہلے گھس آئے تھے اور جس چيز پر غلبہ حاصل كريں اسے سختي سے مٹا ديں۔ (اگر تم راہ راست كي طرف لوٹ آئے تو) اميد ہے كہ خدا پھر اپني رحمت كو تمہارے شامل حال كر دے اور اگر تم نے پھر وہي كيا اور برائي كي طرف لوٹ آئے تو ہم بھي وہي كريں گے اور پھر سے دشمن اور عذاب معين كرديں گے ۔“
يہ آخري جملہ
( وان عدتم عدنا )
”تم جس قدر تباہي كي طرف لوٹو گے ہم اسي قدر دشمن كے ہاتھوں تمہيں ذليل كريں گے ۔“
اس توجہ كے ساتھ كہ مخاطب فرد نہيں قوم و ملت ہے، يہ معاشروں پر محيط قوانين كي كليت اور ان كے اٹل ہونے كو ظاہر كرتا ہے ۔
جبر يا اختيار؟
جو بنيادي مسائل اہل دانش كے درميان خاص طور پر موجودہ صدي ميں زير غور ہيں، ان ميں ايك مسئلہ معاشرے كے مقابل فرد كے جبر يا اختيار كا ہے، بعبارت ديگر يہاں اجتماعي روح كے مقابل انفرادي روح كے جبر و اختيار كي گفتگو ہے، اگر ہم معاشرے كي تركيب كے مسئلے ميں پہلے نظريہ كو مانتے ہيں اور معاشرے كي تركيب كو خالص اعتباري جانتے ہيں اور مكمل انفرادي اصليت پر ہمارا عقيدہ ہے تو ا س ميں اجتماعي جبر كي گنجائش نہيں كيوں كہ يہاں سوائے فرد و طاقت اور انفرادي طاقت كے علاوہ اجتماعي قوت نامي كوئي شے موجود نہيں جو فرد كو اپنے احكامات كے زير اثر لائے اور جس سے معاشرتي جبر كا خيال پيدا ہو، اب اگر كوئي جب رونما ہوتا ہے تو اس كا تعلق اجتماعي جبر كے حاميوں كي رائے كے برخلاف معاشرے سے نہيں فرد يا افراد سے ہے ۔ ليكن اگر ہم چوتھے نظريہ كو مانتے ہيں اور فرد كو انساني حيثيت كے اعتبار سے ايك خام مادہ اور ايك خالي برتن كي طرح تصور كرتے ہيں اور فرد كي تمام انساني حيثيت اس كي عقل اور اس كے ارادے كو كہ جو اس كے اپنے اختيار ميں ہے، اجتماعي عقل اور اجتماعي ارادے كا پرتو جانتے ہيں اور يہ عقيدہ ركھتے ہيں كہ اجتماعي روح جو اپنے اجتماعي مقاصد كے حصول كے لئے اپني اكائي ميں ايك انفرادي فريب بن كر ظاہر ہوتي ہے، خلاصہ يہ كہ اگر ہم صرف اور صرف اجتماعي اصليت كے قائل بن كر سوچيں تو پھر اجتماعي امور ميں فرد كي آزادي اور اس كے اختيار كا تصور باقي نہيں رہتا ۔
فرانس كا مشہور عمراني ماہر ”ايمل ڈوركم“ اس حد تك اجتماعي اصليت كا قائل ہے كہ كہتا ہے:
”معاشرتي امور در حقيقت ان امور كے برخلاف جن كا تعلق كھانے پينے اور سونے جيسے امور سے ہے، جو انسان كے حيواني اور حياتياتي (بائيولوجيكل) پہلو سے ہيں، كسي فرد كے فكر و ارادے سے حاصل نہيں ہوتے بلكہ معاشرہ انہيں وجود ميں لاتا ہے اور اس كي تين خصلتيں ہيں:بيروني ہونا، جبري ہونا اور عمومي ہونا ۔ بيروني اس اعتبار سے ہيں كہ فرد كے وجود سے باہر يعني معاشرے سے فرد پر لاگو ہوتے ہيں اور اس سے پہلے كہ فرد وجود ميں آئے، يہ معاشرے ميں موجود ہوتے ہيں اور وہ انہيں معاشرے كے زير اثر قبول كرتا ہے ۔ آداب، اخلاق اور معاشرتي رسميں، مذہب اور ان جيسي چيزيں معاشرے سے اسے ملتي ہيں اور اس اعتبار سے جبري ہيں كہ وہ خود كو فرد پر ٹھونستي ہيں اور فرد كے ضمير، اس كے احساسات اس كے فيصلوں اور اس كے افكار و عواطف كو اپني شكل اور اپنے رنگ ميں ڈھال ليتي ہيں اور جبري ہونا عموميت كي دليل ہے۔“
ليكن اگر ہم تيسرے نظريے كو اپناتے ہيں يعني فرد كو بھي اصليت ديتے ہيں اور معاشرے كو بھي اگرچہ معاشرے كي طاقت افراد كي طاقت پر غلبہ ركھتي ہے تو اس صورت ميں ضروري نہيں ہے كہ افراد انساني مسائل اور سماجي امور ميں مجبور قرار پائيں ۔
”ڈوركم“ كا نظريہ جبر اس بات سے وجود ميں آيا ہے كہ طبيعت كے صفحے پر جوہري تكامل سے وجود ميں آنے والي انساني فطرت كي اصالت سے غفلت برتي گئي ہے، يہ فطرت انسان كو ايك خاص طرح كي حريت، امكان اور آزادي عطا كرتي ہے جس كے باعث وہ معاشرے كي طرف سے ڈھونسي جانے والي پاپنديوں كي مخالفت كے قابل ہوجاتا ہے ۔ يہي وجہ ہے كہ فرد اور معاشرے كے درميان ايك طرح كا ”امر بين الامرين“ حكم فرما ہے ۔
قرآن كريم جہاں معاشرے كے لئے طبيعت، حيثيت، عينيت، توانائى، حيات، موت، اجل، ضمير اور اطاعت و عصيان كا قائل ہے، وہاں صريحاً فرد كو امكاني طور پر معاشرے كے احكام سے حكم عدولي كرنے ميں آزاد اور توانا جانتا ہے ۔ قرآن نے اس مسئلے ميں جس چيز كو بنياد بناتا ہے اس كا نام ”فطرة اللہ“ ركھا ہے ۔ سورہ نساء كي آيت۹۷ ميں اس گروہ كي نسبت جو مكہ كے معاشرے ميں اپنے آپ كو ”مستضعف“ و ناتواں جانتا تھا اور فطري ذمہ داري سے دستبرداري كے لئے اسي ناتواني كو عذر بناتا تھا اور درحقيقت خود كو معاشرے كے مقابل مجبور پيش كرتا تھا:
”ان كا عذر كسي طرح بھي قابل قبول نہيں اس لئے كہ كم از كم وہ يہ تو كر سكتے تھے كہ اپنے آپ كو اس معاشرتي ماحول سے نكال كر دوسرے معاشرتي ماحول ميں منقل كر ديتے ۔“
پھر دوسري جگہ ارشاد ہوتا ہے:
( يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ) (سورہ مائدہ، آيت ۔۱۰۵)
”اے صاحبان ايمان! تم خود اپنے نفوس كي حفاظت كے ذمہ دار ہو، ہرگز دوسروں كي گمراہي (لازمي طور پر) تمہاري گمراہي كا سبب نہ بنے ۔“
”ذر“ سے متعلق مشہور آيت جس كا اشارہ انساني فطرت كي طرف ہے ۔ اس گفتگو كے بعد كہ خداوند عالم نے توحيد كے عہد كو انسان كے وجود اور اس كي ذات ميں سمو ديا ہے، گوش گذار كيا گيا ہے اور يہ اس لئے ہے تاكہ تم بعد ميں يہ نہ كہہ سكو كہ ہمارے باپ دادا مشرك تھے اور ہمارے پاس كوئي چارہ كار نہيں تھا، ہم مجبور تھے كہ اپنے باپ دادا كي سنت پر باقي رہيں، اس الٰہي فطرت كے بعد اب كسي جبر يا مجبوري كي گنجائش باقي نہيں رہتي ۔
قرآني تعليمات سراسر مسئوليت اور ذمہ داري كي اساس پر قائم ہيں ۔ اپني اور معاشرے كي ذمہ دارى، امر بالمعروف اور نہي عن المنكر معاشرے كي برائيوں اور بدعنوانيوں كے خلاف فرد كے قيام كا حكم نامہ ہے ۔ قرآن مجيد كے بيشتر قصص و حكايات برائي كے اجتماعي ماحول كے مقابل فرد كے سينہ سپر ہونے سے عبارت ہيں، جناب نوح عليہ السلام، جناب ابراہيم عليہ السلام، جناب موسيٰ عليہ السلام ، جناب عيسيٰ عليہ السلام، رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم، اصحاب كہف اور مومن آل فرعون وغيرہ سب كے سب اسي حيثيت كے حامي ہيں ۔
معاشرے اور معاشرتي ماحول ميں افراد پر جبر كے واہمہ كي بنياد اس تصور پر ہے، حقيقي تركيب كے لئے لازمي ہے كہ اجزاء ايك دوسرے ميں مدغم ہوجائيں اور كثرت ”كل“ كي اكائي ميں جذب ہو جائے اور ايك نئي حقيقت سامنے آئے (اور اس واہم كي بنياد يہ تصور بھي ہے كہ) ياتو فرد كي حيثيت اس كي آزادي اور استقلال كو مانا جائے اور تركيب كے حقيقي اور عيني ہونے كو رد كيا جائے جيسا كہ پہلے اور دوسرے نظريے ميں معاشرے يا فرد كي اصالت كا ذكر آيا ہے، يا پھر ”ڈوركم“ كي طرح تركيب كي اصالت اور معاشرے كي عينيت كو تسليم كيا جائے اور فرد كي حيثيت، استقلال اور آزادي كو ٹھكرا ديا جائے كيوں كہ ان دونوں كي يكجائي ناممكن ہے اور چونكہ عمرانيات اپنے تمام دلائل كي رو سے معاشرے كي عينيت كو تسليم كرتي ہے، لہٰذا فرد سے متعلق گفتگو كو مسترد سمجھا جائے ۔
سچ تو يہ ہے كہ فلسفي نقطہ نظر سے تمام حقيقي تركيبوں كو يكساں نوعيت كي نہيں سمجھنا چاہيے، عالم طبيعت كے نچلے درجات يعني جمادات اور حيات سے عاري موجودات ميں كہ جن ميں بااصطلاح اہل فلسفہ صرف ايك بسيط قوت كار فرما ہے اور جو بہ تعبير فلاسفہ ”عليٰ وتيرہ واحدہ“ پر قائم ہيں، اجزاء اور قوي ايك دوسرے ميں مكمل طور پر مدغم ہوجاتے ہيں اور ان كا وجود ”وجود كل“ ميں مكمل طور پر حل ہوجاتا ہے، جيسے پاني كي تركيب ميں آكسيجن اور ہائيڈروجن ليكن تركيب درجات ميں جس قدر بلند ہوگى، اجزاء كل كي نسبت اتنے ہي زيادہ نسبي استقلال كے حامل ہوں گے اور عين وحدت كے ساتھ ايك طرح كي كثرت اور عين كثرت كے ساتھ وحدت كا ظہور ہوگا اور يہي كچھ انسان ميں ہم ديكھتے ہيں كہ وہ عين وحدت كے ساتھ ايك عجيب كثرت كا حامل ہے كہ جہاں صرف يہي نہيں كہ اس كے اندر كي طاقتيں اپني كثرت كو ايك حد تك محفوظ ركھتي ہيں بلكہ ان ميں ايك طرح كا تضاد اور دائمي كشمكش برقرار رہتي ہے ۔ معاشرہ عالم طبيعت كے بلند ترين موجودات ميں سے ہے اور اس كو تركيب ميں لانے والے اجزاء كا نسبي استقلال اس سے كہيں بلند تر ہے۔
پس اس اعتبار سے كہ افراد بشر ايك معاشرے كے اجزاء ہيں، اپنے طبيعي اور انفرادي وجود ميں معاشرے سے زيادہ فطري عقل اور ارادے كے مالك ہيں نيز يہ كہ چونكہ عالم طبيعت كے اعليٰ مراتب كي ترتيب ميں اجزاء كا نسبي استقلال محفوظ رہتا ہے اس لئے انساني افراد يعني انفرادي روح معاشرے يعني اجتماعي روح كے مقابلے ميں مجبور اور مسلوب الاختيار نہيں ہوتي ۔
____________________
۱. ملاحظہ ہو تفسير الميزان، جلد ۴۔ ص۔۱۰۲.
۲. جيسے سورہ بقرہ كي آيت: ۷۹،فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل مما يكسبون ، اسي طرح آل عمران كي ۱۱۲، آيت:ضرب عليهم الذلة اينما ثقفوا الابحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بعض من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبيا بغير حق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون
۳.تفسير الميزان، جلد۴، ص۱۱۲.
معاشرتي تقسيم اور طبقہ بندى
معاشرہ باوجود وحدت كے اپنے اندر گروہوں، طبقوں اور مختلف اصناف ميں كہ جہاں متضاد صورتيں بھي نكل آتي ہيں، بٹا ہوا ہے ۔ يہ صورت حال اگر كلي نہيں تو كم از كم بعض معاشروں كا يہي حال ہے لہٰذا مكان ہے كہ معاشرہ اپني عين وحدت ميں اندروني طور پر مخالف اور كبھي متضاد طبقوں ميں منقسم ہو، پس معاشرہ وحدت كے ساتھ كثرت اور كثرت كے ساتھ عين وحدت كا حامل ہے اور حكمائے اسلام كي اصطلاح ميں معاشرے پر كثرت ميں ايك طرح كي وحدت اور وحدت ميں ايك طرح كي كثرت كار فرما ہے ۔ پچھلے ابواب ميں معاشرے كي وحدت پر گفتگو تھي كہ وہ وحدت كس نوعيت كي ہے ۔ اب گفتگو معاشرے كي كثرت سے متعلق ہے كہ اس كي نوعيت كيا ہے؟
اس سلسلے ميں دو نظريے مشہور ہيں، ايك نظريے كي بنياد تاريخي ماديت اور جدلياتي تضاد پر ہے، اس نظريے كے مطابق، جس كے بارے ميں آگے چل كر گفتگو ہوگى، ہمارا موضوع بحث مالكيت كے قانون كے تابع ہے، يعني وہ معاشرے جن ميں ذاتي مالكيت كا كوئي وجود نہيں مثلاً اوائل تاريخ كا سوشلسٹ معاشرہ يا آئندہ رونما ہونے والا سوشلسٹ معاشرہ بنيادي طور پر ايك طبقے كے حامل ہيں اور وہ معاشرے جن ميں ذاتي مالكيت كي بالادستي ہے حتمي طور پر دو طبقوں كے حامل ہيں پس اس صورت ميں معاشرہ يا تو ايك طبقے كا حامل ہے يا دو كا، اور اس كي كوئي تيسري صورت نہيں ہے ۔ دو طبقے ركھنے والے معاشروں ميں انسان دو گروہوں ميں بٹ جاتا ہے، ايك استحصال كرنے والا اور دوسرا استحصال ہونے والا اور سوائے ان دو حاكم و محكوم گروہوں يا لشكروں كے تيسرا كوئي گروہ موجود نہيں ۔ آرٹ، فلسفے، اخلاق، مذہب جيسے ديگر معاشرتي امور ميں بھي اسي طبقاتي نظام كا رنگ نظر آنے لگتا ہے، مثلاً دو طرح كا فلسفہ، دو طرح كا اخلاقى نظام اور دو طرح كے مذہب وغيرہ معاشرے پر حاكم ہوجاتے ہيں اور ہر ايك كسي مخصوص اقتصادي طبقے كا رنگ اپنے اوپر چڑھا ليتا ہے، اگر بالفرض ايك فلسفہ ايك مذہب يا ايك اخلاق معاشرے پر حاكم ہوتو بھي يہ انہي دو طبقات كے رنگوں ميں كسي ايك كا رنگ ہوگا جسے دوسرے طبقے پر ٹھونسا گيا ہوگا ۔
دوسرا نظريہ يہ ہے كہ كسي معاشرے كي ايك طبقے يا كئي طبقوں سے وابستگي كا انحصار مالكيت كے قانوني اصول پر نہيں ہے، بلكہ ثقافتى، اجتماعى، نسلي اور نظرياتي علل و اسباب بھي كسي معاشرے كو كئي طبقوں ميں بانٹ سكتے ہيں ۔ نخاص طور پر ثقافتي اور نظرياتي اسباب اس ميں بنيادي كردار ادا كر سكتے ہيں اور معاشرے كو صرف دو نہيں بلكہ كئي متضاد طبقوں ميں تقسيم كر سكتے ہيں، اسي طرح معاشرے كو اصل مالكيت كے لازماً رد كئے بغير ايك طبقاتي معاشرے ميں تبديل كيا جا سكتا ہے ۔
اب ہم ديكھتے ہيں كہ قرآن معاشرے كي كثرت كے بارے ميں كس نقطہ نظر كا حامل ہے ۔ كيا وہ كثرت و اختلاف كو تسليم كرتا ہے يا نہيں؟ اور اگر تسليم كرتا ہے تو كيا اس كے نزديك معاشرہ دو طبقوں كا حامل ہے اور وہ بھي مالكيت اور استحصال كي بنياد پر كوئي اور صورت اس كے پىش نظر ہے؟ ميرے خيال ميں معاشرے اور اجتماع سے متعلق قرآني الفاظ كا استخراج اور ان كے مفاہيم كے بارے ميں قرآن كے نقطہ نظر كا تعين ہي قرآن كي رائے معلوم كرنے كا بہترين نہيں تو كم از كم ايك اچھا راستہ ضرور ہے ۔
معاشرتي حوالے سے قرآني الفاظ كي دو قسميں ہيں بعض كا تعلق معاشرتي آثار سے ہے، جيسے ملت، شريعت، شرعہ، منہاج، سنت اور ان جيسے دوسرے الفاظ جن پر گفتگو ہمارے موضوع سے خارج ہے ليكن الفاظ جو سب كے لئے يا انساني گروہوں كے لئے اجتماعى عنوان كے حامل ہيں، صحيح طور پر قرآن كے نقطہ نگاہ كو مشخص كر سكتے ہيں، جيسے قوم، امت، ناس، شعوب، قبائل، رسول، نبى، امام، ولى، مومن، كافر، منافق، مشرك، مذبذب، مہاجر، مجاہد، صديق، شہيد، متقى، صالح، مصلح، مفسد، امر بالمعروف، نہي عن المنكر، عالم، ناصح، ظالم، خليفہ، ربانى، ربى، كاہن، رہبان، احبار، جبار، عالى، مستعلى، مستكبر، مستضعف، مسرف، مترف، طاغوت، ملا، ملوك، غنى، فقير، مملوك، مالك، جبر، عبد، رب وغيرہ ۔
البتہ بظاہر ان سے مشابہت ركھنے والے دوسرے الفاظ بھي ہيں ۔ جيسے مصلى، مخلص، صادق، منفق، مستغفر، تائب، عابد، حامد اور ان جيسے ديگر الفاظ ليكن يہ الفاظ جماعتوں اور گروہوں سے ہٹ كر صرف ايك طرح كے ”افعال“ كو ذكر كرنے كے لئے آئے ہيں ۔ اسي لئے ان كے بارے ميں يہ احتمال نہيں ہو سكتا كہ ان ميں گروہوں، جماعتوں اور معاشرتي طبقات كي گفتگو ہے ۔
اب يہ ضروري ہے كہ ان آيتوں كا جن ميں پہلے گروہ كے الفاظ كا تذكرہ ہے اور خاص طور پر وہ آيتيں جو اجتماعى رخ كو معين كرتي ہيں، بنظر غائر مطالعہ كيا جائے تاكہ يہ بات كھل جائے كہ ان سب كو دو گروہوں ميں سمويا جا سكتا ہے يا ان كے لئے متعدد گروہوں كي ضرورت ہے؟ اگر بالفرض انہيں دو گروہوں ميں سمويا جاسكتا ہو، تو كن دو گروہوں كو ان كے لئے مختص كيا جائے؟
يعني كيا ان سب كو اعتقادى موقف اختيار كرنے والے دو گروہوں، جو مومن اور كافر سے عبارت ہيں، ميں تقسيم كيا جائے يا اس تقسيم كي بنياد اقتصادي حالت كو بيان كرنے والے دو گروہوں يعني غنى اور فقير كے حوالے سے ہو؟ بعبارت ديگر تمام تقسيمات فرعي ہيں يا ايسا نہيں؟ اگر ايك تقسيم پر منتہي ہوتي ہيں تو وہ اصلي تقسيم كيا ہے؟ بعض لوگوں كا خيال ہے كہ معاشرے سے متعلق قرآن كا نقطہ نگاہ دو طبقوں كا حامل ہے ۔ ان كے بقول قرآن كي رو سے معاشرے كے دو طبقے ہيں، ايك مسلط اور دوسرا محكوم ۔ مسلط طبقے ميں مستكبرين اور ان كے مخالف اور محكوم حلقے ميں وہ لوگ ہيں جنہيں قرآن ميں ”مستضعفين“ كا نام ديا گيا ہے ۔ مومن كافر يا موحد اور مشرك يا صالح و فاسد، جيسي تمام تقسيمات فرعي پہلو كي حامل ہيں يعني يہ ظالم طاقتيں اور بے جا ظلم ہے جو كفر و شرك و نفاق وغيرہ كو وجود ميں لاتا ہے اور اس كے مقابلے ميں مظلوميت انسان كو ايمان، ہجرت، جہاد، صلاح، اصلاح وغيرہ كي طرف كھينچتي ہے، بعبارت ديگر وہ باتيں جنہيں قرآن عملى، اخلاقى يا اعتقادى انحراف سے ياد كرتا ہے، بنيادي طور پر اقتصادي روابط كي خاص كيفيات ہيں يعني استحصال كا عمل ہيں اور وہ باتيں جن كي قرآن اعتقادى، اخلاقى يا عملي اعتبار سے تائيد و تاكيد كرتا ہے بنيادي طور پر مظلوميت اور محكوميت ہيں ۔ انسان كا ضمير فطرتاً اور جبراً اپني مادي زندگي كي صورت حال كا تابع ہے، مادي حالات ميں تبديلي كے بغير لوگوں كے روحانى، نفسياتي اور اخلاقى حالات ميں تبديلي ناممكن ہے، يہي وجہ ہے كہ قرآن طبقاتي جدوجہد كي شكل ميں معاشرتي تحريكوں كو صحيح اور بنيادي قرار ديتا ہے، يعني وہ اقتصادي يا اخلاقى جدوجہد كي نسبت اجتماعى جدوجہد كو افضليت اور اصالت ديتا ہے ۔ قرآن كے اعتبار سے كافر، منافق، مشرك، فاسق، فاجر اور ظالم ان گروہوں سے ابھرتے ہيں جنہيں قرآن ”مترف“، ”مسرف“، ”ملا“، ”ملوك“، ”مستكبر“ اور ان جيسے ناموں سے ياد كرتا ہے ممكن نہيں كہ ايسے گروہ متقابل طبقے سے ابھريں اور يہ بالكل اسي طرح ہے جس طرح پىغمبر، رسول، امام، صديق، شہيد، مجاہد، مہاجر اور مومن مستضعف گروہ سے ابھرتے ہيں اور مقابل طبقہ سے ان كا ابھرانا ناممكن ہے، پس يہ استكبار و استضعاف ہے جو معاشرتي مزاج كو بتاتا ہے، اسے ايك سمت عطا كرتا ہے بقيہ تمام اور انہي كے مظاہر و تجليات ہيں ۔
قرآن نہ صرف يہ كہ ان گروہوں كو مستكبر و مستضعف كے دو اصلي طبقوں كے مظاہر سمجھتا ہے بلكہ اس نے ايك طرف صداقت، عفاف، اخلاص، عبادت، بصيرت، رافت، رحمت، فتوت، خشوع، انفاق، ايثار، خشيت اور فروتني جيسي صفات و ملكات كي طرف اشارہ كيا ہے اور اس كے مقابلے ميں كذب، خيانت، فجور، ريا، نفس پرستى، كور دلى، قساوت، بخل اور تكبر جيسي برائيوں كا ذكر كيا اور پہلے گروہ كي خصوصيات كمزور بنائي جانے والي جماعت كي صفات اور دوسرے گروہ كي خصوصيات كو كمزور بنانے والوں كي صفات سے تعبير كيا ہے ۔
پس كمزور بنانا اور كمزور بننے پر مشتمل دائرہ عمل نہ صرف مخالف اور متضاد گروہوں كا مركز طلوع ہے بلكہ متضاد اخلاقى صفات و ملكات بھي اس سے پھوٹتي ہيں اور يہ ہر انتخاب پر رجحان اور ہر سمت كے تعين، يہاں تك كہ تمام ثقافتي اور مدني آثار كي بنياد ہے، كمزور بنانے والے طبقے سے ابھرنے والا اخلاق، فلسفہ، آرٹ، علم و ادب اور مذہب اس كي اجتماعى موقف كو بيان كرتا ہے جو تمام كا تمام موجودہ حالات كو صحيح ثابت كرنے ميں مصروف ہوتا ہے اور معاشرے كے جمود و ركود اور توقف كي اصل وجہ ہے، ليكن اس كے برخلاف مستضعفين يا زمين پر كمزور بنائے جانے والے طبقے كا اخلاق، فلسفہ ، علم و ادب، آرٹ اور مذہب، بيدار ركھنے والا حركت آفرين اور انقلابى ہوتا ہے ۔
مستكبر يا جابر حكمران طبقہ اپني آقائيت اور اپني معاشرتي امتيازي خصوصيات كے باعث تاريك انديش، روايت پسند اور عافيت طلب ہوتا ہے جب كہ مستضعف و محكوم طبقہ اس كے برخلاف بيدار، روايت شكن، انقلابى، مصمم، پرجوش و پرعزم ہوتا ہے ۔
مختصر يہ كہ ان افراد كے عقيدے كے مطابق قرآن اس كي تائيد كرتا ہے كہ وہ چيز جو انسان كو بناتي اور اس كے گروہ كو مشخص كرتي ہے، اسے رخ حيات ديتي اور اس كے فكرى، اخلاقى، مذہبى اور نظرياتي مقام كو معين كرتي ہے وہ اس كي معاشي حالت ہے اور مجموعي طور پر قرآني آيات سے يہ ظاہر ہوتا ہے كہ قرآن نے اپني تعليم كو اسي بنياد پر قائم كيا ہے ۔
اس اعتبار سے ايك خاص طبقے سے وابستگي ہر شے كا معيار ہے اور اسي معيار كے ذريعے تمام دعوؤں كو جانچا جا سكتا ہے، مومن، مصلح، رہبر يہاں تك كہ نبى يا امام كي تائيد و تكذيب بھي اسي كسوٹي كے ذريعے ہوني چاہيے ۔
يہ نظريہ حقيقتاً انسان اور معاشرے كے بارے ميں ايك مادي نقطہ نظر ہے، اس ميں كوئي شك نہيں كہ قرآن نے افراد كي اجتماعى حيثيت كا بطور خاص تذكرہ كيا ہے، ليكن كيا اس كا يہ مفہوم ہے كہ قرآن تمام نفسيات اور تمام طبقہ بنديوں كي اسي معيار پر توجيہ كرتا ہے؟ ہماري نظر ميں انسان دنيا اور معاشرے سے متعلق اسلامي نقطہ نظر اس نوعيت كے معاشرتي نقطہ نظر سے ہم آہنگ نہيں ہے اور يہ قرآني مسائل كے ايك سطحي مطالعے سے پىدا ہوا ہے، چونكہ ہم كتاب كے اس باب ميں جہاں تاريخ پر اس عنوان سے بحث ہوئي ہے كہ ”كيا طبيعت تاريخ مادي ہے؟ “، اس موضوع پر مكمل گفتگو كريں گے لہٰذا في الوقت اس موضوع كو يہيں رہنے ديتے ہيں ۔
معاشروں كي يگانگت يا ان كا تنوع بہ اعتبار ماہيت
اس مسئلہ كا بيان بھي جيسا كہ پہلے اشارہ ہوچكا ہے ہر مكتب فكر كے لئے ضروري ہے كيونكہ اسي گفتگو سے يہ بات واضح ہوتي ہے كہ كيا تمام انساني معاشرے ايك نظريہ حيات كے تابع ہو سكتے ہيں يا معاشروں كا تنوع مختلف نظريہ ہائے حيات كي پىداوار ہے اور ہر قوم، ہرملت، ہر تمدن اور ہر ثقافت كو خاص نظريہ حيات ( Ideology ) كي ضرورت ہے كيونكہ نظريہ حيات ان منصوبوں اور ان راستوں سے عبارت ہے جو معاشرے كو كمال و سعادت كي طرف لے جاتے ہيں، ہم يہ بھي جانتے ہيں كہ ہر نوع، اپني ايك خاص استعداد اور عليحدہ آثار و خواص كي حامل ہوتي ہے اور اس كا كمال و سعادت ہوتي ہے۔گھوڑے كے لئے كمال اور سعادت بعينہ گوسفند يا انسان كے لئے كمال اور سعادت نہيں ہے ۔ پس اگر تمام معاشروں كے لئے اصالت و غيبت كو فرض كر ليا جائے اور وہ سب ايك ذات، ايك طبيعت اور ايك ماہيت كے حامل ہوں تو ان كے لئے ايك واحد نظريہ حيات ہي ممكن ہوسكتا ہے اور اس صورت ميں ان كے اختلافات بھي ايسے ہوں گے جيسے ايك نوع كے افراد كے درميان ہوتے ہيں، ہر زندہ نظريہ حيات جزئيات كے اختلاف كے بارے ميں لچك اور انطباق كي قابليت ركھتا ہے، ليكن اگر معاشرے طبيعتوں، ماہيتوں اور ذوات ميں مختلف ہوں گے تو يہ فطري امر ہے كہ ان كے منصوبے، ان كے لائحہ ہائے عمل، ان كے نظريات اور ان كے لئے كمال و سعادت بھي متنوع ہوں گے اور واحد نظريہ حيات ان سب كا احاطہ نہيں كر سكے گا۔
بالكل يہي صورت آپ كو وقت كے دوش پر گذرتے ہوئے معاشروں كے انقلابات ميں ملتي ہے، كيا معاشرے اپنے انقلابات كي راہ ميں اپني نوعيت اور ماہيت بدلتے ہيں؟ اور اس طرح معاشروں كي حد تك تبدل انواع كا قانون جاري ہوتا ہے يا ان كے معاشرتي انقلابات كي كيفيت ايك نوع كے ايك فرد ميں رونما ہونے والي تبديليوں كي مانند ہے كہ جس كي ماہيت اور نوعيت محفوظ رہتي ہے ۔
پس پہلے مسئلے كا تعلق معاشرے سے ہے اور دوسرے كا تاريخ سے، ہم في الحال پہلے مسئلے كے بارے ميں گفتگو كريں گے اور دوسرے مسئلے كو تاريخ كي بحث ميں لايا جائے گا۔
عمرانيات كا مطالعہ يہ بتائے گا كہ معاشروں كے درميان مشترك ذاتي خواص موجود ہيں يا نہيں؟ كيا ان كے درميان فرق كو ہم سطحي كہہ سكتے ہيں اور اس فرق كے سبب يا معلول كو معاشرے كي ذات اور طبيعت سے باہر تصور كر سكتے ہيں اور معاشرے كي ذات اور طبيعت سے تعلق ركھنے والي تمام چيزوں كو يكساں جان سكتے ہيں، يا يہ كہ كہيں كہ بنيادي طور پر معاشرے اپني ذات اور طبيعت ميں مختلف ہيں لہٰذا بالفرض بيروني شرائط كے اعتبار سے ان ميں يكسانيت ہو ، تو بھي ان كا عمل مختلف ہوگا اور يہ خود وہ راستہ ہے كہ اس سلسلے ميں جن كے بارے ميں ابہام ہے، فلسفہ خود ان اشياء كو ان كي نوعي وحدت و كثرت كي پركھ كے لئے پىش كرتا ہے، يہاں ايك نزديك كا راستہ بھي موجود ہے اور وہ خود حضرت انسان ہے۔انسان كے بارے ميں ايك امر مسلم يہ ہے كہ انسان نوع واحد ہے، علم حياتيات كے اعتبار سے انسان جب سے وجود ميں آيا ہے اس ميں كوئي حياتياتي تبديلي رونما نہيں ہوئي ہے، بعض سائنس دانوں كا كہنا ہے كہ عالم طبيعت ميں جانداروں كے كمال كے نتيجے ميں انسان بن گيا اور انسان تك پہنچ كر طبيعت نے راستہ بدل ليا اور ارتقائي عمل زيست سے اجتماع ميں منتقل ہوگيا اور اس كا ارتقائي عمل جسماني سے روحاني اور معنوي گذرگاہ ميں منتقل ہوگيا ۔
گذشتہ اوراق ميں ہم انسان كے مدني الطبع ہونے كي بحث ميں اس نتيجے پر پہنچے تھے كہ انسان جو انواع كا نہيں بلكہ نوع واحد كا حامل ہے، اپني فطرت اور طبيعت كے اعتبار سے اجتماعى ہے يعني انسان كا اجتماعى رجحان اور اس كا گروہ و جماعت كي صورت ميں رہنا اور اس كا اجتماعى روح كا حامل ہونا، اس كي نوع اور اس كي ذات كا خاصہ ہے اور يہ انساني نوع كے فطري خواص ميں سے ہے ۔ انسان اس كمال تك پہنچنے كے لئے جس كي صلاحيت اس ميں ركھ دي گئي ہے، اجتماعى ميلان كا حامل ہے ۔ اس سے اجتماعى روح كے لئے بنياد فراہم ہوتي ہے ۔ اجتماعى روح اپني جگہ خود ايك وسيلہ ہے جو انساني نوع كو اپني انتہائے كمال تك پہنچاتا ہے، لہٰذا انسان كي نوع ہي اس كي اجتماعى روح كے راستے كا تعين كرتي ہے، جو خود اپنے مقام پر انساني فطرت كي خدمت ميں مصروف ہے ۔ انساني فطرت جب تك انسان باقي ہے، اپني مصروفيت جاري ركھے گي پس انفرادي روح يا يوں كہہ ليجئے انسان كي انساني فطرت پر اجتماعى روح كا دارومدار ہے اور چونكہ انسان نوع واحد ہے لہٰذا انساني معاشرے بھي يكساں ذات، يكساں طبيعت اور يكساں ماہيت كے حامل ہيں ۔ البتہ جيسے ايك فرد كبھي فطرت كے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے بلكہ كبھي مسخ بھي ہو جاتا ہے، اسي طرح معاشرہ بھي كبھي اپنے فطري راستے كو چھوڑ ديتا ہے ۔ معاشروں كا تنوع، افراد كے اخلاقى تنوع كي طرح ہے جو كسي بھي صورت انسان كے نوع ہونے كے دائرے سے باہر نہيں ہوتا لہٰذا معاشرے، ثقافتيں، تہذيبيں مختصر يہ كہ اجتماعى روح جو معاشروں پر حكم فرما ہے اپنے ڈھانچے اور اپني رنگت ميں اختلاف كے باوجود انساني نوع ہي كي حامل ہے اور غير انساني ماہيت نہيں ركھتي ۔
ہاں! اگر ہم معاشرتي تركيب كے چوتھے نظريے كو قبول كر ليں اور افراد كو قابل جذب مادوں اور ظرفيت ركھنے والي خالي برتنوں كي طرح جانيں اور منكر فطر ہوجائيں تو پھر معاشروں كے نوعي اور ماہيتي اختلاف كو پىش كر سكتے ہيں، ليكن يہ نظريہ ڈوركم كے انداز فكر كي شكل ميں كسي طرح بھي قابل قبول نہيں ۔ اس لئے كہ وہ پہلا سوال جو اس ميں لاجواب رہ جاتا ہے يہ ہے كہ اگر اجتماعى روح كا ابتدائي سرمايہ فرديت اور انسان كے طبيعي يا حياتياتي پہلو سے نہ نكلے تو پھر وہ كہاں سے وجود ميں آئے؟ كيا اجتماعى روح كا وجود خالصتاً عدم سے پھوٹا ہے؟ كيا اجتماعى روح كي توجيہ كے لئے يہ كہنا كافي ہوگا كہ جب سے انسان كا وجود رہا ہے، معاشرہ اس كے ساتھ ہے؟ علاوہ ازيں خود ”ڈوركم“ كہتا ہے كہ اجتماعى امور يعني وہ امور جن كا تعلق معاشرے سے ہے انہيں اجتماعى روح نے خلق كيا ہے ۔ مذہب، اخلاق اور آرٹ جيسي چيزيں ہر معاشرے ميں رہي ہيں اور ہميشہ رہيں گي اور خود ڈوركم كي تعبير كے مطابق يہ سب چيزيں ”ہميشگي“ اور ”ہمہ جائيت“ ركھتي ہيں اور يہ خود اس بات كي دليل ہے كہ ڈوركم بھي اجتماعى روح كے لئے ماہيتي اور نوعي اكائي كا قائل ہے ۔
اسلامي تعليمات كو جو دين كے لئے ايك واحد نوعيت كي قائل ہيں اور شريعتوں كے اختلاف كو فرعي جانتي ہيں، نہ كہ ماہيتي اور دوسري طرف ہميں يہ بھي معلوم ہے كہ دين انفرادي اور اجتماعى ارتقاء سے متعلق لائحہ عمل كے سوا كچھ بھي نہيں، تو ظاہر ہوتا ہے كہ ان تعليمات كي بنياد معاشروں كي نوعي وحدت پر ہے اور اگر معاشرے نوعيت كے اعتبار سے متعدد ہوتے تو كمال اور اس تك پہنچنے كي راہيں متعدد ہوتيں اور پھر ماہيت اديان كا مختلف اور متعدد ہونا لازمي تھا ۔ قرآن كريم اصرار اور صراحت كے ساتھ كہتا ہے كہ دين تمام علاقوں، معاشروں، وقتوں اور زمانوں ميں ايك سے زيادہ نہيں رہا ہے، بااعتبار قرآن اديان (بصورت جمع) كوئي حقيقت نہيں ركھتے ۔ دين ہميشہ بصورت مفرد موجود رہا ہے، تمام انبياء الٰہي كا ايك ہي دين ، ايك ہي راستے اور ايك ہي مقصد كي طرف انسانوں كو بلاتے رہے ہيں ۔
( شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسيٰ و عيسيٰ ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . (سورہ شوريٰ، آيت۔ ۱۳)
”تمہارے لئے اس نے دين كي وہي باتيں مقرر كيں جن كي بابت اس نے نوح كو پىش تر وصيت كي تھي اور (اے رسول!) جس كي بابت ہم نے تمہاري طرف وحي كي ہے اور جس كي بابت ہم نے ابراہيم اور موسيٰ و عيسيٰ كو وصيت كي تھي ۔ وہ يہي تھي كہ دين كو قائم ركھو اور اس ميں اختلاف نہ ڈالو ۔“
ايسي آيتيں قرآن ميں كثرت سے مليں گے، جو يہ ثابت كرتي ہيں كہ دين ہر زمانے، ہر علاقے اور ہر پىغمبر كي زبان پر ايك ہي رہا ہے، البتہ شريعتوں كے اختلافات رائے نقص و كمال كے اختلافات ميں سے ہيں ۔ دين كے ماہيتاً ايك ہونے كي منطق انسان اور انساني معاشرے كي اس فكر پر ہے كہ انسان انواع نہيں بلكہ نوع واحد ہے اور بالك اسي طرح انساني معاشرہ ايك واقعيت عيني ہونے كے اعتبار سے انواع نہيں بلكہ نوع واحد ہے۔
معاشروں كا مستقبل
آج كے معاشروں، تمدنوں، ثقافتوں كو اگر ہم بالفرض نوع اور ماہيت كے اعتبار سے مختلف نہ بھي جانيں تو بھي كيفيت اور شكل و صورت كے اعتبار سے ان كا مختلف ہونا ناقابل انكار ہے ۔ انساني معاشرے آگے چل كر كيا صورت اختيار كريں گے؟ كيا يہ ثقافتيں، يہ تمدنيں، يہ معاشرے اور يہ قوميں بالكل اسي طرح اپني حالت پر باقي رہيں گي يا ايك تمدن، ايك ثقافت اور ايك معاشرے كي سمت انسانيت كا سفر جاري و ساري رہے گا اور يہ سب آگے چل كر مستقبل ميں اپنا روپ بدل ليں گے اور ايك رنگ ميں ڈھل جائيں گے، جو اصلي اور انسانيت كا رنگ ہوگا ۔ اس مسئلے كا تعلق بھي معاشرے كي ماہيت، اجتماعى اور انفرادي روح كے ايك دوسرے سے وابستہ ہونے كي نوعيت پر ہے، ظاہر ہے فطرت كي اصالت اور اس نظريے كي بنياد پر ہے كہ انسان كا اجتماعى وجود اس كي اجتماعى زندگي يعني معاشروں كي اجتماعى روح ايك ايسا وسيلہ ہے جسے انسان كي نوعي فطرت نے كمال مطلق تك پہنچنے كے لئے انتخاب كيا ہے ۔
يہ كہنا بجا ہوگا كہ معاشرے، ثقافتيں اور تہذيبيں ايك اكائي ہونے، متحد الشكل ہونے اور آخر كار ايك دوسرے ميں مدغم ہونے كي سمت گامزن ہيں اور انساني معاشروں كا مستقبل ايك كمال يافتہ عالمي اكائي پر مبني معاشرہ ہوگا جس ميں انسانيت سے متعلق تمام امكاني اقدار عملي صورت اختيار كرليں گے ۔ يہ وہ منزل ہوگي جہاں، انسان اپنے حقيقي كمال و سعادت اور اس انسانيت كو پہنچے گا، جو اصيل ہوگي ۔
قرآن كي رو سے يہ بات مسلم ہے كہ قطعي حكومت حق كي حكومت اور باطل كي مكمل نابودي سے عبارت ہے اور انجام كار متقىن كے لئے ہے۔
تفسير الميزان ميں ہے:
”كائنات كے بارے ميں گہري جستجو اس بات كو ظاہر كرتي ہے كہ انسان بھي كائنات كے ايك جزو كي حيثيت سے آئندہ اپني غايت و كمال كو پہنچے گا ۔“(۴)
قرآن كا يہ ارشاد كہ عالم ميں نفاذ اسلام ايك حتمي امر ہے، دراصل اسي بات كي دوسري تعبير ہے كہ انسان كو بالآخر كمال مطلق تك پہنچنا ہے۔ قرآن كہتا ہے:
( من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه. ) (سورہ مائدہ، آيت۵۴)
”بالفرض اگر تم اس دين سے پھر جاؤ تو اللہ بشريت كو اس دين كے ابلاغ اور اسے مستحكم كرنے كے لئے تمہارے بجائے دوسري قوم كو لے آئے گا ۔“
يہاں در حقيقت مقصود يہ ہے كہ ضرورت خلقت اور انسان كے انجام كار كو بتلا يا جائے، اس ضمن ميں يہ آيت بھي ملاحظہ ہو:
( وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) (سورہ نور، آيت ۵۵)
”اللہ نے وعدہ كيا ہے كہ تم ميں سے وہ لوگ جو ايمان لائے اور عمل صالح كرتے رہے انہيں وہ ضرور زمين ميں جانشين بنائے گا اور ضرور ان كے دين كو جسے اس نے ان كے لئے پسند كيا ہے، نافذ كرے گا اور يقينا انہيں خوف ميں ايك عرصہ گذارنے كے بعد امن عطا كرے گا (دشمنوں كو مٹا دے گا) تاكہ پھر وہ ميري ہي عبادت كريں اور كسي چيز كو (ميري اطاعت ميں) ميرا شريك قرار نہ ديں ۔“ (توحيد كے مباحث ميں اس پرگفتگو ہو چكي ہے)
اس كے بعد ايك دوسري آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:
( ان الارض يرثها عبادي الصالحون )
”يہي امر حتمي ہے كہ ميرے صالح اور شائستہ بندے ہي زمين كے وارث ہوں گے ۔“
”الميزان“ ہي ميں ہے كہ اسلامي ملك كي سرحديں، جغرافيائي حدود يا معاہداتي رقبے نہيں بلكہ عقائد ہيں ۔ اس سلسلے ميں صاحب الميزان لكھتے ہيں:
”اسلام نے قومي تفريقات كي بنياد كو اس اعتبار سے كہ تشكيل معاشرہ ميں موثر كردار كي حامل ہوں، رد كيا ہے ۔ ان تفريقات كي دو اصلي وجوہات ہيں:
ايك نسلي رابطہ كي اساس پر قائم شدہ قبيلوں كي ابتدائي زندگي اور دوسري جغرافيائي خطوں كا اختلاف ۔ انہي دو چيزوں نے نوع انساني كو قوموں، قبيلوں اور اختلاف زبان و رنگ ميں بانٹ ديا ہے، يہي وہ دو اسباب ہيں، جو آگے چل كر اس بات كا سبب بنے كہ ہر قوم ايك خطے كو اپنے لئے مخصوص كر لے اور اسے وطن سے منسوب كر كے اس كے دفاع پر آمادہ ہو جائے ۔
يہ وہ پہلو ہے جس طرف طبيعت ( Nature ) انسان كو كھينچتي ہے، ليكن اس ميں ايك ايسي چيز موجود ہے جو انساني فطرت كے تقاضے كے خلاف ہے اور اس بات كا سبب بنتي ہے كہ انسان ايك ”كل“ اور ايك ”يونٹ“ كي صورت ميں زندگي بسر كرے ۔ قانون طبيعت بكھرے ہوؤں كو سميٹنے اور متفرق كو يكجا كرنے كي اساس پر قائم ہے اور اسي كے ذريعے طبيعت اپني غايتوں كو حاصل كرتي ہے ۔
يہ وہ امر ہے كہ جو مزاج طبيعت سے ہمارے سامنے آيا ہے اور ہم ديكھتے ہيں كہ كس طرح اصلي مادہ، عناصر اور پھر نباتات، پھر حيوان اور پھر انسان تك پہنچتا ہے ملكي اور قبائلي تفريقات ايك ملك يا قبيلے كو ايك مركز اتحاد پر لاتي اور اس كے ساتھ ساتھ وہ انہيں كسي دوسري وحدت كے بھي مقابل قرار ديتي ہيں، اس طرح كہ ايك قوم كے افراد آپس ميں ايك دوسرے كو تو اپنا بھائي سمجھتے ہيں مگر دوسرے انسان ان كي نظر ميں مد مقابل قرار پاتے ہيں اور وہ انہيں اس نگاہ سے ديكھتے ہيں، جس نگاہ سے اشياء كو ديكھا جاتا ہے ، يعني ان كي نگاہ منفعت جوئي اور سود و زياں پر ہوتي ہے اور يہي وجہ ہے كہ اسلام نے قومي اور قبائلي تفريقات كو جس سے انسانيت ٹكڑے ٹكڑے ہوجاتي ہے، رد كيا ہے اور انساني معاشرے كو نسل، قوم يا وطن كي بنياد نہيں بلكہ (كشف حق اور اس سے لگاؤ كے) عقيدے پر قرار ديا ہے (جو سب كے لئے يكساں ہے) يہاں تك كہ زوجيت اور ميراث كے بارے ميں بھي عقيدہ كے اشتراك كو معيار قرار ديا ہے ۔“(۵)
اسي طرح ”دين حق بالآخر كامياب ہے“ كے زير عنوان صاحب تفسير الميزان لكھتے ہيں:
”نوع انسان اس فطرت كے تحت جو اس ميں وديعت كي گئي ہے اپنے متعلق كمال و سعادت كي خواہاں ہے، يعني وہ اجتماعى صورت ميں اعليٰ ترين مادي اور معنوي مراتب زندگي كي خواہشمند ہے ۔ ايك دن يہ اسے مل جائيں گے ۔ اسلام جو دين توحيد ہے، اسي طرح كي سعادت كا ايك لائحہ عمل ہے اس طولاني مسافت ميں جن انحرافات سے انسان كو واسطہ پڑتا ہے، انہيں انساني فطرت كے بطلان اور اس كي صورت سے منسوب نہيں كرنا چاہيے۔ ہميشہ انسان پر اصلي حاكميت فطرت ہي كي ہوتي ہے اور بس انحرافات اور اشتباہات تطبيق ميں خطا كي حيثيت ركھتے ہيں ۔
وہ كمال و غايت جسے انسان اپني بے قرار فطرت كے حكم كے مطابق حاصل كرنا چاہتا ہے، ايك دن (جلد يا بدير) ضرور اسے حاصل ہو جائے گي ۔ سورہ روم كي تيسري آيت جو اس جملہ سے شروع ہوتي ہے:
( فاقم و جهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها ) اور( لعلم يرجعون ) پر ختم ہوتي ہے ۔
اس مفہوم كو ظاہر كرتي ہے كہ حكم فطرت آخر الامر اتباع چاہتا ہے اور انسان بھٹكتا ہوا اور تجربات سے گذرنے كے بعد اپني راہ پالے گا اور اسے نہيں چھوڑے گا۔ان لوگوں كي باتوں پر كان نہيں دھرنا چاہيے جو اسلام كو اس طرح ديكھتے ہيں جيسے يہ انساني ثقافت كا ايك مرحلہ ہے۔
جس نے اپني ذمہ داري پوري كر دي ہے اور اب تاريخ كا ايك حصہ بن گيا ہے ۔ اسلام اس مفہوم ميں كہ جس ميں ہم اسے جانتے ہيں اور اس پر بحث كرتے ہيں، عبارت ہے قطعي كمال پر مبني انسان سے جو بضرورت ناموس خلقت ايك دن يقينا اس تك پہنچے گا ۔“(۶)
بعض لوگوں كا دعويٰ اس كے برعكس ہے اور كہتے ہيں كہ اسلام كسي صورت بھي انساني ثقافت اور انساني معاشرے كي يگانگت كے حق ميں نہيں ہے بلكہ وہ ان كے تنوع اور تعداد كا حامي ہے اور اسي تنوع اور تعداد كو باضابطہ طور پر مانتا اور ثابت كرتا ہے، وہ كہتے ہيں:
ايك قوم كي حيثيت، ہويت اور خودي اس كي اپني ثقافت سے عبارت ہے اور يہ ثقافت اس قوم كي اجتماعى روح كي ہے۔ اس اجتماعى روح كو اس قوم كي اپنے سے متعلق وہ خاص تاريخ بناتي ہے، جس ميں دوسري قوموں كا كوئي دخل نہيں ہوتا، عالم طبيعت انسان كي نوعيت كو بناتا ہے اور تاريخ اس كي ثقافت كو بلكہ در حقيقت يہ اس كي حيثيت، رويے اور حقيقي خودي كي معمار ہے۔ ہر قوم اپنے سے متعلق ايك خاص ثقافت، ايك خاص ماہيت اور خاص طرح كے رنگ و مزاج و اصول كي حامل ہے، جو اس كي حيثيت كي تكميل كرتي ہے اور اس ثقافت كي حفاظت كرتي ہے يعني اس ملت كي ہويت كي حفاظت كرتي ہے ۔
جس طرح كسي فرد كي ہويت اور حيثيت خود اسي سے متعلق ہوتي ہے اور اس كو چھوڑ كر دوسري ہويت اور دوسري شخصيت كو اپنانا گويا اپنے آپ كو اپنے سے سلب كرنا ہے يعني مسخ ہونا اور اپنے آپ سے بيگانہ ہونا ہے، كسي قوم كے لئے ہر وہ كلچر بيگانہ و اجنبي ہے جو تاريخ ميں كبھي اس كي مزاج سازي ميں دخيل نہ ہوا ہو، يہ بات كہ ہر قوم ايك خاص قسم كا احساس فكر، ذوق، پسند، ادب، موسيقى، حساسيت اور آداب و رسول ركھتي ہے اور كچھ ايسي چيزوں كو پسند كرتي ہے جو دوسري قوموں كے مزاج سے مختلف ہوتي ہيں، اس لئے ہے كہ يہ قوم اپني تاريخ ميں كاميابيوں، ناكاميوں، ثروتوں، محروميوں، آب وہوا كي كيفيتوں، مہاجرتوں، رابطوں اور نامور نابغہ لوگوں سے متعلق مختلف وجوہات كي بناء پر ايك خاص كلچر كي حامل ہوگئي ہے۔ اس خاص كلچر يا اس خاص ثقافت نے اس كي قومي و اجتماعى روح كو ايك خاص صورت ميں اور خاص زاويوں كے ساتھ بنايا ہے۔ فلسفہ، علم، ادبيات، ہنر، مذہب اور اخلاق وہ عناصر ہيں جو كسي انساني گروہ كے مشترك تاريخي سلسلے ميں ايك خاص صورت اور ايك خاص تركيب اختيار كرتے ہيں اور اس كي ماہيت وجودي كو دوسرے انساني گروہوں كے مقابل الگ تشخص ديتے ہيں اور اس تركيب سے ايك ايسي روح جنم ليتي ہے جو ايك گروہ كے افراد كو ”اعضائے يك پىكر“ كے مانند ايك حياتي اور اعضائي ارتباط ديتي ہے يہي وہ روح ہے جو اس پىكر كو نہ صرف ايك الگ مشخص وجود بخشتي ہے، بلكہ ايك ايسي زندگي عطا كرتي ہے جو تاريخ ميں ديگر روحاني اور ثقافتي پىكروں كے مقابل اس كي وجہ شناخت بن جاتي ہے، كيوں كہ يہ روح اس كي اجتماعى روش، اس كے طرز فكر، جماعتي عادات، ردعمل، طبيعت، حيات، واقعات، احساسات، ميلانات، خواہشات اور عقائد كے مقابل انساني تاثرات ميں حتيٰ كہ اس كي تمام سائنسى، فني اور ہنري ايجادات ميں بلكہ يوں كہيے كہ انساني زندگي كے تمام مادي اور معنوي جلوؤں ميں بڑي محسوس و ممتاز ہے ۔
كہا جاتا ہے كہ مذہب ايك طرح كي آئيڈيالوجى (نظريہ حيات) ہے، عقيدہ اور ايسے خاص عواطف و اعمال كا مجموعہ ہے جو اس عقيدے كے نتيجے ميں وجود ميں آتے ہيں ليكن قوميت تشخص ہے اور ان ممتاز خصائص كي حامل ہے جو ايك ہي تقدير سے وابستہ انسانوں كي مشترك روح كو جنم ديتي ہے۔ اس اعتبار سے قوميت اور مذہب كے درميان وہي رابطہ ہے جو تشخيص اور عقيدہ كے درميان ہے ۔
كہتے ہيں نسلي امتيازات اور قومي تفاوت سے متعلق اسلام كي مخالفت كو مختلف قوميتوں كي مخالفت پر منطبق نہيں كرنا چاہيے، اسلام ميں برابري اور يكسانيت كے اصول قوموں كي نفي كے مفہوم ميں نہيں ہيں بلكہ اس كے برعكس اسلام ايك مسلم اور ناقابل انكار طبيعي حقيقت كے عنوان سے قوميتوں كے وجود كا معترف ہے۔
( يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثي وجعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم )
كہتے ہيں كہ اس آيت كے ذريعے اسلام كے نقطہ نظر سے قوميتوں كي نفي اور انكار پر استدلال كيا جاتا ہے جبكہ يہ بالكل برعكس قوميتوں كے اثبات اور ان كي تائيد پر دليل ہے كيوںكہ آيت سب سے پہلے (ذكور و اناث پر مبني) انسانيت كو بااعتبار جنسيت تقسيم كرتي ہے اور يہ ايك طبيعي تقسيم ہے، پھر فوراً شعوب و قبائل كے اعتبار سے انساني گروہ بندي كا تذكرہ ہوتا ہے اور يہ اس امر كو ظاہر كرتا ہے كہ شعوب و قبائل ميں لوگوں كي گروہ بندي مرد و زن كي تقسيم بندي كي طرح ايك طبيعي اور الٰہي امر ہے۔
يہ آيت اس بات كو واضح كرتي ہے كہ اسلام جس طرح مرد و زن كے درميان خصوصي رابطے كا طرف دار ہے اور جنسيت اور اس كے آثار كو ختم كرنا نہيں چاہتا، اسي طرح قوموں كے درميان مساوات كي بنياد پر رابطے كا حامي ہے اور انہيں مٹانے كے حق ميں نہيں ہے۔ يہ جو قرآن نے قوموں كي تشكيل كو جنسوں كي پىدائش كي طرح خدا سے نسبت دي ہے، اس كا معني يہ ہے كہ مشخص قوموں كا وجود خلقت ميں ايك طبعي حقيقت ہے۔ يہ جو قرآن نے قوموں كے وجودي اختلاف كي غرض و غايت كو ”تعارف“ (قوموں كي آپس ميں شناخت) كہا ہے۔ اس بات كي طرف اشارہ ہے كہ ايك قوم دوسري قوم كے مقابل اپني شناخت تك رسائي حاصل كرتي اور اپنے آپ كو پاتي ہے، ايك قوميت دوسري قوميت كے مقابل اپنے تشخص كو اجاگر كر كے قوت پىدا كرتي ہے۔
لہٰذاجو مشہور ہے، اس كے برخلاف اسلام ثقافت كے مفہوم ميں نيشنلزم كا مخالف نہيں بلكہ حامي ہے، وہ جس نسلي مفہوم ميں نيشنلزم كا مخالف ہے، وہ نسل پرستي ہے۔
يہ نظريہ كسي اعتبار سے مخدوش ہے، اولاً يہ كہ اس كا دارومدار انسان كے بارے ميں كسي خاص نظريے اور انسان كے ثقافتي اصول و مواد يعني فلسفيٰ، علم، فن اور اخلاق وغيرہ كے بارے ميں بھي كسي خاص نظريے پر ہے، جو دونوں مخدوش ہيں۔ انسان كے بارے ميں يہ فرض كيا گيا ہے كہ وہ فكر كے اعتبار سے، مشاہدہ كائنات كے اعتبار سے، عاطفي اعتبار سے اور اس اعتبار سے كہ كس چيز كو چاہے اور كون سا راستہ اختيار كرے اور كس منزل كي سمت چلے اپني ذات ميں ہر صلاحيت سے خالي ہے چاہے بالقوت ہي سہي۔ تمام افكار، تمام عواطف، تمام راستے اور تمام اہداف اس كے لئے يكساں ہيں۔ وہ ايك بے شكل و بے رنگ خالي ظرف كي طرح ہے جو ہر شے كو مظروف سے ليتا ہے، اس كي خودى، اس كي شخصيت، اس كا راستہ، اس كي منزل سب مظروف كي مرہون منت ہے ۔
اس كا مظروف اسے جس طرح كا تشخص دے گا، جس طرح كا راستہ اور جس منزل كو اس كے لئے معين كرے گا، وہ اسي كا پاپند ہوگا، يہي اس كي حقيقي شكل، حقيقي رنگ، حقيقي تشخص اور حقيقي راہ و منزل ہوگى، كيوں كہ ايسي مظروف سے اس كي ”خود“ كو قوام اور سہارا ملا ہے۔ اب اس كے بعد اس كي شخصيت، اس كے رنگ اور اس كي شكل كو اس چھيننے كے لئے جو كچھ بھي اسے ديا جائے گا، اس كے لئے وقتي اور بيگانہ ہوگا، كيوں كہ وہ اس پہلے تشخص كے خلاف ہوگا جسے تاريخ نے اپنے اتفاقي عمل سے بنايا ہے بعبارت ديگر، يہ نظريہ فرد اور معاشرے كي اصالت سے متعلق چوتھے نظريے سے ہم آہنگ ہے جو خالص اجتماعى اصالت پر مبني ہے اور جس پر ہم پہلے اعتراض كر چكے ہيں ۔
انسان كے بارے ميں با اعتبار فلسفي ہو يا بااعتبار اسلامى، اس طرح كا فيصلہ نہيں كيا جا سكتا۔ انسان اپني خاص نوعيت كے اعتبار سے بالقوہ ہي سہي ايك معين تشخص، معين راہ اور مقصد كا حامل ہے اور يہ چيز اسے الٰہي فطرت سے ملتي ہے، يہي فطرت اس كي حقيقي ”خود“ كو معين كرتي ہے۔ انسان كے مسخ ہونے يا نہ ہونے كو تاريخي معيار پر نہيں بلكہ انسان كے فطري اور نوعي معيار پر سمجھا جا سكتا ہے۔ ہر وہ تعليم اور ہر وہ كلچر جو انسان كي انساني فطرت سے ہم آہنگ ہو اور اسے پروان چڑھانے والا ہو، حقيقي و اصيل كلچر ہے۔ہر چند كے تاريخي حالات كے باعث اسے اوليت حاصل نہ ہو اور ہر وہ كلچر جو انسان كي انساني فطرت سے مطابقت نہ ركھتا ہو، اس كے لئے اجنبي اور غير ہے، ايك طرح سے اس كي حقيقي ہويت كو بدلنے والا، مسخ كرنے والا ہے اور اسے ”خود“ سے ”ناخود“ بنانے والا ہے۔ اگرچہ اس كي پىدائش قومي تاريخ كا كرشمہ كيوں نہ ہو مثلاً عقيدہ ثنويت اور آگ كي تقديس ايراني انسانيت كا مسخ ہے اگرچہ وہ اس كي تاريخ ہي سے كيوں نہ ابھري ہو، ليكن توحيد يكتا پرستي اور غير خدا كي پرستش سے دوري حقيقي انسانيت ہويت كي سمت اس كي بازگشت ہے۔ اگرچہ وہ باہر سے آئي ہو اور اس كي سرزمين نے اسے نہ ديا ہو ۔
انساني كلچر كے مواد سے متعلق خيال بھي غلط فرض كيا گيا ہے كہ يہ ان بے رنگ مادوں كي طرح ہے جن كي كوئي خاص شكل اور خاص تشخص نہيں ہوتا۔ ان كي شكل اور ان كي كيفيت كو تاريخ بناتي ہے، يعني فلسفہ بہرحال فلسفہ ہے اور اسي طرح سائنس، سائنس ہے۔ مذہب، مذہب ہے۔ اخلاق، اخلاق ہے اور آرٹ، آرٹ ہے خواہ وہ كسي شكل اور كسي رنگ ميں كيوں نہ ہو۔ ليكن يہ بات كہ اس كا رنگ اور كيفيت كيا ہوگى، يہ ايك نسبي امر ہے اور اس كي وابستگي تاريخ سے ہے، ہر قوم كي تاريخ ، اس كا كلچر، اس كا فلسفہ، اس كا مذہب، اس كي سائنس، اس كا اخلاق اور اس كا فن متقاضي ہے كہ وہ خود اس سے مخصوص ہو ۔
بعبارت ديگر جس طرح انسان اپني ذات ميں بے شكل و بے ہويت ہے اور اس كا كلچر اسے شكل و ہويت ديتا ہے، انساني كلچر كے حقيقي مواد و اصول بھي خود اپني ذات ميں بے شكل و صورت ہيں، تاريخ انہيں رنگ عطا كرتي ہے اور ان پر اپنا خاص رنگ جماتي ہے۔ بعض لوگ اس نظريے ميں يہاں تك آگے بڑھ گئے ہيں كہ اب ان كا يہ دعويٰ ہے كہ
”علم رياضي كي طرف فكر بھي ہر كلچر كے خاص ڈھب كے زير اثر قائم ہے ۔“(۷)
يہ نظريہ انساني كلچر كے نسبي ہونے كا نظريہ ہي ہے، ہم نے ”اصول فلسفہ“ ميں اصول فكر كے اطلاق اور نسبيت كے بارے ميں گفتگو كي ہے اور يہ ثابت كيا ہے كہ نسبي چيزيں اعتباري اور عملي علوم و ادراكات ہيں اور يہي وہ ادراكات ہيں جو مختلف ثقافتوں ميں مختلف زماني اور مكاني شرائط كے مطابق مختلف ہو اكرتے ہيں۔ نيز يہي وہ ادراكات ہيں جو اپني سطح سے ہٹ كر كسي دوسري حقيقت كے بارے ميں فيصلہ كرنے اور ان كے لئے حق وباطل اور غلط و صحيح كا معيار بننے سے معذور ہيں، ليكن وہ نظري افكار و ادراكات و علوم جو انسان كے نظري علوم اور فلسفے كو بنانے والے ہيں، مثلاً اصول مطالعہ، كائنات با اعتبار مذہب اور اخلاق كے بنيادي اصول پكے مطلق اور غير نسبي ہيں۔ مجھے افسوس ہے كہ ميں يہاں اس سے زيادہ اس گفتگو كو آگے نہيں بڑھا سكتا ۔
ثانياً يہ جو كہا جاتا ہے كہ مذہب عقيدہ ہے اور قوميت تشخص ہے اور ان دونوں كا رابطہ عقيدے اور تشخص كا رابطہ ہے اور يہ كہ اسلام قومي تشخصات كو اسي طرح استحكام بخشتا ہے اور انہيں اصولي طور پر مانتا ہے جيسي كہ وہ ہيں، مذہبى ابلاغ و ہدايت كي سب سے بڑي نفي ہے۔ مذہب وہ بھي اسلام جيسے مذہب كي ذمہ داري يہ ہے كہ وہ محور توحيد پر قائم كلي نظام سے متعلق ايك صحيح اور بنيادي انداز فكر ہميں دے اور اسي انداز فكر كي بنياد پر نوع بشر كي روحاني اور اخلاقى شخصيت كو سنوارنے اور افراد اور معاشرے كي انہيں خطوط پر پرورش كا لازمہ ہے كہ ايك نئي ثقافت كا بيج بويا جائے جو قومي نہيں انساني ثقافت ہے۔ يہ جو اسلام نے دنيا كو كلچر ديا اور آج ہم اسے اسلامي كلچر كے نام سے ياد كرتے ہيں اس لئے نہيں تھا كہ ہر مذہب كم و بيش اپنے لوگوں كے درميان موجود كلچر ميں گھل مل جاتا، اس سے متاثر ہوتا اور كم و بيش اسے اپنے زير اثر لے آتا ہے، بلكہ اس لئے تھا كہ كلچر بنانا اس مذہب كے متن ابلاغ ميں ركھ ديا گيا ہے۔ اسلامي كي ذمہ داري يہ ہے كہ وہ لوگوں كو اس كلچر سے باہر نكالے جس ميں انہيں نہيں ہونا چاہيے اور وہ چيزيں انہيں دے جن كي ان كے پاس كمي ہے اور وہ چيزيں جن كا ہونا ان كے لئے ضروري ہے اور ان كے پاس بھي ہيں، انہيں استحكام بخشے جسے قوموں كي مختلف ثقافتوں سے كوئي سروكار نہ ہو اور وہ سب سے ہم آہنگ ايسا مذہب ہے كہ جو پورے ہفتے ميں صرف ايك بار چرچ والوں ہي كے كام آسكتا ہے اور بس ۔
ثالثاً: ”( انا خلقنا كم من ذكر و انثي ) “ كا يہ مفہوم نہيں كہ ہم نے تمہيں دو طرح كي جنس خلق كيا ہے، يہ كہا جائے كہ اس آيت ميں سب سے پہلے انسان كو جنسيت كي بنياد پر تقسيم كيا ہے، پھر فوراً قومي تقسيم كي بات آئي ہے اور ساتھي ہي يہ نتيجہ نكالا جائے كہ آيت يہ سمجھانا چاہتي ہے كہ جس طرح اختلاف جنسيت ايك طبيعي امر ہے اور كسي مكتب فكر كو اس كي اساس پر استوار ہونا چاہيے نہ كہ اس كي نفي كي اساس پر، قوميت ميں اختلاف كي صورت بھي يہي ہے۔
آيت كا مفہوم يہ ہے كہ ہم نے تمہيں مرد اور عورت سے خلق كيا ہے، خواہ اس كا مطلب يہ ہو كہ تمام انسانوں كا نسلي رابط ايك مرد اور ايك عورت (آدم و حوا) پر منتہي ہوتا ہے اور خواہ يہ ہو كہ تمام انسان اس اعتبار سے يكساں ہيں كہ سب كا باپ ہوتا ہے اور سب كي ماں ہوتي ہے اور اس اعتبار سے كہيں كوئي امتياز نہيں ہے ۔
رابعاً: ”لتعارفوا“ جو آيہ كريمہ ميں بعنوان غايت استعمال ہوا ہے، اس مفہوم ميں نہيں ہے كہ قوموں كو اس اعتبار سے مختلف قرار ديا گيا ہے كہ وہ ايك دوسرے كي شناخت پىدا كر ليں اور اس سے يہ نتيجہ نكالا جائے كہ قوموں كو لازمي طور پر جداگانہ حيثيتوں سے باقي رہنا چاہيے تاكہ وہ اپنے مدمقابل كي شناخت سے بہرہ ور ہو سكيں، اگر يہي بات تھى، تو ”لتعارفوا“ (ايك دوسرے كي شناخت كرو) كے بجائے ”ليتعارفوا“ (ايك دوسرے كي شناخت كريں) استعمال ہوتا كيوں كہ مخاطب عوام ہيں اور انہي عام افراد سے خطاب ہے كہ يہ جو گروہ يا تفريقات اس وجہ سے وجود ميں آئي ہيں متن خلقت ميں كسي حكمت سے اس كا سروكار ہے اور وہ حكمت يہ ہے كہ تم لوگ قوموں اور قبيلوں كي نسبت كے ساتھ ايك دوسرے كو پہچانو اور ہم جانتے ہيں كہ يہ حكمت اس بات پر موقوف نہيں كہ تمام قوميتيں لازمي طور پر جداگانہ حيثيت سے ايك دوسرے سے عليحدہ رہيں ۔
خامساً: جو كچھ ہم نے گذشتہ اوراق ميں معاشرہ كي يگانگي اور تنوع سے متعلق اسلامي نقطہ نگاہ كو پىش كيا اور بتايا كہ معاشروں كا طبيعي اور تكويني سفر يگانہ معاشرے اور يگانہ ثقافت كي طرف ہے اور اسلام كا بنيادي لائحہ عمل اسي ثقافت اور اسي معاشرے كا استحكام ہے۔ مذكورہ بالا نظريے كي ترديد كے لئے كافي ہے ۔
اسلام ميں فلسفہ ”مہدويت“ اسلام، انسان اور عالم كے مستقبل كے بارے ميں اسي طرح كے نظريے كي اساس پر قائم ہے اور اسي منزل پر ہم معاشرے سے متعلق اپني اس بحث كا خاتمہ كر كے تاريخ كو زير بحث لاتے ہيں ۔
تاريخ كيا ہے؟
تاريخ كي تعريف تين طرح سے ہو سكتي ہے۔درحقيقت تاريخ سے متعلق تين ايسے علوم ہونے چاہيں جو ايك دوسرے سے قريبي تعلق ركھتے ہوں۔
۱۔ زمانہ حال ميں موجود حالات و كيفيات كے بجائے گذرے ہوئے انسانوں كے اوضاع اور احوال اور بيتے ہوئے حادثات كا علم، ہر وہ كيفيت، ہر وہ حالت، ہر وہ واقعہ و حادثہ جس كا تعلق زمانہ حال سے ہو يعني اس زمانے سے ہو كہ جس ميں ابھي اس پر گفتگو چل رہي ہو، ”آج كا واقعہ“ اور ”آج كا حادثہ“ ہوگا اور جب يہ قيد تحرير ميں آجائے گا تو ”روزآنہ“ كہلائے گا۔ ليكن جونہي اس كي تازگي ختم ہوجائے گي اور وقت كي طنابيں كھينچ جائيں گى، يہ تاريخ كا حصہ بن جائے گا۔ پس اس مفہوم ميں علم تاريخ ان حادثات، واقعات اور ان افراد كے حالات و كيفيات پر مبني علم ہے جو گذشتہ سے اپنا رشتہ جوڑ چكے ہيں وہ تمام سوانح عمرياں، ظفرنامے اور سيرتوں پر مشتمل كتابيں جو ہر قوم ميں تاليف ہوئي ہيں اور ہو رہي ہيں، اسي ضمن ميں آتي ہيں ۔
علم تاريخ اس مفہوم ميں اولاً جزو ہے، كليات كا علم نہيں، يعني اس كا تعلق انفرادي اور ذاتي امور كے ايك سلسلے سے ہے نہ كہ قواعد و ضوابط، روابط اور كليات سے۔ ثانياً يہ عقلي نہيں نقلي علم ہے۔ ثالثاً اس كا تعلق كيوں ہوا سے نہيں، كيسے تھا سے ہے۔ رابعاً اس كي وابستگي حال سے نہيں ماضي سے ہے۔ ہم اس طرح كي تاريخ كو ”نقلي تاريخ“ كي اصطلاح ديتے ہيں۔
۲۔ گذشتہ زندگيوں پر حكم فرما قواعد و روايات كا علم جو ماضي ميں رونما ہونے والے واقعات اور حوادث جو نقلي تاريخي ہيں، كے مطالعے اور تحليل و تجزيہ سے حاصل ہوتاہے۔ يعني گذشتہ كے حوادث و واقعات اس علم كے مبادي و مقدمات كي حيثيت ركھتے ہيں اور درحقيقت يہ حوادث و واقعات، تاريخ كے اس دوسرے مفہوم ميں ايك ايسے مواد كا حكم ركھتے ہيں اور درحقيقت يہ حوادث و واقعات، تاريخ كے اس دوسرے مفہوم ميں ايك ايسے مواد كا حكم ركھتے ہيں، جسے طبيعات كا سائنس دان اپني تجربہ گاہ ميں اس لئے اكٹھا كرتا ہے كہ اس پر تجزيہ و تحقيق كر كے اس كي خاصيت اور فطرت معلوم كرے اور اس كے علت و معلول سے متعلق رابطے كو سمجھے، تاريخي حوادث كا مزاج دريافت كرنے اور ان كے سبب و مسبب كو جاننے كي ٹوہ ميں ہوتا ہے تاكہ قواعد و ضوابط كا وہ عمومي سلسلہ اس كے ہاتھ آئے جس سے حال، مشابہ امور ميں ماضي كي صورت اختيار نہ كرے۔ ہم اس معني ميں تاريخ كو ”علمي تاريخ“ كي اصطلاح كا نام ديتے ہيں ۔
ہرچند كہ علمي تاريخ كا موضو ع تحقيق، وہ واقعات اور وہ حادثات ہيں، جن كا تعلق گذشتہ سے ہے، ليكن يہ جو مسائل اور قواعد استنباط كرتا ہے گذشتہ سے مخصوص نہيں ہوتے بلكہ عموميت ركھتے ہيں اور آئندہ پر بھي منطبق كئے جا سكتے ہيں۔
تاريخ كا يہ رخ اسے بڑا سود مند بنا ديتا ہے۔يہ انساني معرفت يا انساني شناخت كا ايك مآخذ بن كر انسان كو اس كے مستقبل پر دسترس ديتا ہے۔ علمي تاريخ كے محقق اور ماہر علم طبيعات كا كاموں ميں يہ فرق ہے كہ علم طبيعات كے ماہر كا تحقيقي مواد ايك موجود اور حاضر عيني مواد ہے جو لازماً اپني تحقيق اور تحليل و تجزيہ ميں عيني اور تجرباتي پہلو ركھتا ہے، ليكن مورخ كا تحقيقي مواد گذشتہ دور ميں تو تھا ليكن اب نہيں ہے صرف اس سے متعلق كچھ اطلاعات اور كچھ ريكارڈ مورخ كے پاس ہوتا ہے۔ مورخ اپنے فيصلوں ميں عدالت كے ايك قاضي كي طرح ہوتا ہے جو ريكارڈ ميں موجود دلائل و شواہد كي بنياد پر اپنا فيصلہ صادر كرتا ہے۔ اس كے پاس منطقى، ذہني اور عقلي تحليل ہے، خارجي اور عيني تحليل نہيں۔ مورخ اپنے تجزيوں كو خارجي تجربہ گاہ ميں يا قرع و انبيق جيسے آلات كے ذريعے انجام نہيں ديتا، بلكہ اس كا عمل عقل كي تجربہ گاہ ميں قياس و استدلال كے آلات سے ہوتا ہے، لہٰذا مورخ اس جہت سے علم طبيعات كے ماہر كي نسبت ايك فلسفي كے مشابہ ہوتا ہے۔
علمي تاريخ بھي نقلي تاريخ كي طرح سے ہي حال سے نہيں گذشتہ سے متعلق ہے۔ يہ علم”كيوں ہوا “كا نہيں، ” كيسے تھا“ سے متعلق علم ہے ليكن نقلي تاريخ كے برخلاف كلي ہے جزوي ہے، نيز عقلي ہے محض نقلي نہيں ۔
علمي تاريخ درحقيقت عمرانيات كا ايك حصہ ہے، يعني گذشتہ معاشروں سے متعلق عمرانيات كا موضوع مطالعہ عمومي ہے، جو معاصر معاشرے اور گذشتہ معاشرے دونوں پر محيط ہے ۔
اگر ہم عمرانيات كو معاصر معاشروں كي شناخت كے لئے مختص كر ديں، تو پھر علمي تاريخ اور عمرانيات دو الگ علم ہوں گے، ليكن رشتہ ميں ان كا ايك دوسرے سے قريبي تعلق ہوگا اور وہ ايك دوسرے كے ضرورت مند ہوں گے۔
۳۔ فلسفہ تاريخ يعني معاشروں كے ايك مرحلے سے دوسرے مرحلوں ميں جانے اور انقلابات سے دوچار ہونے كا علم، نيز ان قوانين كا علم جن كا ان انقلابات پر سكہ رہا ہے۔ بعبارت ديگر:يہ ”كيوں ہوا“ كا علم ہے نہ كہ ”كيسے تھا“ كا علم۔ ممكن ہے محترم قارئين كا ذہن اس طرف جائے كہ كيا يہ ممكن ہے كہ معاشروں ميں ”كيسے تھا“ بھي ہواور ”كيوں ہوا“ بھي جبكہ ”كيسے تھا“، ”علمي تاريخ“ كے نام سے كسي علم كا موضوع ہو ليكن فلسفہ تاريخ كے نام سے كسي دوسرے علم كا موضوع ہو؟ جبكہ ان دونوں كے درميان اجتماع ناممكن ہے كيوں كہ ”كيسے تھا“ سكون ہے اور ”كيوں ہوا“ حركت، لہٰذا ان دونوں ميں سے ايك كا انتخاب كرنا ہوگا۔ گذشتہ معاشروں كے بارے ميں ہمارے پردہ ذہن كي تصوير يا ”كيسے تھا“ سے متعلق ہوني چاہيے يا ”كيوں ہوا“ سے۔ ممكن ہے محترم قارئين اشكال كو زيادہ كلي اور زيادہ جامع بنا كر پىش كريں اور وہ يوں كہ كلي طور پر كائنات اور معاشرہ بااعتبار اس كے كہ كلي كائنات كا ايك جزو ہے، سے متعلق ہماري شناخت اور پردہ ذہن كي تصوير يا ساكن اور ايستادہ امور ميں سے ہے يا ان ميں سے ہے جن ميں تحريك پايا جاتا ہے، اگر دنيا يا معاشرہ ساكن يا ايستادہ ہے تو پھر اس ميں”كيسے تھا“تو ہوگا۔ ”كيوں ہوا“ نہيں اور اگر يہ متحرك ہے تو اس ميں ”كيوں ہوا“ ہوگا، ”كيسے تھا“ نہيں۔ اس اعتبار سے ہم ديكھتے ہيں كہ يہ اہم ترين فلسفي نظام دو بنيادي گروہوں ميں تقسيم ہوتے ہيں ايك ”كيسے تھا“ كا فلسفہ اور دوسرا ”كيوں ہوا“ كا فلسفہ۔ پہلا فلسفہ وہ جو ”ہونے“ اور ”نہ ہونے“ كو ناقابل جمع اور متناقص قرار ديتا ہے۔ جہاں ”ہونا“ ہے وہ ”نہ ہونا“ نہيں اور جہاں ”نہ ہونا“ ہے وہاں ”ہونا“ نہيں۔ پس ان دونوں ميں سے ايك كا انتخاب ضروري ہے مگر چونكہ ضرورتاً ”ہونا“ ہے اور دنيا اور معاشرہ ايك حرف عبث نہيں لہٰذا اس دنيا پر ”سكون“ اور قيام كي حكومت ہے۔ ”كيوں ہوا“ كا فلسفہ وہ ہے كہ جو ”ہونے“ اور ”نہ ہونے“ كو آن واحد ميں قابل جمع جانتا ہے اور يہ حركت ہي ہے۔ حركت سوائے اس كے اور كچھ نہيں كہ كوئي شے اور باوجود ہونے كے نہ ہو۔ پس ”كيسے تھا“ كا فلسفہ اور ”كيوں ہوا“ كا فلسفہ ہستي كے بارے ميں دو بالكل متضاد اور مختلف نظريے ہيں۔ ان ميں سے ايك كا انتخاب كرنا ہوگا۔ اگر ہم پہلے گروہ ميں اپنے آپ كو شامل كر ليں تو ہميں يہ فرض كرنا ہوگا كہ معاشروں ميں ”ہونا“ رہا ہے ”نہ ہونا“ نہيں۔ اس كے برعكس اگر ہم دوسرا گروہ اختيار كر ليں تو وہاں معاشرے ”نہ ہونے“ سے متعلق ہيں، ”ہونے“ سے نہيں۔ پس ہمارے پاس گذشتہ مفہوم كے مطابق يا علمي تاريخ ہے اور فلسفہ تاريخ نہيں يا فلسفہ تاريخ ہے اور علمي تاريخ نہيں۔ جواب يہ ہے كہ ہستي اور نيستى، حركت و سكون اور امتناع تناقص كے قانون كے بارے ميں اس طرح كي سوچ مغربي انداز فكر ہے اور يہ ہستي كے فلسفي مسائل خاص طور ”اصالت وجود“ كے عميق مسئلے اور بہت سے ديگر مسائل سے ناواقفيت پر مبني ہے ۔
اول يہ كہ ”ہونا“ سكون كے مساوي بعبارت ديگر سكون ”ہونا“ ہے اور حركت ہونے نہ ہونے كے درميان ملاپ ہے يعني دو نقيضوں كا ملاپ ہے، يہ بات ان بڑے اشتباہات ميں سے ہے جن سے مغرب كے بعض فلسفي دوچار ہوئے ہيں، ثانياً جو كچھ يہاں ذكر ہوا ہے، اس كا اس فلسفي مسئلے سے كوئي واسطہ نہيں ہے۔ يہاں جو بات كہي گئي وہ يہ ہے كہ معاشرہ ہر زندہ وجود كي طرح دو قسم كے قوانين كا حامل ہے۔ ايك وہ قوانين جو ہر نوع كے دائرہ نوعيت پر حكم فرما ہے اور دوسرے وہ جو انواع كے تغيرات اور ان كے آپس ميں تبديلي سے وابستہ ہوتے ہيں۔ ہم پہلي قسم كو ”كيسے تھا“ اور دوسري كو ”كيوں ہوا“ سے متعلق قوانين كي اصطلاح ديتے ہيں ۔
اتفاقاً بعض بہت اچھے ماہرين عمرانيات نے اس نكتہ پر توجہ مبذول كي ہے، ”آگسٹ كانٹ“ انہي ميں سے ہے۔ ”ريمون آرون“ كہتا ہے: حركت اور سكون ”آگسٹ كانٹ“ كي عمرانيات كے دو خاص مقولے ہيں۔ سكون اس موضوعي مطالعے سے متعلق ہے، جسے آگسٹ كانٹ نے اجتماعى اجماع (يا اجتماعى توافق) كا نام ديا ہے۔ معاشرہ ايك اعضاء كے ايك مجموعے ( Organism ) كي طرح زندہ ہے۔ جس طرح بدن كے كسي حصے كي كاركردگي كو سمجھنے كے لئے يہ ضروري ہوتا ہے كہ اسے اس زندہ كل سے وابستہ كيا جائے جس كا وہ خود ايك حصہ ہے۔ اسي طرح حكومت اور سياست كي جانچ پڑتال كے لئے بھي يہ ضروري ہوتا ہے كہ اسے تاريخ كے ايك معين وقت ميں معاشرے كے كل سے وابستہ كيا جائے۔ آغاز ميں حركت ان پے در پے مراحل كي سادہ سي توصيف سے عبارت ہے جسے انساني معاشرے طے كرتے چلے آئے ہيں ۔
دودھ پلانے والے جانور ہوں يا رينگنے والے كيڑے، پرند ہوں يا چرند، مختلف انواع كے زندہ موجودات كي ہر نوع كو اگر ديكھا جائے تو معلوم ہوگا كہ يہ اپنے خاص قوانين سے متصل ہيں جن كا تعلق ان كي نوعيت سے ہوتا ہے۔ جب تك وہ اپني اس نوع كي حدود ميں رہتے ہيں، مذكورہ قوانين ان پر لاگو ہوتے ہيں۔ جيسے كسي حيوان كے مراحل جين سے متعلق قوانين يا اس كي صحت يا بيماري يا طرز پىدائش و پرورش يا انداز حصول غذا ء يا پھر اس كي مہاجرت، جبلت اور توالد و تناسل سے متعلق قوانين ليكن تبديلي و تكامل انواع كے نظريے(۸) كے مطابق خصوصي قوانين كے علاوہ ہر نوع اپنے نوعيت ميں كچھ اور قوانين بھي ركھتي ہے جو تبديلي و تكامل انواع اور ان كي پستي سے بلندي تك پہنچنے سے متعلق ہے۔ يہي قوانين ہيں جو فلسفي شكل اختيار كرتے ہيں اور جسے ہم فلسفہ تكامل تو كہہ سكتے ہيں مگر علم حياتيات نہيں، معاشرہ بھي اس اعتبار سے كہ ايك زندہ وجود ہے، دو طرح كے قوانين كا حامل ہے: ايك قوانين حيات اور دوسرے قوانين تكامل۔ وہ قوانين جن كا تعلق تمدنوں كي پىدائش اور ان كے انحطاط كے اسباب سے ہے اورجو معاشروں كي شرائط حيات كو معين كرتے ہيں اور جن كي حكمراني تمام معاشروں، اطوار اور تغيرات پر ہے، انہيں ہم معاشروں كے قوانين كي اصطلاح كہتے ہيں اور وہ قوانين جو معاشروں كے ايك عہد سے دوسرے عہد ميں ارتقاء پانے اور ايك نظام سے دوسرے نظام ميں جانے سے متعلق ہيں، ان كے لئے معاشروں كي ”كيوں ہوا“ كے قوانين كي اصطلاح لاتے ہيں، بعد ميں جب ہم دونوں قسم كے مسائل كو پىش كريں گے تو ان كا فرق بہتر طور پر واضح ہوگا۔ پس علم تاريخ تيسرے مفہوم ميں معاشروں كے ايك مرحلے سے دوسرے مرحلے ميں جانے اور تكامل پانے سے متعلق علم ہے۔ ان كي زندگي كا علم نہيں جو ان كے ايك خاص مرحلے يا تمام مراحل حيات كي عكاسي كرے۔ہم نے ان مسائل كے لئے ”فلسفہ تاريخ“ كي اصطلاح اس لئے پىش كي ہے تاكہ ان مسائل كا ان مسائل پر گمان نہ ہو، جنہيں ہم نے علمي تاريخ كے نام سے ياد كيا ہے۔ علمي تاريخ سے نسبت پانے والے مسائل جن كا تعلق معاشرے كي غير تكاملي حركات سے ہے، ان مسائل سے جدا نہيں كئے جا سكتے جو فلسفہ تاريخ سے متعلق ہيں اور جن كي نسبت معاشرے كي تكاملي حركات سے ہے اور اس لئے اشتباہات رونما ہوتے ہيں۔
فلسفہ تاريخ علمي تاريخ كي طرح كلي ہے جزوي نہيں، عقلي ہے نقلي نہيں۔ ليكن علمي تاريخ كے برخلاف يہ معاشروں كے ”كيوں ہوا“ كا علم ہے ”كيسے تھا“ كا نہيں۔ نيز علمي تاريخ كے برخلاف فلسفہ تاريخ سے متعلق مسائل كا تاريخ سے رشتہ صرف يہ نہيں ہے كہ وہ گزرے ہوئے زمانے سے وابستہ ہيں بلكہ يہ ان واقعات كي نشاندہي كرتے ہيں جن كا آغاز گذشتہ زمانے ميں ہوا اور جن كا عمل اب بھي جاري ہے اور آئندہ بھي رہے گا۔ زمانہ اس طرح كے مسائل كے لئے محض ايك ”ظرف“ نہيں بلكہ يہ ان مسائل كے پہلوؤں سے ايك پہلو ہے ۔
علم تاريخ اپنے تينوں مفاہيم ميں مفيد ہے يہاں تك كہ نقلي تاريخ بھي جس كا تعلق اشخاص كي سيرت اور ان كے حالات سے ہو، سود مند ، انقلاب آفرين، مربي اور تعميري ہو سكتي ہے۔ البتہ يہ اس بات سے وابستہ ہے كہ ہم كن افراد كي تاريخ حيات كا مطالعہ كرتے ہيں اور ان كي زندگي سے كن نكات كو ليتے ہيں۔ انسان جس طرح ”محاكات“ كے قانون كے تحت اپنے زمانے كے لوگوں كي ہم نشينى، ان كي رفتار و كردار اور ارادوں سے متاثر ہوتا ہے اور جس طرح معاصر لوگوں كي زندگي اس كے لئے سبق آموز اور عبرت انگيز ہوتي ہے، نيز جس طرح وہ اپنے زمانے كے لوگوں سے ادب اور راہ و رسم زندگي سيكھتا ہے اور كبھي لقمان كي طرح بے ادبوں سے ادب سيكھتا ہے تاكہ ان جيسا نہ ہو، اسي طرح گذشتہ لوگوں كي سرنوشت بھي اس كے لئے باعث ہدايت ہوتي ہے۔ تاريخ ايك براہ راست نشر ہونے والي فلم كي طرح ہے جو ماضي كو حال ميں بدلتي ہے، اسي لئے قرآن كريم ان افراد كي زندگي كے مفيد نكات كو پىش كرتا ہے، جو نمونہ عمل اور ”اسوہ“ بننے كي صلاحيت ركھتے ہيں اور اس بات كي تصريح بھي كرتا ہے كہ انہيں ”اسوہ“ قرار دو۔ جب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے:( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) . (سورہ احزاب، آيت ۲۱)
”رسول اللہ صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كي زندگي ميں تمہارے لئے ايك عمدہ نمونہ حيات موجود ہے ۔“
حضرت ابراہيم عليہ السلام كے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے:( قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذي معه ) . (سورہ ممتحنہ، آيت۵)
”ابراہيم اور ان كے ساتھ رہنے والوں ميں تمہارے لئے ”اسوئہ حسنہ“ موجود ہے ۔“
قرآن ”اسوہ“ كے عنوان سے جن ہستيوں كو پىش كرتا ہے وہاں اس كے پىش نظر ان كي دنياوي شخصيت نہيں ہوتي بلكہ وہ ان كي اخلاقى اور انساني شخصيت كو پىش نظر ركھتا ہے۔ جيسے ايك سياہ رنگ غلام لقمان جو بادشاہ تھے نہ مشہور فلسفي اور نہ ہي دولت مندوں ميں ان كا شمار ہوتا تھا بلكہ اس كے برعكس ايك غلام تھے مگر صاحب بصيرت تھے۔ قرآن نے انہيں حكيم و دانا كے نام سے ياد كيا ہے اور ان كے علم كو حكمت و دانائي كہا ہے يہي صورت ”مومن آل فرعون“ اور ”مومن آل ياسين“ كي ہے ۔
اس كتاب ميں جس ميں ہم معاشرے اور تاريخ كو اسلامي طرز فكر كي روشني ميں پىش كر رہے ہيں، ہمارے مطمع نظر صرف ”سائنسي تاريخ“ اور ”فلسفہ تاريخ“ ہے، كيوں كہ تاريخ كے يہي وہ دو رخ ہيں جو طرز فكر كے كلي مفہوم كے دائرے ميں آتے ہيں ۔
اس اعتبار سے ہم اپني گفتگو كو ان دونوں موضوعات كے بارے ميں كچھ آگے بڑھاتے ہيں اور ”سائنسي تاريخ“ سے آغاز كلام كرتے ہيں ۔
سائنسي تاريخ
سب سے پہلے مقدمہ كے طور پر يہ ياد آوري ضروري ہے كہ علمي تاريخ اس مفہوم پر مبني ہے، جسے ہم گذشتہ اوراق ميں عرض كر چكے ہيں اور وہ يہ كہ افراد سے الگ معاشرہ اصالت و حيثيت كا حامل ہے، اگر افراد سے جدا معاشرہ اصالت كا حامل نہ ہو تو افراد اور ان پر لاگو قوانين كے علاوہ كچھ بھي نہ ہوگا اور اس كے نتيجہ ميں علمي تاريخ جو معاشروں پر حكم فرما قواعد و ضوابط كا علم ہے، باقي نہيں رہے گا، تاريخ كسي قانون كي حامل تب ہو سكتي ہے جب تاريخ كوئي طبيعت ركھتي ہو اور تاريخ كسي طبيعت كي حامل تب ہو سكتي ہے جب معاشرہ كوئي طبيعت ركھتا ہو۔ سائنسي تاريخ كے بارے ميں مندرجہ ذيل مسائل كا مطالعہ ضروري ہے:
۱۔ علمي تاريخ جيسا كہ پہلے عرض كيا جا چكا ہے، نقلي تاريخ پر منحصر ہے، نقلي تاريخ علمي تاريخ كي تجربہ گاہ كے لئے مواد كي حيثيت ركھتي ہے، پس سب سے پہلے يہ تحقيق ضروري ہے كہ نقلي تاريخ معتبر اور قابل اعتماد ہے بھي يا نہيں۔ اگر قابل اعتماد نہيں ہے، تو پھر گذشتہ معاشروں پر حاكم قوانين كے بارے ميں كسي طرح كي علمي تحقيق بيہودہ اور عبث ہے ۔
۲۔ بالفرض ”نقلي تاريخ“ قابل اعتماد ہو اور معاشرے كے لئے افراد سے الگ حيثيت اور طبيعت كو مان ليا جائے، تاريخ حوادث و واقعات سے كلي قواعد اور قوانين كا استنباط اس بات پر موقوف ہے كہ قانون ”عليت“ اور جبر و سبب و مسبب انساني مسائل كے حدود و اختيارات ميں موجود ہو، يعني ان مسائل ميں موجود ہو، جو انسان كے ارادہ و اختيار سے وابستہ ہيں اور جن ميں تاريخي واقعات بھي شامل ہيں، وگرنہ قابل عموميت و كليت نہيں اور انہيں قاعدے اور ضابطے كے تحت نہيں ليا جا سكتا۔ كيا قانون عليت تاريخ پر مسلط ہے؟ اگر ہے تو پھر آزادى اور اختيار كے بارے ميں انسان كا رويہ كيا ہونا چاہيے؟
۳۔ كيا تاريخ ”ميٹر يالسٹ“ ہے اور مادي طبيعت كي حامل ہے؟ كيا تاريخ پر حكم فرما اصلي طاقت مادي ہے اور تمام روحاني طاقتيں تاريخ كي مادي طاقت كے تابع ہيں اور ان كي صورت فرعي يا طفيلي كي سي ہے؟ يا اس كے برعكس طبيعت تاريخ معنوي ہے اور تاريخ پر حاكم طاقت ايك معنوي طاقت ہے اور مادي طاقتيں اس كي فرع، اس كي تابع اور طفيلي ہيں؟ يعني كيا تاريخ خود اپني ذات ميں مثاليت پسند ہے يا كوئي تيسري صورت موجود ہے؟ اور وہ يہ ہے كہ تاريخ كي طبيعت مخلوط ہے اور اس ميں دو يا كئي طاقتوں كا عمل دخل ہے اور متعدد مادي اور معنوي طاقتيں كم و بيش ايك ہم آہنگ اور كبھي متضاد نظام كي صورت ميں تاريخ پر حكومت كرتي ہيں؟
۱۔ نقلي تاريخ كا معتبر يا بے اعتبار ہونا
كچھ لوگ نقلي تاريخ سے شديد بدظن ہيں، وہ تمام واقعات كو ناقلين كي جعل سازي جانتے ہيں جوذاتي اغراض و مقاصد يا قومي اور مذہبى تعصبات يا پھر اجتماعى تعلقات كي بنياد پر واقعات كو نقل كرنے ميں كمي بيشى، الٹ پھير، جعل و تخريف كرتے ہيں اور تاريخ كو اپني مرضي كے مطابق جيسا چاہتے ہيں، رنگ ديتے ہيں۔ حتيٰ كہ ان افراد نے بھي جنہوں نے عملاً اخلاقى طور پر جعل اور الٹ پھير سے دامن بچايا ہے، واقعات كو نقل كرنے ميں ”انتخاب“ سے كام ليا ہے، يعني انہوں نے ہميشہ ان چيزوں كو نقل كيا ہے، جو ان كے عقائد اور اہداف سے ہم آہنگ رہي ہے اور ان واقعات كو نقل كرنے سے پرہيز كيا ہے، جو ان كے عقائد اور جذبات كے خلاف رہے ہيں، اس طرح كے لوگوں نے اگرچہ تاريخي واقعات كو نقل كرنے ميں اپني طرف سے كسي چيز كا اضافہ نہيں كيا اور كوئي جعلي بات اس ميں نہيں بڑھائى، ليكن اپني پسند كے واقعات نقل كركے تاريخ كو جيسا چاہا ہے، شكل دے دي ہے۔ ايك حادثہ ايك شخصيت اسي وقت صحيح طور پر قابل تحقيق و تحليل ہے كہ جب اس سے متعلق تمام باتيں محقق كے روبرو ہوں اور اگر بعض چيزيں ہوں اور بعض نہ ہوں اور چھپا دي گئي ہوں، تو پھر حقيقي چہرہ پوشيدہ رہتا ہے اور كوئي دوسري صورت ابھر آتي ہے ۔
يہ بدگمان لوگ نقلي تاريخ كے بارے ميں بالكل اسي طرح سوچتے ہيں، جس طرح بعض بدگمان فقہا مجتہدين نقل احاديث و روايات كے بارے ميں سوچتے ہيں اور اسي كو ”انسداد باب علم“ كہا گيا ہے۔ تاريخ كے بارے ميں بھي ايسي سوچ كے حامل افراد ”انسدادي“ ہيں۔ بعض لوگوں نے تاريخ كے بارے ميں طنزاً كہا ہے:
”تاريخ نام ہے، وقوع پذير نہ ہونے والے واقعات كا جو مورخ موقع سے غير حاضر ہوتا ہے ۔“
ايك صحافي سے اس طنز كو نقل كيا گيا ہے كہ
”حقيقتيں مقدس ہيں، مگر عقيدہ آزاد ہے ۔“
تاہم بعض افراد اس دور تك بدگمان نہيں ہيں، ليكن انہوں نے تاريخ كے بارے ميں شك كے فلسفے كو ترجيح دي ہے ۔
كتاب ”تاريخ كيا ہے؟“ ميں پروفيسر سر جارج كلارك سے نقل كيا گيا ہے كہ:
”گذشتہ دور ميں رونما ہونے والے واقعات ايك يا كئي ذہنوں سے چھنتے چھناتے، ہم تك پہنچتے ہيں، لہٰذا ناقابل تغير، بسيط اور جامد ذرات پر حاوي نہيں ہيں، اس موضوع پر تحقيق لاحاصل رہتي ہے، اسي لئے بعض محققين نے فلسفہ شك ميں پناہ لي ہے اور كچھ نہيں تو اس عقيدے كا سہارہ ليا ہے، چونكہ تمام تاريخي فيصلوں ميں لوگوں كے ذاتي نظريات كا عمل دخل ہے، لہٰذا كسي پر بھروسہ نہيں كيا جا سكتا اور كوئي عيني تاريخي حقيقت موجود نہيں ہے ۔“(۹)
يہ حقيقت ہے كہ آنكھيں بند كر كے موثق راويوں پر بھي اعتبار نہيں كيا جا سكتا، ليكن پہلي بات تو يہ ہے كہ تاريخ، دوسرے علوم ميں بديہات كي طرح كچھ اصول ركھتي ہے اور وہي اصول خود محقق كے تحليل و تجزيہ ميں آسكتے ہيں۔ پھر ثانياً محقق ايك طرح كے اجتہاد كے ساتھ بعض نقول كي صحت اور عدم صحت كي كسوٹي پر پركھ كر ا س سے نتيجہ حاصل كر سكتا ہے۔ آج ہم ديكھتے ہيں كہ بہت سے ايسے مسائل جن كي بعض ادوار ميں بہت دھوم رہي ہے ليكن كئي صدياں گذرنے كے بعد محققين نے ان كے غير معتبر ہونے كو سورج كي طرح روشن كر ديا ہے، اسكندريہ كے كتب خانے كو جلانے كي داستان جو ساتويں صدي كي ہے۔
جي ہاں فقط ساتويں صدي ہجري سے زبان زد خاص و عام ہوئي اور اس طرح پھيلي كہ بدريج اكثر تاريخي كتابوں ميں سرائيت كر گئي ، موجودہ صدي كے محققين كي تحقيق نے يہ ثابت كيا ہے كہ يہ محض ايك بے بنياد افسانہ ہے، جسے خود غرض عيسائيوں نے گڑھ ركھا ہے، جيسے كوئي حقيقت چھپا دي جاتي ہے، ليكن كچھ عرصے كے بعد وہ سامنے آ جاتي ہے، لہٰذا مندرجات تاريخ كے بارے ميں بطور كلي بدگماني نہيں كي جا سكتي ۔
۲۔ تاريخ ميں قانون علت و معلول
كيا تاريخ پر قانون علت حكم فرما ہے؟ اگر علت كي حكومت ہے، تو اس كا لازم يہ ہے كہ ہر واقعہ كي وقوع پذيري اس كي اپني حد تك حتمي اور ناقابل اجتناب رہي ہے اور اس طرح ايك خاص”جبر“ تاريخ پر مسلط ہے اور اگر تاريخ پر جبر كا تسلط ہے ، تو پھر نوع بشر كي آزادى اور اختيار جبري ہے، تو پھر كسي شخص كي كوئي ذمہ داري نہ ہوگي اور كوئي بھي قابل توصيف و تمجيد يا مستحق مذمت و ملامت نہيں ہوگا اور قانون علت كي حكمراني نہيں تو پھر كليت بھي نہيں اور اگر كليت نہيں تو پھر تاريخ قوانين اور ضوابط سے عاري ہے، كيونكہ قانون كليت كا نتيجہ ہے اور كليت قانون علت كا نتيجہ ہے۔يہ وہ پىچيدہ سوال ہے، جو ”علمي تاريخ“ اور ”فلسفہ تاريخ“ كے بارے ميں پايا جاتا ہے، بعض افراد نے قانون علت اور قانون كليت كو مان كر آزادى اور اختيار كاا نكار كيا ہے اور آزادى كے نام پر جو چيز انہوں نے قبول كي ہے، وہ درحقيقت آزادى نہيں ہے، بعض نے اس كے برعكس اصول آزادى كو قبول كر كے تاريخ كي قانون پذيري سے انكار كيا ہے۔ اگر عمرانيات كے ماہرين نے قانون علت اور آزادى كو غير قابل يكجائي جانا ہے اور عليت سے رشتہ جوڑ كر آزادى كي نفي كي ہے۔ ”ہيگل“ اور اس كي پىروي ميں ”ماركس“ جبر تاريخ كے حامي رہے ، ہيگل اور ماركس كي نظر ميں آزادى ضرورت تاريخ سے آگاہي كے سواء كچھ نہيں ۔ ”ماركس اور ماركسزم“ كا مصنف اينجلز كي تاليف شدہ كتاب ”اينٹي ڈيورنگ“ كے حوالے سے لكھتا ہے:
”ہيگل وہ پہلا شخص تھا جس نے آزادى اور ضرورت كے تعلق كي انتہائي واضح طور پر نشان دہي كي ہے۔ اس كي نظر ميں آزادى، ادراك ضرورت كا نام ہے، ضرورت بس اس حد نابينا ہے كہ اس كا ادراك نہ ہو، آزادى، قوانين فطرت كے مقابل كھڑے ہونے ميں نہيں بلكہ ان قوانين كي شناخت اور انہيں معين مقاصد كے لئے بروئے كار لانے ميں ہے۔ يہ امر خارجي طور پر بھي قوانين فطرت پر صادق آتا ہے اور انسان كي روح و جسم پر بھي ۔“
نيز اس كتاب ميں مولف اس موضوع پر ايك مختصر بحث كرتا ہے كہ انسان خاص تاريخي حالات كے تحت اور ان حالات كي معين كردہ سمت ميں اقدام كر سكتا ہے اور اسے كرنا چاہيے۔اس كے بعد لكھتا ہے:
”درحقيقت تاريخ كے ذريعے ہمارے حوالے كي جانے والي چيزوں كي شناخت انسان كے عمل كو زيادہ موثر بناتي ہے، ان چيزوں كے خلاف ہر اقدام تاريخ كے خلاف رد عمل اور اس سے ٹكرانے كے مترادف ہوگا، ان سے ہم آہنگ سمت ميں اقدام، گويا تاريخ كي سمت اور راستے پر حركت كہلائے گى، ليكن يہاں يہ سوال ہوگا كہ آزادى كا كيا بنے گا؟ ماركس كا مكتب فكر اس كا جواب يوں ديتا ہے كہ آزادى عبارت ہو گى، فرد كي ضرورت تاريخ اور اس جماعت كے راستے سے آگاہي كي جس كي سمت اسے كھينچا جا رہا ہے ۔“(۱۰)
ظاہر ہے يہ باتيں مسئلے كو حل نہيں كرتيں، يہاں بات تاريخي حالات كے ساتھ انسان كے رابطہ كي ہے۔ كيا انسان تاريخي شرائط پر حاكم ہے؟ انہيں كوئي اور جہت دے سكتا ہے؟ ان كا رخ بدل سكتا ہے يا نہيں؟ اگر وہ ايسا نہيں كر سكتا اور تاريخ كو كوئي سمت نہيں دے سكتا يا اس كے رخ ميں تبديلي نہيں لا سكتا، تو پھر مجبوراً تاريخ كے دھارے پر لا كر ہي وہ اپنے آپ كو زندہ ركھ سكتا، بلكہ كمال حاصل كر سكتا ہے، وگرنہ اس كے خلاف اپني راہ متعين كرنا موت كو دعوت دينا ہے۔ اب يہ سوال درپيش ہے كہ كيا انسان كو تاريخ كي سمت ميں قرار پانے اور نہ پانے ميں اختيار ہے؟ يعني كيا وہ اس امر ميں آزاد ہے يا مجبور؟ اور كيا فرد پر معاشرے كے تقدم كے قانون كے مطابق اور اس بات كے بعد كہ فرد كے وجدان و شعور و احساس كو مكمل طور پر معاشرہ و تاريخ خاص كر اقتصادي حالات بناتے ہيں، آزادى كے لئے كوئي جگہ باقي رہتي ہے؟
پھر ”آزادى، ضرورت كے بارے ميں آگاہي سے عبارت ہے“ كا كيا مفہوم ہے؟ كيا وہ شخص جو خوفناك سيلاب كا شكار ہے اور اس بات سے آگاہ ہے كہ چند گھنٹوں ميں يہ سيلاب اسے سمندر كي گہرائيوں ميں پہنچا دے گا يا وہ شخص جو كسي بلندي سے گر رہا ہو، اس بات سے واقف ہو كہ قانون كشش ثقل اسے چند لمحوں ميں چور كر دے گا، سمندر كي گہرائيوں ميں جانے يا زمين پر گرنے ميں آزاد ہے؟
تاريخي جبري ماديت كي رو سے، مادي و اجتماعى شرائط انسان كو محدود كر ديتي ہے، اس كے لئے سمت كا تعين كرتي ہيں اور اس كے وجدان، اس كي شخصيت اور اس كے ارادہ انتخاب كو بناتي ہيں اور وہ اجتماعى شرائط كے مقابل ايك خالي برتن اور خام مواد كے سواكچھ نہيں اور انساني شرائط كا ساختہ ہے۔ انسان نے اجتماعى شرائط كو نہيں بنايا پچھلوں كي شرائط بعد ميں انسان كے لئے راستہ معين كرتي ہيں، مستقبل كي شرائط كي معمار نہيں، اس بناء پر آزادى كي صورت كوئي معني و مفہوم نہيں ركھتي۔ حقيقت يہ ہے كہ انساني آزادى، نظريہ فطرت كے بغير قابل تصور نہيں، اس نظريے كے مطابق انسان دنيا كے عمومي جوہري حركت كي راہ ميں دنيا سے ہٹ كر ايك اضافي پہلو كے ساتھ آتا ہے، يہي پہلو اس كي شخصيت كو پہلي بنياد فراہم كرتا ہے۔ اس كے بعد عوامل ماحول كے زير اثراس كي شخصيت كي تكميل اور پرورش ہوتي ہے، يہي وجودي بعد ہے، جو انسان كو انساني شخصيت ديتا ہے اور اس منزل تك لاتا ہے كہ وہ تاريخ پر حكمراني كرنے لگتا ہے اور تاريخ كي راہ كو معين كرتا ہے، ہم اس سے پہلے ”جبر و اختيار“ كے عنوان كے تحت عظيم شخصيات كے كردار كے تذكرے ميں اس موضوع پر مزيد روشني ڈاليں گے ۔
انسان كي آزادى ، جس مفہوم ميں ہم اشارہ كر چكے ہيں، نہ تو قانون عليت سے ٹكراتي ہے اور تاريخي مسائل كي كليت سے اور نہ ہي تاريخ كي قانون پذيري كي منافي ہے۔ يہ بات كہ انسان آزادى و اختيار كے ساتھ اپني فكر اور ارادے كے موجب اجتماعى زندگي ميں ايك معين، مشخص اور غير قابل تغير راہ ركھتا ہو، اس كا معني سوائے اس كے كہ كچھ نہيں كہ انسان اور انسان كے ارادے پر ايك اندھي ضرورت حكم فرما ہو، تاريخ كي قانوني پذيري اور كليت ميں ايك معترض بات يہ بھي ہے كہ تاريخ واقعات و حادثات كے مطالعے سے يہ بات واضح ہوتي ہے كہ كبھي چند جزوي اور حادثاتي واقعات بھي تاريخ كے دھارے كو بدل ديتا ہے، البتہ اتفاقي واقعات سے مراد بعض نا واقف افراد كي سوچ كے برخلاف علت كے بغير رونما ہونے والے واقعات نہيں ہيں، بلكہ وہ واقعات ہيں جو ايك عام اور كلي علت سے رونما نہيں ہوتے اور اس اعتبار سے كلي ضابطے سے عاري ہيں۔ اگر وہ واقعات، جو كلي ضابطے سے عاري ہيں، تاريخ ميں موثر كردار كے حامل ہوں، تو تاريخ كسي قاعدے، قانون اور مشخص روايت سے خالي ہوگي۔ اتفاقي تاريخي واقعات سے متعلق ضرب المثل مصر كي مشہور ملكہ قلو بطرہ كي ناك ہے، جس نے تاريخ كے دھارے كو موڑ ديا۔ ايسے جزوي اور اتفاقي واقعات كي كمي نہيں، جنہوں نے تاريخ كے رخ كو موڑ ديا ہے ۔
”ايڈورڈ ہيلٹ كار“ اپني كتاب ”تاريخ كيا ہے؟ “ ميں لكھتا ہے: ”جبر تاريخ پر حملے كي دوسري بنياد قلوپطرہ كي ناك“ كا مشہور معمہ ہے۔ يہ وہي نظريہ ہے ، جو تاريخ كو كم و بيش اغراض كا ايك باب اور اتفاقي امور سے ابھرنے والے واقعات كي ايك كڑي اور انتہائي اتفاقي علل سے منسوب ايك چيز جانتا ہے ۔
عام طور پر مورخين نے جنگ ايكٹيوم كي طرف جن علل كو مسلم جانتے ہوئے نسبت دي ہے، وہ درست نہيں۔ يہ جنگ انتھوني كي قلوپطرہ سے عشق كا نتيجہ تھى، جب بايزيد گٹھيا كي بيماري كي وجہ سے مركزي يورپ ميں اپني پىش قدمي جاري نہ ركھ سكا ۔
گيبن نے لكھا ہے: ”كسي انسان پر كسي بيماري كا تھوڑا سا حملہ ممكن ہے، كئي قوموں كو تباہي سے بچا لے يا تباہي كو التوا ميں ڈال دے ۔“ جس وقت ۱۹۲۰ء كے موسم خزاں ميں يونان كے بادشاہ اليگزينڈر كو ايك تربيت يافتہ بندر نے كاٹ ليا اور اس كي موت كا سبب بنا، تو اس حادثے نے ايسے واقعات كو جنم ديا كہ سر وينسٹن چرچل كو كہنا پڑا كہ ”۲۵۰۰ افراد بندر كے كاٹنے سے مر گئے ۔“ ياٹرو ئسكي ۱۹۲۳ء كے موسم خزاں ميں مرغابيوں كا شكار كرتے ہوئے بخار كے عارضے ميں مبتلا ہوگيا اور ايسے موقع پر جب اس كي جنگ زينوف كا منف اور اسٹالن سے ۱۹۳۳ء كے موسم خزاں ميں جاري تھى، وہ بستر پر گر پڑا ۔وہ لكھتا ہے:
”انسان كسي جنگ يا انقلاب كي پىشنگوئي تو كر سكتا ہے، ليكن موسم خزاں ميں مرغابيوں كے شكار كے نتائج كي پىشگوئي نا ممكن ہے ۔“(۱۱)
عالم اسلام ميں آخري اموي خليفہ مروان بن محمد كي شكست اس امر كي ايك عمدہ مثال ہے كہ اتفاق كو تاريخ كي سرنوشت دخل حاصل ہے، عباسيوں كے ساتھ اپني آخري جنگ كے دوران ميں سخت پىشاب آ گيا، لہٰذا وہ ايك طرف چلا گيا اتفاق سے وہاں دشمن كا ايك آدمي جا رہا تھا، اس كي نظر پڑي اور اس نے اسے قتل كر ديا۔ اس كے قتل كي خبر فوج ميں پھيل گئي چونكہ اس حادثے كے بارے ميں پہلے سے سوچا نہ گيا تھا، فوج كا جذبہ سرد پڑ گيا اور وہ بھاگ كھڑي ہوئي۔ يوں بني اميہ كي حكومت ختم ہوگئى، لہٰذا كہا گيا:
ذهبت الدولة ببولة
ايڈورڈ ہيلٹ كار اس امر كي توضيح كے بعد كہ حادثہ علت و معلول كے ايك رشتے سے منسلك ہوتا ہے، جو علت و معلول كے ايك اور رشتے كو قطع كر ديتا ہے نہ يہ كہ ايسا كوئي حادثہ ہوتا ہے ، جو بے علت ہو، لكھتا ہے:
”آخر كس طرح ہم علت و معلول كے منطقي تواتر كو تاريخ ميں دريافت كر سكتے ہيں اور اسے تاريخ كا مبنيٰ قرار دے سكتے ہيں، جب كہ ہمارا تواتر ہر آن ممكن ہے-، كسي دوسرے تواتر كے ذريعے جو ہماري نگاہ ميں غير مربوط ہو، منقطع ہوتا رہے يا كسي اور ڈگر پر چل پڑے ۔“(۱۲)
اس اشكال كے جواب كا تعلق معاشرے اور تاريخ كے لئے ايك معين رنگ والي طبيعت كے ہونے اور نہ ہونے سے ہے، اگر تاريخ معين راہ ركھنے والي طبيعت سے ہمكنار ہے، تو جزوي واقعات كا كردار ناچيز ہو جائيگا، يعني جزوي واقعات اگرچہ مہروں ميں تبديلي پىدا كرتے ہيں ، ليكن كل تاريخ كي راہ ميں ان كا كوئي اثر نہيں ہوتا، زيادہ سے زيادہ يہ ہوگا كہ اس سفر ميں تيزي يا كندي آجائيگى، ليكن اگر تاريخ طبيعت، حيثيت اور اس معين شدہ راہ سے عاري ہوگئى، جس سے طبيعت اور الگ حيثيت اس كے لئے مقرر كرے گى، تو لازماً تاريخ كي كوئي معين اور مشخص راہ نہيں ہوگي اور پہلے سے اس كے بارے ميں كچھ نہيں كہا جا سكتا اور وہ كليت سے عاري ہوگي ۔
تاريخ كے بارے ميں ہمارا نكتہ نظر يہ ہے كہ تاريخ طبيعت اور حيثيت كي حامل ہے اور يہ طبيعت اور حيثيت اسے ان انسانوں سے ملتي ہے، جو فطرتاً كمال كي تلاش ميں ہوتے ہيں۔ اتفاقي طور پر رونما ہونے والے واقعات تاريخ كي كليت اور ضرورت كو نقصان نہيں پہنچاتے۔ مونٹيسكو نے اتفاق كے بارے ميں بڑي خوبصورت بات كہي ہے اور اس كے كچھ حصے كو ہم پہلے بيان كر چكے ہيں۔ وہ كہتا ہے:
”اگر اتفاقي طور پر يعني ايك خاص علت كے سبب كسي حكومت كا تختہ الٹ جائے، تو يقينا اس ميں كسي كلي سبب كا ہاتھ ہوتا ہے جس كي وجہ سے يہ حكومت ايك جنگ ميں گھٹنے ٹيك بيٹھتي ہے ۔“
وہي كہتا ہے: ”بولٹاوا كي جنگ جو سويڈن كے بادشاہ باروہويں چارلس كے زوال كا سبب ہوئى، اگر نہ ہوتي اور وہ بولٹاوا ميں شكست نہ كھاتا تو كسي اور مقام پر شكست كھا ليتا، اتفاقي واقعات كي تلافي آسان ہو جاتى، ليكن جو واقعات چيزوں كي فطرت سے دائماً جنم ليتے رہتے ہيں ان سے محفوظ رہا جا سكتا ہے ۔“(۱۳)
۳۔ كيا تاريخ كي فطرت مادي ہے؟
تاريخ كس فطرت كي حامل ہے؟ اس كي اصل فطرت ثقافتي ہے يا سياسى ہے؟ اقتصادي ہے، مذہبى ہے يا اخلاقى ہے؟ اس كے مزاج ميں ماديت ہے يا روحانيت؟ يا پھر مخلوط ہے؟ پہلا سوال تاريخ سے متعلق اہم ترين مسائل ميں سے ہے۔ جب تك يہ مسئلہ حل نہيں ہوگا، تاريخ كے بارے ميں ہماري شناخت صحيح نہيں ہوگي۔ ظاہر ہے كہ مذكورہ تمام مادي اور روحاني عوامل تاريخ كے بننے اور اس كي تشكيل ميں موثر رہے ہيں اور اب بھي ہيں، ليكن يہاں تقدم، اصالت اور تعين كنندہ ہونے سے متعلق گفتگو ہے۔ يہاں ہميں يہ ديكھنا ہے كہ ان عوامل ميں سے كونسا عامل تاريخ كي اصلي روح اور اس كي اصل ہويت ہے؟ كون سا عامل باقي تمام عوامل كي توجيہ و تفسير كرتا ہے؟ ان ميں سے كونسا عامل بنياد ہے اور باقي عوامل عمارت؟ عام طور پر اہل نظر تاريخ كو كئي انجنوں والي گاڑي سمجھتے ہيں، جس ميں ہر انجن دوسرے انجن كي نسبت اپني جگہ اپني الگ حيثيت ركھتا ہے۔ يہ لوگ تاريخ كو صرف ايك فطرت والي نہيں سمجھتے بلكہ اسے كئي فطرتوں والي جانتے ہيں، ليكن اگر ہم تاريخ كوكئي انجنوں والي گاڑي اور كئي فطرتوں والي شے جانيں تو پھر تاريخ كے تكامل اور كمال كي طرف ا كے سفر كا مفہوم كياہو گا؟ يہ بات ممكن ہي نہيں كہ متعدد انجن چل رہے ہوں، جو كاركردگي ميں ايك دوسرے ميں الگ ہوں اور تاريخ كو اپنے اپنے دھارے پر پہنچانا چاہتے ہيں، تاريخ پر حكم فرما ہوں اور تاريخ كسي مشخص كمال كے راستے ميں آگے بڑھ سكے۔ مگر يہ كہ مذكورہ عوامل كو تاريخ كي جبلي قوتوں كا درجہ ديا جائے اور ان تمام پر مافوق، تاريخ كي ايك روح ماني جائے، جو تاريخ كي گوناگوں جبلي طاقتوں سے فائدہ اٹھا كر كسي معين راہ كمال پر پہنچاتي ہو۔ يہي وہ روح ہے جو تاريخ كي حقيقي ہويت ہے، ليكن يہ تعبير تاريخ كي ايك طبيعت كي بات سے مختلف ہے۔ تاريخ كي جبلي طاقتوں سے مراد كچھ اور ہے اور طبيعت تاريخ سے كچھ اور، كيوں كہ طبيعت تاريخ وہي ہے، جسے روح تاريخ سے تعبير كيا گيا ہے۔ ہمارے اس دور ميں ايك نظريہ يہ ابھرا ہے، جس نے اپنے بہت سے حامي پىدا كر لئے ہيں اور وہ تاريخي ميٹر يالزم يا تاريخي ”ڈائلكٹك ميٹريالزم“ كے نام سے مشہور ہے ۔ تاريخي ميٹريالزم يعني تاريخ كو معاشي نقطہ نظر سے ديكھنا، بعبارت ديگر تاريخي ماديت يعني يہ كہ تاريخ ايك مادي ماہيت اور جدلياتي وجود كي حامل ہے۔ مادي ماہيت ركھنے كا مطلب يہ ہے كہ كسي بھي معاشرے كي تمام تحريكيں شعبے اور مظاہر اس كي اقتصادي تنظيم كا حصہ ہيں، يعني اس معاشرے كي پىداوار كي مادي قوتيں اس كے پىداواري روابط كي كيفيت ہيں جو اخلاق، علم، فلسفہ، مذہب، قانون اور ثقافت وغيرہ سے متعلق معاشرے كي تمام روحاني حقيقتوں كي تشكيل كرتے ہيں، انہيں سمت ديتے ہيں اور جب بدل جاتے ہيں توانہيں بھي بدل ديتے ہيں ۔
ليكن يہ جو كہا جاتا ہے كہ تاريخ ايك جدلياتي وجود كي حامل ہے، جدلياتي اس مفہوم ميں ہے كہ تاريخ كي تكاملي حركات دراصل جدلياتي حركات ہيں، يعني وہ ايك ايسے جدلياتي تضادات كا محلول اور نتيجہ ہے جو ايك دوسرے سے خاص نوعيت كا رشتہ ركھتے ہيں، غير جدلياتي تضادات سے جدلياتي تضادات كا فرق يہ ہے كہ ہر مظہر اور واقعہ جبري طور پر اپني نفي اور انكار كو اپنے وجود ميں پرورش ديتا ہے اور ان مختلف تبديليوں كے بعد جو داخلي تضاد كے نتيجے ميں پىدا ہوتي ہيں، وہ مظہر ايك شديد كيفي تغير كے بعد پہلے دو مرحلوں كي نسبت زيادہ بلند مرحلے ميں تكامل پاتا ہے ۔
پس تاريخي ميٹريالزم ميں دو مسئلے شامل ہيں، ايك ہويت تاريخ كا مادي ہونا اور دوسرا اس كي حركات كا جدلياتي ہونا۔ ہماري گفتگو يہاں پہلے مسئلے كے بارے ميں ہوگى، دوسرا مسئلہ اس باب ميں زير بحث آئے گا، جہاں ہم تاريخ كے تحول و تكامل كے بارے ميں گفتگو كريں گے۔ ”ہويت تاريخ كي ماديت“ كا نظريہ ايك اور سلسلہ اصول سے وابستہ ہے، جو فلسفے، نفسيات يا عمرانيات كا پہلو لئے ہوئے ہے اور خود اپنے مقام سے آئيڈيالوجى سے متعلق نظريات اخذ كرتا ہے، بعض روشن فكر مسلمان اہل قلم اس بات كے مدعي ہيں كہ اسلام نے ہرچند فلسفي ماديت كو تسليم نہيں كيا ہے، ليكن تاريخي ماديت اس كے لئے قابل قبول ہے اور اسلام نے تاريخي اور معاشرتي نظريات كو اسي بنياد پر قائم كيا ہوا ہے، لہٰذا ہم ضروري سمجھتے ہيں كہ ذرا تفصيل سے اس پر گفتگو كي جائے لہٰذا جس اصول پر يہ نظريہ قائم ہے، ہم اس كے بارے ميں اپني معروضات پىش كرتے ہوئے اس كے ”نتائج“ پر بھي گفتگو كريں گے اور اس كے بعد اصل نظريہ كو سائنسي اور اسلامي نقطہ نظر سے تحقيق و تنقيد كي منزل پر لائيں گے ۔
ماديت تاريخ كے نظريہ كي بنياد
۱۔ روح پر مادہ كا تقدم
انسان جسم بھي ركھتا ہے اور روح بھي۔ جسم، علم حياتيات اور علم طب كا موضوع كا مطالعہ ہے ليكن روح اور اس سے متعلق امور فلسفے اور نفسيات كا موضوع ہيں، افكار، ايمان، احساسات ، ميلانات، نظريات اور آئيڈيالوجى نفسياتي امور كا حصہ ہيں۔ روح پر مادے كي تقدم كے اصول كي كوئي اساس نہيں بلكہ يہ صرف وہ عادي انعكاسات ہيں، جو مادہ عيني سے اعصاب اور دماغ پر وارد ہوتے ہيں۔ ان امور كي حيثيت صرف اس حد تك ہے كہ يہ باطني مادي قوتوں اور بيروني دنيا ميں رابطہ پىدا كرتے ہيں، ليكن خود يہ امور انسان كے وجود پر حاكم مادي طاقتوں كے مقابل طاقت شمار نہيں ہوتے، مثال كے طور پر نفسياتي امور كو، گاڑي كي لائٹس سے تشبيہ دي جا سكتي ہے، گاڑي رات كو لائٹس كے بغير نہيں چل سكتى، وہ لائٹس كي روشني ميں اپنا راستہ طے كرتي ہے، ليكن گاڑي كو چلانے والي شے لائٹس نہيں انجن ہے۔ نفسيات اور روح سے متعلق امور يعني افكار، ايمان، نظريات اور آئيڈيالوجى اگر تاريخ كي مادي طاقتوں كے رخ پر كام آئيں تو وہ تاريخ كي حركت ميں معاون ثابت ہوں گے، ليكن وہ خود ہرگز كسي حركت كو وجود ميں نہيں لا سكتے اور ہرگز مادي طاقتوں كے مقابل طاقت نہيں بن سكتے، نفسياتي اور روحاني امور بنيادي طور پر كوئي طاقت نہيں ہيں، نہ يہ كہ طاقت نہيں بلكہ ان كي حقيقت مادي ہے، انساني وجود كي حقيقي طاقتيں بن رہي ہيں، جو مادي طاقتوں كے عنوان سے جاني جاتي ہيں اور جنہيں مادي ترازو كے ذريعے تو لا سكتا ہے۔
اس اعتبار سے نفسيات پر مبني امور، حركت بخش اور جہت بخش ہونے كي صلاحيت نہيں ركھتے اور معاشرے كو آگے بڑھانے كے لئے اہرم ( Lever ) شمار نہيں ہوتے، نفسياتي تدريس اگر مطلقاً مادي اقدار پر منحصر اور ان كي توجيہ كرنے والي نہ ہوں تو كسي طرح بھي ايك اجتماعى حركت ان سے ظہور ميں نہيں آسكتي۔ اس بناء پر تفسير تاريخ ميں بڑي احتياط كي ضرورت ہے۔ ہميں ظاہري فريب ميں نہيں آنا چاہيے، اگر تاريخ كے كسي حصے ميں بظاہر يہ ديكھنے ميں آئے كہ كسي فكر، كسي عقيدے اور كسي ايمان نے كسي معاشرے كو آگے بڑھايا ہے اور اسے رشد و كمال كي طرح حركت دي ہے، اگر اچھي طرح تاريخ كا پوسٹ مارٹم كيا جاے تو معلوم ہوگا كہ ان عقائد كي كوئي بنيادي حيثيت نہيں ہے اور جو مادي طاقتيں ہيں، جنہوں نے معاشرے كو آگے كي سمت حركت دي ہے، يہ امور تو انہي مادي طاقتوں كا انعكاس ہيں، يہي طاقتيں ايمان كي شكل ميں تحريك بن كر ابھري ہيں۔ تاريخ كو آگے بڑھانے والي مادي طاقت فني نقطہ نظر سے معاشرے كا پىداواري نظام اور انساني نقطہ نظر سے معاشرے كا محروم اور لوٹ كھسوٹ كا شكار ہونے والا طبقہ ہے۔ مشہور مادي فلسفي ”فوئر باخ“ (Feuer Bagh) ) (جرمن فلسفي) جس كے بہت سے مادي نظريات سے ماركس نے استفادہ كيا ہے، لكھتا ہے: ”نظريہ كيا ہے؟ “، ”پراكسز (فلسفہ عمل اجتماعى) كيا ہے؟ “ ان دونوں كے درميان كس بات كا فرق ہے؟ اور پھر بات كا جواب اس طرح ديتا ہے:
”ہر وہ چيز جو ميرے ذہن تك محدود ہے، نظري ہے اور جو بہت سے اذہان ميں ابھرتي ہے، عملي ہے، وہ جو بہت سے اذہان كو آپس ميں متحد كرتي ہے، ايك گروہ كي تشكيل كرتي ہے اور اس طرح دنيا ميں اپنے لئے ايك مقام پىدا كرتي ہے ۔“(۱۴)
اس كا وفا دار شاگرد ماركس لكھتا ہے:
”ظاہر ہے كہ تنقيد كا اسلحہ، اسلحے پر تنقيد كي جگہ نہيں لے سكتا، مادي طاقت كو مادي طاقت سے ہي نيچا دكھايا جا سكتا ہے ۔“
ماركس غير مادي طاقتوں كي اصالت كا قائل نہ ہونے كي وجہ سے ان كي توضيحي اہميت (اس سے زيادہ نہيں) پر بات كرتے ہوئے كہتا ہے:
”ليكن نظريہ بھي يونہي عوام ميں رسوخ پىدا كر ليتا ہے، مادي طاقت ميں بدل جاتا ہے ۔“
روح پر مادہ كے تفدم، نفس پر جسم كے تقدم اور روحاني اور معنوي اقدار اور طاقتوں كي اصالت كا نہ ہونا دراصل فلسفي ماديت كے بنيادي اصول ہيں ۔
اس نظريے كے مقابل نظريہ اصالت روح ہے، اس كے مطابق انساني وجود كے تمام بنيادي پہلوؤں كي مادہ اور اس سے متعلق امور كے حوالے سے توجيہ و تفسير نہيں كي جا سكتى، روح انسان كے مركز وجود ميں ايك بنيادي حقيقت ہے، روحاني توانائي مادي توانائيوں سے بالكل جدا چيز ہے۔ اس اعتبار سے روحاني طاقتيں يعني فكرى، اعتقادى، ايماني اور جذبوں كي طاقتيں بعض اعمال كے لئے ايك جداگانہ حيثيت ركھتي ہيں۔ يہ اعمال انفرادي بھي ہو سكتے ہيں، اجتماعى بھي۔ان قوموں سے تاريخ كو آگے بڑھايا جا سكتا ہے، بہت سے تاريخي واقعات و حركات جداگانہ طور پر ان قوتوں كے مرہون منت ہوتے ہيں، خاص طور پر انسان كے انفرادي اور اجتماعى بلند پايہ كاموں كي براہ راست ان طاقتوں سے وابستگي ہے، ان كاموں نے انہيں طاقتوں سے بلندي حاصل كي ہے ۔
نفس كي قوتيں كبھي كبھي بدن كي مادي طاقتوں كو نہ صرف اختياري فعاليتوں كي حد ہيں بلكہ ميكانياتى، كيميائي اور حياتياتي كاموں كي سطح پر بھي شديد متاثر كرتي ہيں اور اپني خاص سمت ميں ان سے كام ليتي ہيں ۔جسماني بيماريوں كے علاج كے لئے نفسياتي طريقہ علاج اور ہپناٹزم كے غير معمولي اثرات ايسي چيزيں ہيں، جن كا انكار نہيں كيا جا سكتا۔ (ايسے مسائل كے بارے ميں زيادہ آگاہي كيلئے ہم كاظم زادہ ايرانشہري كي كتاب ”تداوي روحي“ كے مطالعے كي تلقين كرتے ہيں) علم اور ايمان اور خصوصاً ايمان، خاص طور پر وہاں جہاں نفس كي يہ دونوں قوتيں ہم آہنگ ہوں، ايك عظيم اور كارآمد طاقت بن جاتي ہيں اور تاريخ ميں زيرو زبر كر دينے والي اور ارتقاء بخش تحريك پىدا كر سكتي ہيں۔ روح اور روحاني طاقتوں كي اصالت”فلسفي ريلزم“ ( Philosophical Realism ) كے اركان ميں سے ہے ۔(۱۵)
۲۔ معنوي ضرورتوں پر مادي ضرورتوں كا تقدم
انسان كو كم از كم اپنے اجتماعى وجود ميں دو طرح كي ضرورتيں درپيش ہيں: ايك روٹى، پانى، مكان، كپڑا اور دوا جيسي ضرورتيں اور دوسري تعليم، ادب، آرٹ، فلسفي افكار، ايمان، آئيڈيالوجى، دعا، اخلاق اور ان جيسي روحاني چيزيں۔ يہ دونوں ضرورتين بہرحال اور بہر سبب انسان ميں موجود ہيں۔ ليكن يہاں گفتگو ان ضرورتوں كے تقدم اور اوليت كے بارے ميں ہے كہ كون سي ضرورت دوسري پر مقدم ہے۔ مادي ضرورتيں روحاني ضرورتوں پر مقدم ہيں، يا برعكس ہے يا پھر كوئي تقدم نہيں ركھتيں۔ مادي ضرورتوں كے تقدم سے متعلق نظريہ يہ ہے كہ مادي ضرورتوں كو تقدم اور اوليت حاصل ہے اور يہ اوليت اور تقدم صرف اس جہت سے نہيں كہ انسان سب سے پہلے مادي ضرورتوں كو پورا كرنے كے درپے ہوتا ہے اور جب يہ پوري ہوجاتي ہيں، تو پھر معنوي ضرورتوں كا سرچشمہ ہيں ايسا نہيں ہے كہ انسان اپني خلقت ميں دو طرح كي ضرورتوں اور دو طرح كي جبلتوں كے ساتھ آيا ہو، مادي ضرورت و جبلت اور معنوي ضرورت و جبلت، بلكہ انسان ايك طرح كي ضرورت اور ايك طرح كي جبلت كے ساتھ پىدا ہوا ہے اور اس كي معنوي ضرورتيں ثانوي حيثيت كي حامل ہيں اور درحقيقت يہ مادي ضرورتوں كو بہتر طور پر پورا كرنے كے لئے ايك وسيلہ ہيں، يہي وجہ ہے كہ روحاني ضرورتيں شكل، كيفيت اور ماہيت كے اعتبار سے بھي مادي ضرورتوں كے تابع ہيں۔ انسان ہر دور ميں آلات پىداوار ميں نشوونما كے تناسب سے مختلف شكل و رنگ اور كيفيت كي مادي ضرورتيں ركھتا ہے اور چونكہ اس كي معنوي ضرورتيں اس كي مادي ضرورتوں سے ابھرتي ہيں، لہٰذا وہ بھي شكل و صورت اور كيفيت و خصوصيت كے اعتبار سے مادي ضرورتوں سے مناسبت ركھتي ہيں۔ پس در حقيقت مادي ضرورتوں اور معنوي ضرورتوں ميں دو طرح كي ترجيحات موجود ہيں، ايك وجود سے متعلق ترجيحات، يعني روحاني ضروريات مادي ضروريات كي پىداوار ہيں اور دوسري ہويت سے متعلق ترجيح۔ جس ميں روحاني ضرورتوں كي شكل و صورت اور خصوصيت و كيفيت مادي ضرورتوں كي شكل و صورت، كيفيت و خصوصيت كے تابع ہيں۔ پى۔ رويان ”ميٹريالزم تاريخى“ ميں ”ہايمن لوئي“ كي كتاب ”فلسفي افكار“ كے صفحہ(۹۲)كے حوالے سے لكھتا ہے:
”انسان كي مادي زندگي نے اسے اس بات پر ابھارا كہ وہ اپنے زمانے كي مادي ضروريات كو پورا كرنے كے لئے وسائل كے مطابق نظريات بيان كرے۔ يہ نظريات جو تصور كائنات، معاشرے، آرٹ، اخلاق اور ديگر روحاني پہلوؤں كے بارے ميں ہيں كہ جو اسي مادي راستے اور پىداوار سے پىدا ہوئے ہيں ۔“(۱۶)
اس اعتبار سے ہر شخص كے علمي تضادات، اس كي فلسفيانہ سوچ، اس كا ذوق، حس جماليات، فنون لطيفہ كا ذوق، اخلاقى ميزان اور مذہبى رجحان اس كي طرز معاش كے تابع ہے۔ اسي لئے جب قانون كسي فرد كے بارے ميں لايا جائے گا، تو اس كي ادائيگي كي صورت يہ ہوگي ۔
”بتاؤ وہ كيا كھاتا ہے؟ تاكہ ميں بتا سكوں كہ وہ كيا سوچتا ہے؟ “ اور اگر اسے معاشرے كي سطح پر استعمال كيا جائے تو جملہ يہ ہوگا ”مجھے بتاؤ كہ پىداواري آلات ميں بہتري كس درجے پر ہے اور يہ بھي كہ معاشرے ميں افراد كے مابين كس طرح كے اقتصادي روابط كار فرما ہيں تاكہ ميں يہ بتا سكوں كہ اس معاشرے ميں كس طرح كي آئيڈيالوجى، كس طرح كا فلسفہ، كس طرح كا اخلاق اور كيسا مذہب پايا جاتا ہے؟ “
اس كے مد مقابل روحاني ضرورتوں كي اصالت پر مبني نظريہ ہے۔ اس نظريے كے مطابق ہر چند انسان ميں مادي ضرورتيں وقت كے اعتبار سے جلدي جوان اور نماياں ہوجاتي ہيں اور اپنے آپ كو جلد ظاہر كرتي ہيں، جيسا كہ چھوٹے بچے كے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، پىدا ہوتے ہي اسے دودھ اور ماں كي چھاتي كي تلاش ہوتي ہے، ليكن انسان كي سرشت ميں چھپي ہوئي معنوي ضرورتيں بتدريج اس ميں پھوٹنے لگتي ہيں اور رشد و كمال كي ايك ايسي منزل آتي ہے، جب وہ اپني مادي ضرورتوں كو روحاني ضرورتوں پر قربان كر ديتا ہے۔ بہ تعبير ديگر:معنوي لذتيں انسان ميں مادي لذتوں اور مادي كششوں كي نسبت بنيادي بھي ہيں اور زيادہ طاقتور بھي (ارشادات كے باب ہشتم ميں بو علي نے اس مسئلے پر نہايت عمدہ بحث كي ہے)۔ آدمي جس قدر تعليم و تربيت حاصل كرے گا، اس كي معنوي ضرورتيں، معنوي لذتيں يہاں تك كہ اس كي تمام حيات معنوي اسي قدر مادي ضرورتوں، مادي لذتوں اور مادي حيات كو اپنے زير اثر لے آئے گى، معاشرے كا بھي يہي حال ہے كہ ابتدائي معاشروں ميں معنوي ضرورتوں سے زيادہ مادي ضرورتوں كي حكمراني ہوتي ہے، ليكن جس قدر معاشرہ كمال كي منزليں طے كرتا ہے، اسي قدر اس كي معنوي ضرورتيں قابل قدر بنتي جاتي ہيں اور انہيں تقدم حاصل ہوتا جاتا ہے اور وہ انساني مقصد كي صورت اختيار كر ليتي ہيں اور مادي ضرورتوں كو ثانوي حيثيت دے كر انہيں ايك وسيلے كے مقام تك نيچے لے آتي ہيں ۔(۱۷)
۳۔ فكر پر كام كے تقدم كا اصول
انسان ايك وجود ہے، جو فكر كرتا ہے، پہچانتا ہے اور كام كرتا ہے، تو پھر كام كو تقدم حاصل ہے يا فكر كو؟ انسان كا شرف اس كے كام ميں ہے يا فكر ميں؟ انسان كا جوہر اس كا كام ہے يا فكر؟ انسان كام كا نتيجہ ہے يا فكر كا؟
ماديت تاريخ، فكر پر كام كے تقدم اور اس كي اصالت كي قائل ہے۔ وہ كام كو اصل اور فكر كو فرع اور شاخ شمار كرتي ہے۔ منطق اور قديم فلسفہ، فكر كو كليد جانتا ہے۔ اس منطق ميں فكر، تصور اور تصديق ميں تقسيم ہوتي تھي۔ پھر يہ دونوں بديہي اور نظري ميں منقسم ہوتي تھيں اور پھر بديہي افكار نظري افكار كي كليد سمجھے جاتے تھے، اس منطق اور فلسفے ميں جوہر انسان ميں محض فكر كو سمجھا جاتا تھا، انسان كا كمال اور اس كا شرف اس كے علم ميں بتايا جاتا تھا۔ ايك كامل انسان ايك عالم انسان كے مساوي تھا۔ (فلسفے كي تعريف ميں ہدف و غايت كے پہلو سے كہا جاتا ہے: ”صيرورة الانسان عالما عقليا و مضاهيا للعالم العيني “ يعني ”فلسفي اس سے عبارت ہے كہ انسان عالم فكر بن جائے عالم عيني كي طرح “)
ليكن تاريخ ماديت اس بنياد پر استوار ہے كہ كام، فكر كي كليد اور فكر كا معيار ہے، انسان كا جوہر اس كا پىداواري كام ہے۔ كام انسان كي شناخت كا سبب بھي ہے اور اسے بنانے والا بھي۔ ماركس كہتا ہے:
”پوري تاريخ عالم سوائے اس كے كچھ نہيں كہ انسان كي خلقت انساني كام كے ذريعے سے ہے ۔“(۱۸)
اينجلز كہتا ہے:
”خود انسان بھي كام كي پىداوار ہے ۔“(۱۹)
كيونكہ وہ ابتداء ہي سے بجائے اس كے كہ طبيعي ناہمواريوں كو دور كرنے كے لئے فكر سے كام ليتا، اس نے اپنے پر مشقت كام كے ذريعے اپنے بيروني ماحول پر غلبہ پاليا اور اسي انقلابى عمل كے ذريعے و رجارحين كا مقابلہ كيا ۔
اپني مرضي كے معاشرے كو آگے بڑھايا اور اس كي تعمير كي ۔ ”ماركس اور ماركسزم“ كا مولف لكھتا ہے:
”ايسي صورت ميں جب فلسفہ ہستي ميں يہ معمول تھا كہ پہلے فكر و اصول پىش ہوں اور پھر ان كي روشني ميں عملي نتائج برآمد ہوں پر اكسز (فلسفہ عمل كے موجد) نے عمل كو فكر كي اساس قرار ديا (فلسفہ ہستي وہ فلسفہ ہے۔ جو دنيا كو ”ہونے“ كي اساس پر تفسير كرتا ہے، اس كے مقابل پر ”ہو چكنے“ كا فلسفہ ہے۔ ماركسزم اسي سے تعلق ركھتا ہے)۔“
پروكسز طاقت كو عقيدے كي جگہ سمجھتا ہے اور ہيگل سے ہم آواز ہو كر اس عقيدے كو پىش كرتا ہے كہ ”انسان كي حقيقي ہستي پہلے مرحلے پر اس كا عمل ہے“ اور اپنے اس عقيدے ميں جرمنى كے ايك نہايت صاف دل فلسفي كے ساتھ بھي شامل ہوجاتا ہے اور اس كے مشہور جملے كو الٹ كر ديتا ہے كہ ”سب سے پہلے فعل تھا“ يعني روح تھي اور كلام سے يہي ظاہر ہوتا ہے، اس فلسفے نے اسے يوں بنا ديا ہے:پہلے عمل تھا(۲۰) كہ يہ ماركسزم كا ايك اصول ماہيت ہے، اس ميں ماركسزم كے اصول كو ”پراكسز“ كے نام سے شہرت حاصل ہے اور ماركس نے اسے پہلے استاد ماديت ”فوئر باخ“ اور اپنے دوسرے پىشوا ہيگل سے ليا ہے، اس اصول كے مقابل قرار پانے والا اصول فلسفہ ريلزم ہے، جو كام اور فكر كي ايك دوسرے پر تاثير اور فكر كے كام پر تقدم كا قائل ہے۔ اس فلسفے كے مطابق انسان كا جوہر اس كي فكر ہے (نفس كا اپني ذات سے متعلق جوہري حضوري علم) انسان كام كے ذريعے يعني بيروني دنيا سے ارتباط كے ذريعے اپني معلومات كے لئے مواد فراہم كرتا ہے۔ جب تك ذہن اس پہلے مواد كي مدد سے غنى ہوجائے معرفت سے متعلق باتوں پر ”تعميم“، ”انتزاع“ اور استدلال ( Generalization,Abstraction & Argumentation ) كا عمل انجام ديتا ہے اور صحيح معرفت و شناخت كي راہ فراہم كرتا ہے۔ شناخت صرف ذہن ميں عيني مادے كا سادہ انعكاس نہيں بلكہ ذہن ميں اس عيني مادے كا انعكاس كے بعد روح كے غير مادي جوہر سے ابھرنے والے ذہني اعمال كے لئے معرفت كا ايك وسيلہ پىدا ہوتا ہے۔ پس كام فكر سے اور اسي حال ميں فكر كام سے جنم ليتي ہے۔ كام معيار فكر اور اسي طرح فكر معيار كار ہے اور يہ دور (”دور“ ايك فلسفي اصطلاح ہے۔ اس كي سادہ سي مثال يہ ہو سكتي ہے كہ كوئي كہے كہ انڈے نے مرغي كو اور مرغي نے انڈے كو جنم ديا ہے، تو ہم كہيں گے كہ اس طرح تو ”دور“ لازم آتا ہے، مترجم) دور محال نہيں انسان كي بزرگي اس كے علم، اس كے ايمان، اس كي عزت نفس اور كرامت نفس سے ہے اور كام اس اعتبار سے باوقار ہے كہ اس كے ذريعے يہ بزرگي اور عزت حاصل ہوتي ہے۔ انسان كام كا خالق بھي ہے اور اس كا بنايا ہوا بھي اور يہ انسان كا ايك خاص امتياز ہے كہ جس ميں اور كوئي اس كا شريك نہيں اور يہ شرف اسے اللہ تعاليٰ كي طرف سے خاص قسم كي خلقت حاصل ہونے كي وجہ سے ہے۔(ہم نے ”مسئلہ شناخت“ كے بارے ميں اپني كتاب ميں اس بارے ميں تفصيل سے گفتگو كي ہے) ليكن كام سے متعلق انسان كي تخليق ايك ايجادي اور ايجادي تخليق ہے، جب كہ كام سے انسان كي تخليق ”اعدادي“ ہے يعني انسان حقيقتاً اپنے كام كو خلق كرتا ہے، ليكن كام واقعاً انسان كو خلق نہيں كرتا، بلكہ كام، تكرار عمل اور تجربہ انسان كي تخليق كے لئے اندروني طور پر راہ ہموار كرتا ہے اور جہاں دو اشياء كا باہمي رابطہ ايسا ہو، جہاں ايك طرف ”ايجابي“ اور ”ايجادي“ ہو اور دوسري طرف ”اعدادي“ اور ”امكاني“ تو ہميشہ ”ايجابي“ اور ”ايجادي“ كو تقدم حاصل ہوگا۔
پس وہ انسان جس كا جوہر ذات ايك طرح كي آگاہي ہے (نفس كا اپني ذات كے بارے ميں حضوري علم)، كام جس كے ساتھ اس كا رابطہ مدمقابل كا اور فريقي ہے اور انسان كام كو خلق كرنے والا اور اسے وجود ميں لانے والا ہے اور يہ كام انسان كو وجود ميں لانے والا ہے، اس اعتبار سے كہ انسان كام كي ايجابي علت اور كام انسان كي اعدادي اور امكاني علت ہے، پس انسان كام پر تقدم ركھتا ہے، كام انسان پر نہيں ۔
۴۔ انسان كے انفرادي وجود پر اس كے اجتماعى وجود كا تقدم
بعبارت ديگر انسان كي نفسيات پر اس كي عمرانيات كا تقدم۔ انسان تمام جاندار مخلوقات ميں حياتيات كے لحاظ سے زيادہ كامل مخلوق ہے۔ وہ تكامل كي نوع كے لحاظ سے استعداد كا حامل ہے، جسے انساني تكامل كہا جاتا ہے۔ انسان ايك خاص شخصيت كا حامل ہے، جس سے اس كے وجود كے انساني تكامل كہا جاتا ہے۔ انسان ايك خاص شخصيت كا حامل ہے، جس سے اس كے وجود كے انساني پہلو تشكيل پاتے ہيں۔ وہ بعض تجربات اور تعليم كے زير اثر فكرى، فلسفي اور علمي پہلو كا حامل ہوتا ہے اور پھر بعض تجربات كے ذريعے ايك اور جہت تك پہنچتا ہے، جسے ہم اخلاقى جہت كے نام سے ياد كرتے ہيں، يہي وہ بعد يا جہت ہے، جو قدرت ( Value ) پىدا كرتي ہے، اس كے لئے اخلاقى معيار عمل پىش كرتي اور بتاتي ہے كہ كيا كرنا يا ہونا چاہيے اور كيا نہيں؟ مذہب اور آرٹ كي جہت كي بھي يہي صورت ہے۔ انسان اپني فكرى اور فلسفي جہات ميں كچھ فكرى اصول و مباني پىدا كر ليتا ہے اور يہي اس كي فكرى و فلسفي اساس بنتے ہيں، اسي طرح اپني اخلاقى اور اجتماعى معيار سنجي كے ذريعے وہ كچھ مطلق اور نيم مطلق اقدار تك پہنچتا ہے۔ يہ سب انساني ابعاد اور جہات انساني وجود كي تشكيل كرتي ہيں ۔
انساني جہات تمام كي تمام اجتماعى عوامل سے وجود ميں آتي ہيں۔ انسان آغاز پىدائش ميں ان تمام جہات سے عاري ہوتا ہے، فقط ايك خام مادہ ہوتا ہے، جو ہر فكرى اور جذباتي شكل ميں ڈھلنے كے لئے تيار ہوتا ہے، اب يہ اس بات پر منحصر ہے كہ وہ كن عوامل كے زير اثر قرار پاتا ہے، وہ ايك خالي برتن كي طرح ہے، جسے باہر سے بھرا جاتا ہے، وہ ايك آڈيو ٹيپ ہے، جس ميں آوازيں ريكارڈ كي جاتي ہيں اور جو چيز اس ميں بھرتي جاتي ہے، بعينہ وہي سني جاتي ہے۔ مختصر يہ كہ انسان كي شخصيت كي تعمير كرنے والے اور اسے ”شئے“ كي صورت سے نكال كر ”شخص“ بنانے والے وہ خارجي اجتماعى عوامل ہيں جو اسے ”شئے“ سے ”شخص“ بناتے ہيں۔ ”پى- رويان“ اپني تاليف ”تاريخي ميٹريالزم“ ميں ”ماركسزم كے اصولي مسائل“ جو ”بلخانف“ كي تاليف ہے، كے صفحہ(۴۳) سے نقل كرتا ہے:
”سماجي ماحول كي صفات ہر زمانے كي اپني پىداواري قوتوں كي سطح كے مطابق وجود ميں آتي ہيں يعني جب پىداواري قوتوں كي سطح معين ہوجاتي ہے، تو اجتماعى ماحول كي صفات اور اس سے متعلق سائيكالوجى، ماحول اور افكار و كردار كے باہمي روابط كا تعين بھي ہو جاتا ہے ۔“
اسي كتاب ميں مزيد لكھتا ہے:
”جب پىداواري قوتوں كے ذريعے سائيكالوجي (نفسيات) كا تعين ہوجاتا ہے تو نتيجتاً اس سے متعلق وہ آئيڈيالوجىز ( Ideologies ) بھي معين ہوجاتي ہيں، جو اس سائيكالوجي سے قريب ہوں، ليكن اس آئيڈيالوجى كي برقراري كے لئے كہ جو تاريخي مرحلے ميں اجتماعى روابط سے ابھرتي ہے اور نيز اس لئے كہ وہ وقت كے حاكم طبقے كے مفادات كي ہميشہ حفاظت كرے، ضروري ہے كہ اجتماعى اداروں كے ذريعے اس كي تقويت اور تكميل ہو۔
پس در حقيقت طبقاتي معاشروں كے اجتماعى ادارے باوجود اس كے كہ حكمران طبقے كي حفاظت اور آئيڈيالوجى كي توسيع و تقويت كے لئے وجود ميں آتے ہيں ليكن اصولاً ان كا تعلق اجتماعى روابط كے نتائج سے ہوتا ہے۔ آخري تجزيے كے مطابق وہ پىداواري كيفيت اور خصلت سے ابھرتے ہيں مثلاً چرچ اور مسجديں مذہبى عقائد كي نشر و اشاعت كے لئے ہوتي ہيں اور ان كي بنياد تمام مذاہب ميں روز جزاء پر ايمان ہے۔ روز جزاء پر ايمان طبقاتي تقسيم پرمبني مخصوص اجتماعى روابط سے پىدا ہوتا ہے جب كہ طبقاتي تقسيم پىداواري وسائل كے ايك تكاملي مرحلے سے وجود ميں آتي ہے۔گويا آخري بات يہ ہے كہ روز جزاء پر ايمان پىداواري قوتوں كي خصلت كا نتيجہ ہے ۔
اس اصول كا نقطہ مقابل علم بشريات ( Enthropology ) كے ايك اور مكتب كے ايك اصول جس كے مطابق اعليٰ افكار اور عالى جذبوں پر مشتمل انساني شخصيت كي اساس اس كي خلقت ميں عوامل خلقت كے ہاتھوں ركھي گئي ہے۔ يہ درست ہے كہ انسان افلاطون كے نظريے كے برخلاف ايك بني بنائي شخصيت كے ساتھ دنيا ميں نہيں آتا ليكن وہ اپني شخصيت كے اصلي اركان اور اصلي بنيادوں كو معاشرے سے نہيں بلكہ خلقت سے پاتا ہے۔ اگر ہم فلسفي اصطلاح ميں يہ بات كہنا چاہيں تو ہميں اس طرح كہنا ہوگا كہ اخلاق، مذہب، فلسفہ، آرٹ ار عشق جيسي بنيادي انساني جہات كا اصلي سرمايہ انسان كي نوعي صورت، اس كے باب كا مبداء ار اس كا نفس ناطقہ ہے، جس كي تكوين عوامل خلقت كے ذريعے ہوتي ہے۔ معاشرہ انسان كو ذاتي استعداد كے اعتبار سے يا پرورش ديتا ہے يا پھر مسخ كرتا ہے۔ نفس ناطقہ ابتدائي امر ميں بالقوہ ہوتا ہے اور پھر بتدريج عملي صورت اختيار كرتا ہے، لہٰذا انسان فكر و فہم كے ابتدائي اصول نيز مادي اور معنوي ميلانات كے اعتبار سے دوسرے زندہ موجودات كي طرح ہے كہ پہلے تمام بنياديں بالقوہ اس ميں موجود ہوتي ہيں اور پھر بعض جوہري حركات ان خصلتوں كو ابھارتي ہيں۔ اس طرح يہ چيزيں انسان ميں نشوونما پاتي ہيں۔ انسان بيروني عوامل كے زير اثر اپني فطري شخصيت كي پرورش كرتا ہے اور اسے كمال تك پہنچاتا ہے يا پھر دوسري صورت ميں اسے مسخ اور منحرف كرتا ہے۔ يہ وہي اصول ہے جسے اسلامي علوم ميں ”فطرت“ كے نام سے ياد كيا جاتا ہے، اصول فطرت وہ ہے جسے اسلامي علوم ميں ام الاصول كے عنوان سے ياد كيا جاتا ہے ۔
اصول فطرت كے اعتبار سے انسان كي نفسيات اس كي عمرانيات پر مقدم ہوتي ہے۔ انساني كي عمرانيات اس كي نفسيات سے حصول فيض كرتي ہے۔ اسي اصول فطرت كے اعتبار سے انسان جب پىدا ہوتا ہے باوجود اس كے كہ وہ بالفعل نہ كوئي ادراك ركھتا ہے اور نہ كوئي تصور، نہ تصديق اور نہ اس ميں انساني ميلانات ہوتے ہيں ليكن پھر بھي وہ حيواني پہلوؤں كے ساتھ وجودي پہلوؤں كو بھي اپنے ساتھ لاتا ہے، يہي وہ پہلو ہيں جو انتزاعي تصورات، منطقي تصديقات (منطقي اصطلاح ميں ”معقولات ثانيہ“) كے ايك سلسلے كو جو انساني فكر كي اساس ہے اور اس كے بغير ہر طرح كي منطقي سوچ محال ہے، انسان ميں جنم ليتے ہيں اور اس ميں علوي ميلانات بھي انہي پہلوؤں سے پىدا ہوتے ہيں، يہي وہ پہلو ہيں، جو انساني شخصيت كي حقيقي اساس سمجھے جاتے ہيں۔ انسان كي نفسيات پر اس كي عمرانيات كے تقدم سے متعلق نظريے كي مطابق انسان محض ايك اثر پذير ہستي ہے اور جدوجہد كرنے والي اور تخليق كار نہيں۔ وہ ايك خام مال ہے، جو بھي شكل اسے دي جائے گي اس كي ذات كے اعتبار سے اس كے لئے يكساں ہوگي۔ وہ ايك خالي ٹيپ كي طرح ہے، جو آواز بھي اس ميں بھري جائے گى، ٹيپ كي طرح ذات كے اعتبار سے كسي بھي اور آواز كي طرح ہوگى، جو بھي اس ميں بھري جائے۔ اس خام كے اندر كسي معين شكل كي سمت حركت نہيں كہ اگر وہ ”شكل“ اسے دي جائے تو گويا وہ خود اسي كي اپني شكل ہوگي اور اگر اسے كسي دوسري شكل سے ہمكنار كيا جائے تو گويا ايسا ہوگا، جيسے اس كي صورت كو مسخ كر ديا گيا ہو، اس ٹيپ كے اندر ايك معين آواز مطلوب نہيں ہے كہ اگر دوسري آواز اس ميں بھر دي جائے تو وہ اس كي ذات اور اس كي حقيقت سے ہٹ كر ہوگي۔ اس مادے كي نسبت تمام شكلوں سے، اس ٹيپ كي نسبت تمام آوازوں سے اور اس ظرف كي نسبت تمام چيزوں سے يكساں ہے ۔
ليكن اصول فطرت اور انسان كي نفسيات پر اس كي عمرانيات كے تقدم كي بنياد پر انسان اپنے آغاز حيات ميں ہر چند ہر ادراك بالفعل اور ہر ميلان بالفعل سے عاري ہوتا ہے، ليكن وہ اپنے اندر سے ڈائنا ميكي ( Dynamique ) صورت ميں بعض ابتدائي قضاوتوں جنہيں بديہيات اوليہ بھي كہا جاتا ہے، كي طرف نيز ان بلند مرتبہ اقدار كي سمت جو اس كي انسانيت كي معيار ہے، گامزن ہے، سادہ تصورات جو فكر كرنے كے لئے ابتدائي مواد كا كام كرتے ہيں اور جنہيں فلسفي اصطلاح ميں ”معقولات اوليہ“ كہتے ہيں، باہر سے ذہن ميں اترنے كے بعد وہ اصول نظري ياعملي تصديقات كي صورت ميں پھوٹتے ہيں اور يہ ميلانات اپنا اظہار كرتے ہيں ۔
پہلے نظريے كے مطابق يہ جو انسان ان موجودہ شرائط ميں ”مثلاً ۲*۲=۴ كے اصول كو صحيح تسليم كرتا ہے اور اسے ايك ايسا حكم مطلق مانتا ہے، جو تمام زمانوں اور مكانوں ميں يكساں طور پر حكم فرما ہے، درحقيقت اس كے اپنے ماحول كي خاص شرائط اور حالت كي پىداوار ہے، يعني اس خاصا ماحول اور خاص شرائط ميں بني نوع انسان كا رد عمل ہے اور درحقيقت يہ وہ آواز ہے جو اس ماحول ميں اس طرح ٹيپ ہوئي ہے، ممكن ہے دوسرے ماحول اور دوسري شرائط ميں اس كي صورت مختلف ہو اور وہ مثلاً ۲*۲=۲۶ ہو۔
ليكن دوسرے نظريے كے مطابق ماحول جو كچھ انسان كو ديتا ہے، وہ ۲، ۴، ۸،۱۰وغيرہ كا تصور ہے، ليكن يہ حكم كے ۲*۲=۴ يا ۵*۵=۲۵ انساني روح كي عمارت كا لازمہ ہے اور محال ہے، اس سے كوئي دوسري شكل رونما ہو اور يہ اسي طرح ہے جس طرح انسان كا طلب كمال كرنا اس كي خلقت روح كا لازمہ ہے۔(۲۱)
۵۔ معاشرے كے معنوي پہلوؤں پر مادي پہلوؤں كا تقدم
معاشرہ، اداروں، تنظيموں اور كئي شعبوں كا مجموعہ ہے۔ اقتصادي شعبہ، ثقافتي شعبہ، انتظامي شعبہ، سياسى شعبہ، مذہبى شعبہ، عدالتي شعبہ وغيرہ۔ اس اعتبار سے معاشرہ ايك مكمل عمارت كي طرح ہے۔ جس ميں ايك گھرانہ زندگي بسر كرتا ہے، اس ميں ڈرائنگ روم، ڈائنگ روم، بيڈروم، كچن، غسل خانہ وغيرہ سبھي كچھ ہوتا ہے ۔
معاشرتي اداروں ميں ايك ادارہ ايسا ہے، جس كي حيثيت بنياد كي سي ہے، جس پر تمام عمارت اپني پوري مضبوطي كے ساتھ قائم ہے، اگر وہ متزلزل ہو جائے تو پوري عمارت منہدم ہوجائے اور وہ معاشرے كا اقتصادي ڈھانچہ ہے ، يعني وہ چيزيں جن كا تعلق معاشرے كي بنيادي پىداوار سے ہے۔ جيسے پىداواري آلات، پىداواري ذرائع اور پىداواري روابط و تعلقات ۔
پيداواري آلات جو معاشرے كي ساكھ كا سب سے اہم حصہ ہيں۔ اپني ذات ميں تغير و ارتقاء پذير ہيں۔ پىداواري آلات كي ترقي و تكامل كے ساتھ ساتھ اسي اعتبار سے يہ رابطہ و تعلقات بھي بدلتے رہتے ہيں۔ پىداواري روابط يعني مالكيت سے متعلق اصول و قوانين كي كيفيت، درحقيقت يہ وہ قوانين ہيں، جو معاشرے كے نتيجہ عمل كے ساتھ انسان كے قرارداري روابط كو قائم كرتے ہيں۔ پىداواري روابط كي لازمي اور حتمي تبديلي كے بعد انسان كے تمام قانونى، فكرى، اخلاقى، مذہبى، فلسفي اور علمي اصول بھي تبديل ہو جاتے ہيں۔ مختصر يہ كہ ”بنياد معيشت“ ہے ۔
كتاب ”ماركس اور ماركسزم“ ميں كارل ماركس كے رسالے ”سياسي معيشت پر تنقيد“ سے منقول ہے:
” انسان اپني زندگي پىداوار ميں ايسے ضروري اور معين تعلقات كو اپناتا ہے، جو اس كے ارادے سے الگ ہوتے ہيں۔ يہ پىداواري روابط مادي قوتوں كي ترقي اور توسيع كے ايك معين درجے سے مطابقت ركھتے ہيں۔ مجموعي طور پر يہ روابط معاشرے كا اقتصادي ڈھانچہ بنتے ہيں، يعني حقيقي بنياد جس پر معاشرے كي قانوني اور سياسى عمارت معاشرتي شعور كي معين شكلوں كے مطابق بنتي ہے۔ مادي زندگي ميں سماجى، سياسى اور روشن فكرانہ زندگي كي رفتار پىداواري روش سے معين ہوتي ہے۔ انسان كا شعور اس كے وجود كو معين نہيں كرتا، بلكہ اس كے برعكس اس كا معاشرتي وجود اس كے شعور كو معين كرتا ہے ۔“(۲۲)
اسي كتاب ميں اننكوف كے نام ماركس كے خط سے نقل كيا گيا ہے:
”اگر آپ انسانوں كي پىداواري قوتوں كي وسعت كي كيفيت كو اپنے سامنے ركھيں تو ان كي تجارت اور كھيپ كي كيفيت از خود آپ كے سامنے آجائے گي۔ آپ تجارتي پىداواري اور مصرف پر توجہ كريں تو اس ميں طبقاتي و اصنافي تقسيم اور خانداني نظام اور اجتماعى تركيب مختصراً يہ كہ پورا مدني معاشرہ آپ كو دكھائي دے گا ۔“(۲۳)
”پيٹر“ ماركس كا نظريہ كي ان الفاظ ميں وضاحت كرتا ہے:
”اور اس طرح ماركس معاشرے كو ايك ايسي عمارت سے تعبير كرتا ہے، جس كي بنياد كو معاشي قوتيں اور خود اس عمارت كو افكار، آداب و رسوم اور نيز عدالتى، سياسى، مذہبى وغيرہ ادارے تشكيل ديتے ہيں، جس طرح كسي عمارت كا دارومدار اس كي بنياد پر ہوتا ہے، اسي طرح معاشي حالات يا پىداواري روابط بھي فني كيفيت سے وابستہ ہيں اور افكار، رسوم اور سياسى نظام كي صورتيں بھي اس معاشي حالات كے تابع ہيں۔“(۲۴)
اسي كتاب ميں لينن سے منقول ہے:
”پيداواري روش عالم طبيعت اور انساني زندگي كي پىداوار كے فوري نتائج نيز اجتماعى حالات اور ان سے پىدا شدہ فكرى حالات كے مقابل انساني طرز عمل كي آئينہ دار ہوتي ہے ۔“
”سياسي معيشت پر تنقيد“ كے پىش لفظ ميں وہ لكھتا ہے:
”ميري تحقيقات ميں مجھے يہ فكر دي كہ عدالتي تعلقات اور حكومت كي مختلف صورتيں نہ تو از خود ظہور ميں آسكتي ہيں اور نہ گويا انساني سوچ كا عمومي تحول اسے وجود ميں لا سكتا ہے، بلكہ يہ روابط اور يہ مختلف صورتيں موجود مادي شرائط سے ابھرتي ہيں ۔معاشرے كي ”اناٹومي“ كو سياسى معيشت ميں تلاش كرنا چاہيے ۔“
”ماركس“، ”فقر فلسفہ“ ميں لكھتا ہے:
”معاشري روابط مكمل طور پر پىداوار قوتوں سے تعلق ركھتے ہيں۔ انسان نئي پىداواري قوتوں كو حاصل كر كے اپني پىداوار كي كيفيت كو بدل سكتا ہے۔ پىداواري كيفيت اور طرز حصول معاش ميں تبديلي لا كر مكمل طور پر اپنے اجتماعى روابط كو بدل ديتا ہے۔ ہاتھ كي چكي معاشرے كي طوائف الملوكي اور بجلي يا بھاپ سے چلنے والي چكي سرمايہ دارانہ صنعتي معاشرے كي نشان دہي كرتي ہے ۔“
تمام معاشرتي شعبوں پر مادي شعبے كي تقدم سے متعلق نظريہ فكر پر كام كے تقدم كے نظريے جيسا ہي ہے۔ فكر پر كام كے تقدم كا نظريہ انفرادي سطح پر بيان كيا جاتا ہے اور مادي شعبے كے ديگر اجتماعى شعبوں پر تقدم كا نظريہ درحقيقت فكر پر كام كے تقدم كا نظريہ ہي ہے، ليكن اجتماعى سطح پر انساني نفسيات كے علم كو اس كے اس كے علم عمرانيات پر مقدوم جانے تو اس كے برخلاف ہوگا۔ مادي شعبے كا معاشرے كے ديگر شعبوں پر تقدم انفرادي كام كے انفرادي فكر پر تقدم كا نتيجہ ہے۔
معاشرے كا مادي شعبہ جو معاشي ساخت اور معاشي بنياد بھي كہلاتا ہے، دو حصوں ميں تقسيم ہوتا ہے، ايك پىداواري آلات، جو عالم طبيعت كے ساتھ انسان كے رابطے سے وجود ميں آتے ہيں اور دوسرے دولت كي تقسيم كے سلسلے ميں معاشرے كے افراد كا ايك دوسرے كے ساتھ معاشي رابطہ جسے گاہے پىداواري تعلقات سے بھي تعبير كيا جا سكتا ہے۔ پىداواري آلات اور پىداواري تعلقات كے مجموعے كو عام طور پر ”كيفيت پىداوار“ يا ”طرز پىداوار“ كے نام سے ياد كيا جاتا ہے۔ (پي نكسن كي كتاب ”مباني علم اقتصاد“ ديكھئے جسے ناصر زرافشاں نے ترجمہ كيا ہے مرج۔ نيز رويان كي كتاب ميٹريالزم تاريخ ميں پىداوار كا موضوع ديكھئے) نيز يہ بات بھي جاننا ضروري ہے كہ يہ اصطلاحات تاريخي ماديت كے رہنمائوں كي زبان ميں ابہام ميں خالي نہيں اور وہ صاف اور واضح زبان ميں اس كي وضاحت نہيں كر سكتے۔ (ديكھئے ”تجديد نظرطلبي از ماركس تا مائو “) جہاں اس بات كا تذكرہ ہوتا ہے كہ معاشيات اساس ہے اور معاشرے كا مادي پہلو باقي تمام پہلوؤں پر مقدوم ہے ، اس سے مراد تمام پىداواري نظام ہے۔ اس ميں آلات پىداوار اور پىداواري روابط دونوں شامل ہيں۔ وہ نكتہ جس پر توجہ ضروري ہے اور جو تاريخي ماديت كے رہنمائوں كي گفتگو ميں مختلف مقامات پر پوري طرح ظاہر ہوتا ہے۔ يہ ہے كہ خود بنياد دو طبقوں پر مشتمل ہے، جن ميں ايك دوسرے كي بنياد ہے اور دوسرا اس پر قائم ہے۔ اصل بنياد دراصل پىداواري آلات يعني مجسم كام ہے، يہ مجسم كام دولت كي تقسيم كے اعتبار سے خاص قسم كے معاشي روابط كا متقاضي ہے۔ يہ روابط جو پىداواري آلات كي ترقي كے درجے كے آئينہ دار ہوتے ہيں، اپنے آغاز پىدائش ميں صرف يہي نہيں كہ پىداواري آلات كے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہيں بلكہ ان كا محرك اور مشوق بھي ہوتے ہيں، يعني يہ ان آلات سے حصول منفعت كا بہترين ذريعہ بھي ہيں۔ يہ پىداواري آلات كے جسم پر بالكل فٹ آنے والا لباس ہے، ليكن پىداواري آلات خود اپني ذات ميں ترقي پذير ہيں۔ پىداواري آلات كي ترقي پىداواري نظام كے دونوں يونٹوں كے درميان ہم آہنگي كو توڑ ديتي ہيں، يعني وہي قوانين جو سابقہ پىداواري آلات كي مناسبت سے وجود پذير ہوئے تھے، ترقي يافتہ پىداواري آلات كے بدن پر تنگ ہو جاتے ہيں، اس كے لئے ركاوٹ بن جاتے ہيں اور دو يونٹوں كے درميان تضاد كا سامان فراہم كرتے ہيں۔ آخركار مجبور ہو كر نئے پىداواري آلات سے مناسبت ركھنے والے جديد پىداواري روابط قائم كرنے پڑتے ہيں۔ اس طرح معاشرے كي اساس بالكل دگرگوں ہو جاتي ہے۔ اسي تبديلي كے نتيجے ميں تمام مذہبى، اخلاقى، فلسفي اور قانوني عمارت كو بھي جو اس بنياد پر قائم تھى، منہدم ہونا پڑتا ہے ۔
اجتماعي كام بالفاظ ديگر مجسم كام جسے پىداواري آلات كہتے ہيں، كي ترجيح كو ملحوظ خاطر ركھتے ہوئے نيز اس امر پر توجہ كرتے ہوئے كہ ماركس ان ماہر عمرانيات ميں سے ہے، جو انسان كے علم عمرانيات كو اس كے علم نفسيات پر مقدم جانتے ہيں اور انسان كو انسان كي حيثيت سے ايك اجتماعى وجود اور خود ماركس كے الفاظ ميں ”جزك“ وجود ہے، كام كا فلسفي كردار ماركسزم كي نظر ميں واضح ہوجاتا ہے، يہ بات فلسفہ ماركسٹ كا جوہر ہے، جس پر كم توجہ دي گئي ہے ۔
ماركس، كام كي انساني وجوديت اور انسان كي كام سے وجوديت كے بارے ميں اسي طرح سوچتا ہے، جس طرح ڈيكارٹ انسان كي عقلاني وجوديت، برگسن، استمراري اور ژان پال سارتر اس كي عصياني وجوديت كے بارے ميں سوچتے ہيں ۔
ڈيكارٹ كہتا ہے: ”ميں فكر كرتا ہوں پس ميں ہوں ۔“
برگسن كہتا ہے: ”مجھ ميں استمرار ہے، پس ميں ہوں ۔“
سارتر كہتا ہے: ”ميں گناہ كرتا ہوں، پس ميں ہوں ۔“
ماركس بھي يہي كچھ كہنا چاہتا ہے، وہ كہتا ہے: ”ميں كام كرتا ہوں، پس ميں ہوں ۔“
ان دانشوروں ميں كوئي نہيں چاہتا كہ وہ سوچ، استمرار يا عصيان وغيرہ جيسي چيزوں سے ماوراء انساني ”ميں“ كي موجوديت كو اثبات كرے بلكہ بعض تو انسان كے لئے ان كے علاوہ كسي وجوديت كے قائل نہيں ہيں بلكہ ہر كوئي ضمناً يہ چاہتا ہے كہ وہ جوہر انسانيت اور انسان كي وجودي حقيقت كي تعريف كرے ۔
مثلاً ڈيكارٹ يہ كہنا چاہتا ہے: ”ميري وجوديت، فكر كي وجوديت كے مساوي ہے اگر فكر نہيں تو ميں بھي نہيں ۔“ برگسن كہنا چاہتا ہے: ”انسان كي موجوديت عين استمرار اور زمانے كي موجوديت ہے ۔“ سارتر كي گفتگو بھي يہي ہے كہ ”جوہر انسانيت اور انسان كي حقيقي وجوديت گناہ اور سرتابي ہے، اگر گناہ كو انسان سے ہٹا ليا جائے تو پھر وہ نہيں ہے ۔“ ماركس بھي اپنے مقام پر كہنا چاہتا ہے: ”انسان كي تمام موجوديت اور اس كي حقيقي ہستي ”كام“ ہے۔ كام انسانيت كا جوہر ہے۔ ميں كام كرتا ہوں، اس لئے ميں ہوں۔ اس مفہوم ميں نہيں كہ كام ميري وجوديت كي دليل ہے بلكہ يہ كام ميري عين وجوديت اور ميري حقيقي ہستي ہے ۔“
ماركس كہتا ہے:
”سوشلسٹ انسان كے نزديك پوري عالمي تاريخ بشرى، كام كے ذريعے انسان كي خلقت كے سوا كچھ نہيں ۔“(۲۵)
يا وہاں جہاں وہ انسان كي آگاہي اور اس كے حقيقي وجود كے درميان فرق پىدا كر كے كہتا ہے:
”انسانوں كي آگاہي ان كے وجود كو معين نہيں كرتي بلكہ اس كے برعكس ان كا ”اجتماعي وجود“ ان كي آگاہي كو معين كرتا ہے۔“(۲۶)
يا پھر يہ بات كہ
”وہ مقدمات جن سے ہم آغاز كرتے ہيں، ايسي بنياديں نہيں جو خود اختياري ہوں اور ارادے پر مبني ہوں بلكہ حقيقي افراد، ان كا عمل اور ان كے مادي وجود كي شرائط اور حالات ہيں ۔“
پھر ماركس ان حقيقي افراد كي اس طرح وضاحت كرتا ہے:
”يہ طرز فكر ہم جيسے لوگوں كے لئے حيران كن ہے، جو انسان كي حقيقي ہستي اس كي ”ميں“ ( Self ) كو جانتے ہيں اور اس ”ميں“ كو غير مادي جو ہر قرار ديتے ہيں اور اسے عالم طبيعت كي جوہري حركات كي پىداوار سمجھتے ہيں، معاشرے كي پىداوار نہيں، ليكن وہ شخص جو ماركس كي طرح مادي سوچ كا حامل ہے اور غير مادي جوہر پر يقين نہيں ركھتا اس كے لئے ضروري ہے كہ وہ انسان كے جوہر اور اس كي حقيقت كي حياتياتي پہلو سے توجيہ كرے اور كہے كہ انسان كا جوہر اس كے بدن كي مادي ساخت ہي ہے۔ جس طرح قديم مادہ پرستوں مثلاً اٹھارويں صدي كے مادہ پرستوں كا عقيدہ تھا ليكن ماركس اس نظريے كو رد كرتا ہے، اس كادعويٰ ہے كہ انسانيت كا جوہر معاشرے ميں تشكيل پاتا ہے، عالم فطرت ميں نہيں، جو چيز فطرت ميں صورت اختيار كرتي ہے وہ انسان بالقوہ ہے، بالفعل نہيں۔ اب ماركس فكر كو جوہر انسانيت قرار دے اور كام اور فعاليت كو فكر كا مظہر و تجلي قرار دے۔مادي فكر ركھنے والا ماركس يہي نہيں كہ فرد ميں مادے كي اصالت كا قائل ہے اور فرد ميں مادے سے ماوراء جوہر كا انكاري ہے، معاشرے اور تاريخ كے باب ميں بھي مادے كي اصالت كا قائل ہے اور ناچار دوسري صورت كو منتخب كرتا ہے ۔
اس مقام پر ہويت تاريخ كے بارے ميں ديگر مادہ پرست مفكرين سے ماركس كے نظريے كا فرق واضح ہوتا ہے۔ ہر مادي نظريہ ركھنے والا مفكر بہرحال اس اعتبار سے كہ انسان اور اس كے وجودي مظاہر كو مادي جانتا ہے، تاريخ كي ماہيت و ہويت كو بھي مادي گردانتا ہے، ليكن ماركس اس سے بڑھ كر بات كرتا ہے ۔ وہ كہنا چاہتا ہے:
ماہيت تاريخ معاشي ہے اور معاشيات ميں چونكہ وہ معاشي پىداواري روابط يعني انسان كي مالكيت اور حاصل كار كو ايك لازمي اور ضروري امر اور پىداوار آلات يعني تجسم يافتہ كام كے مرحلہ پىش رفت كي انعكاسي صورت جانتا ہے لہٰذا درحقيقت يہ كہنا چاہتا ہے كہ ہويت تاريخ آلاتي ہے۔ پس صرف يہ كہہ دينا كہ ہويت تاريخ مادي ہے يا حتيٰ اسے معاشي كہنا ماركس كے نظريے كا مكمل بيان نہيں ہے۔ ہميں اس امر پر توجہ دينا چاہيے كہ تاريخ كي روح اور ہويت ماركس كي نگاہ ميں آلاتي ہے، يہي وجہ ہے كہ ہم نے اپني بعض تحريروں ميں ماركس كے تاريخي ميٹريالزم كو ”آلاتي نظريہ“ كہا ہے اور يہ بات ہم نے تاريخ سے مطالق اپنے ”انساني نظريہ“ كو سامنے ركھ كر كہي ہے، جس كے مطابق تاريخ انساني ماہيت كا ماحاصل ہے ۔
حقيقت يہ ہے كہ ماركس ”فلسفہ كار“ ميں اتنا غرق ہے اور كام كو ايسا اجتماعى نظريہ ديتا ہے كہ اس كے فلسفے كے مطابق درست يوں سوچنا پڑتا ہے كہ انسان وہ نہيں جو كوچہ و بازار ميں چلتے، پھرتے، سوچتے اور فيصلہ كرتے نظر آتے ہيں بلكہ مثلاً حقيقي انسان وہ آلات اور وہ مشينيں ہيں جو كارخانوں كو چلا رہي ہيں۔ وہ انسان جو چلتے، پھرتے، سوچتے اور بات كرتے ہيں انسان كي ”مثال“ ہيں ”خود“ انسان نہيں ۔
پيداواري آلات اور اجتماعى كاموں كے بارے ميں ماركس كا تصور ايك جاندار وجود كا سا ہے۔ جو خود بخود سوچي سمجھي ”مثالوں“ يعني انساني مظاہر كے ارادے اور فيصلے كے بغيرہي ايك جبر كے تحت رشد كرتے رہتے ہيں اور ارتقاء پاتے رہتے ہيں اور ظاہري انسانوں ”مثالوں“ كو جو فكر و ارادہ كي حامل ہيں، كو اپنے جبري اور قہري نفوذ كے تحت ركھتے اور انہيں اپنے پىچھے پىچھے چلائے ركھتے ہيں ۔
ايك اعتبار سے يہ كہا جا سكتا ہے كہ ماركس اجتماعى كار اور انسان كے شعور، ارادے اور آگاہي كے بارے ميں وہي كچھ كہتا ہے جو بعض حكمائے الٰہي انسان كے بدن كي اس كي فعاليت كے بارے ميں كہا كرتے تھے، جو غير شعوري طور پر نفس كے ايك آٹو ميٹك پوشيدہ ارادے كے تحت رو بہ عمل رہتي ہے، جيسے ہاضمے كا عمل يا قلب و جگر وغيرہ كے افعال ۔
ان حكماء كے نقطہ نظر سے ميلانات، خواہشات، چاہتيں، نفرتيں اور وہ جملہ امور جو نفس كے عملي پہلو سے تعلق ركھتے ہيں، يعني جو سفلى، تدبيرى، تعلقي اور بدن سے متعلق ہيں اور جو ذہن كے لئے آگاہ شعور كي سطح پر ہوتے ہيں، بعض طبيعي ضرورتوں سے ابھرتے ہيں اور يہ آگاہ شعور يہ جانے بغير كہ ان امور كي اساس كہاں ہے مجبوراً نفس كي پوشيدہ تدبير كے تحت قرار پاتا ہے۔ يہ اس چيز سے ملتي جلتي ہے، جسے فرائيڈ نے شعور باطن يا شعور ناآگاہ كہا ہے اور جو شعور آگاہ پر مقتدرانہ تسلط ركھتي ہے، ليكن اس فرق كے ساتھ كہ جو كچھ سابقہ حكماء كہتے تھے يا جو كچھ فرائيڈ كہتا تھا اولاً شعور ظاہر كے ايك حصے سے اس كا تعلق تھا، ثانياً ايك مخفي شعور كي حكومت اس پر كارفرما تھى، علاوہ ازيں وہ جو كچھ كہتے تھے انسان كے وجود سے باہر نہيں تھا اور جو كچھ ماركس كہتا ہے وہ وجود انسان سے باہر ہے اگر بنظر غائر ديكھا جائے تو ماركس كا نظريہ فلسفي نقطہ نظر سخت تعجب خيز ہے ۔
ماركس اپني اس دريافت كا ڈارون كي مشہور حياتياتي دريافت كے ساتھ موازنہ كرتا ہے۔ ڈارون نے يہ ثابت كيا كہ كس طرح كوئي امر حيوان كے ارادے اور شعور سے باہر اثبات كا سبب بنتا ہے كہ وقت كے گزرتے ہوئے لمحات ميں اس كا بدن بتدريج اور لاشعوري طور پر تكميل كي منزليں طے كرے۔ ماركس بھي يہي دعويٰ كرتا ہے كہ ايك اندھا امر (جو انسان كي حقيقي ہستي بھي ہے) بتدريج اور ناآگاہانہ طور پر اس بات كا سبب بنتا ہے كہ انسان كے اجتماعى بدن كي تعمير ہو، يعني وہ چيزيں جنہيں ماركس نے عمارت كہا ہے بلكہ خود بنياد كا ايك حصہ يعني اجتماعى معاشي روابط كي تعمير ہو۔
وہ كہتا ہے:
”ڈارون نے طبيعي ”فن شناسي“ كي تاريخ كي طرف دانشوروں كي طرف مبذول كي ہے، يعني ان كي زندگي كے لئے پىداواري وسائل كي حيثيت سے پودوں اور جانوروں كے اعضاء كي تشكيل كي طرف توجہ دلائي ہے، كيا اجتماعى انسان كو وجود ميں لانے والے اعضاء كي تاريخ پىدائش يعني ہر طرح كي اجتماعى تشكيلات كي مادي اساس كے بارے ميں اس طرح كي سوچ مناسب نہيں؟ ۔۔۔ فن شناسي عرياں طبيعت كے مقابل انسان كے طرز عمل كو بناتي ہے۔ پىداوار حاصل كرنے والي اس كي مادي زندگي اور نتيجے كے طور پر اجتماعى تعلقات اور فكرى محصولات جو ان سے پىدا ہوتے ہيں، كے شرچشمے كو آشكار كرتي ہے ۔“(۲۷)
اب تك مجموعي طور پر جو كچھ كہا گيا ہے اس سے يہ بات واضح ہوئي كہ تاريخي ميٹريالزم چند اور نظريوں پر مبني ہيں جن سے بعض علم نفسيات سے، بعض عمرانيات سے، بعض فلسفے سے اور بعض علم بشريت سے متعلق ہيں ۔
”ليكن يہ افراد ايسے نہيں، جو اپنے ہي تصور ميں ظاہر ہو سكيں ۔۔۔ بلكہ ايسے كہ مادي طور پىدا كرتے ہيں اور بناتے ہيں يعني وہ اپنے ارادے سے جدا ہو كر معين مادي اساس، شرائط اور حدود كے مطابق عمل كرتے ہيں ۔“(۲۸)
يا پھر اينجلز كا يہ جملہ كہ
”اقتصادي ماہرين كہتے ہيں كہ كام تمام سرمائے كا سرچشمہ ہے ليكن بغير انتہاء كے اس سے زيادہ نہيں۔ كام پوري انساني زندگي كے پہلي بنيادي شرط ہے۔ اس طرح كہ گويا ايك اعتبار سے يہ كہنا پڑتا ہے كہ خود انسان بھي كام كي تخليق ہے ۔“
يہ سب اقوال ايك ہي نظريے كي ترجماني كرتے ہيں۔ البتہ ماركس اور اينجلز نے اضافي وجود ميں كام كے كردار سے متعلق اس نظريے كو ہيگل سے ليا ہے۔ ہيگل نے پہلي بار يہ كہا تھا:
”انسان كي حقيقي ہستي پہلے درجے ميں اس كا عمل ہے ۔“
پس ماركس كے نقطہ نظر سے انسان كي انساني وجوديت اولاً انفرادي نہيں اجتماعى ہے، ثانياً اجتماعى انسان كي وجوديت اجتماعى كام يعني ايك مجسم كام ہے اور اپنے انفرادي احساس يا احساسات كي طرح ہر انفرادي امر يا پھر فلسفہ، اخلاق، آرٹ اور مذہب وغيرہ كي طرح كا ہر اجتماعى امر انسان كي حقيقي وجوديت كا مظہر و تجلي ہے، اس كي عين حقيقي وجوديت نہيں۔ اس بناء پر ہر انسان كا حقيقي تكامل و ارتقاء عيناً اجتماعى كام كا تكامل ہے، ليكن فكرى، جذباتي اور احساساتي تكامل يا معاشرتي نظام كا تكامل حقيقي تكامل كے مظاہر و تجليات ہيں، عين تكامل نہيں۔ معاشرے كا مادي تكامل اس كے روحاني تكامل كا معيار ہے۔گويا يہ اسي طرح ہے، جس طرح عمل معيار فكر ہے۔ فكر كي صحت و سقم كو عمل سے پركھنا چاہيے، فكرى اور منطقي معياروں سے نہيں۔ روحاني تكامل كا معيار بھي مادي تكامل ہے۔ پس اگر يہ بات پوچھي جائے كہ فلسفہ، اخلاق، مذہب اور آرٹ ميں كون سے مكتب زيادہ ترقي يافتہ ہيں، تو فكرى اور منطقي معيار اس كے جواب سے قاصر ہوں گے، صرف اور صرف معيار يہ ہوگا كہ يہ بات پركھي جائے كہ وہ مكتب اجتماعى كام يعني پىداواري آلات كے تكامل كے كس درجے اور كن شرائط كا مولود و مظہر ہے۔
نتائج
تاريخي ماديت كا نظريہ اپني جگہ چند ايسے نتائج كا حامل ہے، جو حكمت عملي اور اجتماعى عملي مقصد ميں موثر ہيں۔ تاريخي ميٹريالزم محض ايك ايسا فكرى اور نظري مسئلہ نہيں، جو معاشرتي رفتار و انتخاب ميں كوئي تاثير پىدا نہ كرے۔ آئيے اب ہم ديكھيں كہ ہم اس سے كيا نتائج حاصل كر سكتے ہيں:
۱۔ پہلا نتيجہ، معاشرے اور تاريخ كي ”شناخت“ سے متعلق ہے، ماديت تاريخ كے نزديك اجتماعى اور تاريخي واقعات كي شناخت اور ان كے تجزيئے كي بہترين اور مطمئن ترين راہ يہ ہے كہ ہم ان كي معاشي بنيادوں كي جانچ پڑتال كريں۔ تاريخي واقعات كي معاشي بنياد كے بغير ان كي پوري اور مكمل شناخت موثر نہيں، كيونكہ يہ بات فرض كر لي گئي ہے كہ تمام معاشرتي تبديلياں ماہيت كے لحاظ سے معاشي ہيں ہرچند كہ ظاہراً ان كي ماہيت ثقافتى، مذہبى يا اخلاقى ہو ۔
يعني يہ تمام چيزيں معلول اور نتيجہ ہيں، معاشرے كي اقتصادي اور مادي وضيعت كا۔پرانے حكماء بھي اس بات كے مدعي تھے كہ اشياء كي معرفت ان كے ايجاد كے اسباب و علل كي وسيلے سے، اعليٰ ترين اور مكمل ترين طرز معرفت ہے۔ پس يہ فرض كرلينے كے بعد كہ تمام اجتماعى تبديليوں كي بنياد معاشرے كي معاشي ساخت پر ہے۔ تاريخ كي معرفت كا بہترين راستہ اجتماعى و معاشي تجزيہ ہے۔ بعبارت ديگر جس طرح حقيقت اور ثبوت كے مرحلے ميں علت كو معلول پر تقدم اور ترجيح حاصل ہے، معرفت اور اثبات كے مرحلے ميں اسے تقدم اور ترجيح حاصل ہے۔ پس اقتصادي بنياد كي ترجيح عيني اور وجودي ترجيح نہيں بلكہ ذہنى، معرفتي اور اثباتي بھي ہے ۔
”تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو“ ميں اس مفہوم كي وضاحت ان الفاظ ميں كي گئي ہے:
”سماجي انقلابات كے تجزيئے ميں سماجي كشمكشوں كو ان كي سياسى، قانوني اور مكتبي شكل كو سامنے ركھ كر نہيں ديكھنا چاہيے بلكہ اس كے بر عكس پىداواري طاقتوں اور پىداواري تعلقات كے درميان تناقص كے رشتے سے ان كي وضاحت كرني چاہيے ۔“
ماركس نے حقيقتاً ہميں اس طرح كے فيصلوں سے باز ركھا ہے، كيونكہ اولاً يہ حقيقت بيني پر مبني نہيں ہوتے اور ان ميں معلول يعني سياسى، قانوني اور مكتبي شكلوں كو علت كي جگہ دے دي جاتي ہے، جو دراصل اقتصادي تناقضات اور تغيرات ہيں۔
ثانياً سطحي ہوتے ہيں كيونكہ وہ معاشرے كي گہرائي ميں اترنے اور حقيقي اسباب كو تلاش كرنے كي بجائے اس كي سطح پر رہ جاتے ہيں اور اسي چيز پر اكتفا كر ليتے ہيں جو فوري ان كے سامنے آتي ہے۔
ثالثاً وہم كي بنياد پر ہوتے ہيں كيونكہ عمارات جو تمام تر مكتبي ہوتي ہيں، سوائے توہم يعني نادرست تصوير كے كوئي حقيقت نہيں ركھتيں، ليكن موضوع كے حقيقي تجزئيے كي بجائے اس كي غلط تصوير سے وابستہ ہو جانا يقينا ہميں گمراہي كي طرف لے جائے گا۔ اس كے بعد كتاب (ماركس و اينجلز كے منتخب آثار) سے اس طرح نقل كيا گيا ہے:
”جس طرح كسي فرد كے بارے ميں اپنے بارے ميں اس كي اپني سوچ كے اعتبار سے فيصلہ نہيں كرتے، اسي طرح انسان كي اپنے بارے ميں آگاہي كے دور پريشاني كے بارے ميں بھي حكم نہيں لگانا چاہيے ۔“(۲۹)
ماركس كوشش كرتا ہے كہ آگہى، فكر اور جدت پسندي كے كردار كو عام طور پر وجود تكامل و ارتقاء سمجھاتا ہے، ختم كردے مثلاً ”سن سيمن“ جس كے بہت سے سے افكار سے ماركس نے استفادہ كيا ہے۔ تكامل ميں جبلتي جدت پسندي كے كردار كے بارے ميں لكھتا ہے:
”معاشرے دو طرح كي اخلاقى قوتوں كے طابع ہيں اور يہ دونوں قوتيں يكساں شدت اثر كي حامل ہيں اور باري باري اپنا اثر دكھاتي ہيں۔ ان ميں ايك قوت عادت ہے اور دوسري جدت پسندي۔ كچھ عرصے كے بعد عادتيں حتمي طور پر بري ہو جاتي ہيں اور يہي وہ وقت ہے، جب نئي چيزوں كي ضرورت محسوس ہوتي ہيں يہ ضرورت حقيقي انقلابى كيفيت كي تشكيل كرتي ہے ۔“(۳۰)
يا پھر ماركس كا دوسرا استاد پروڈن معاشروں كے تكامل ميں عقائد و افكار كے كردار پر اظہار خيال كرتے ہوئے كہتا ہے:
”قوموں كي سياسى صورتيں ان كے عقائد كا مظہر رہي ہيں۔ ان صورتوں كا تحرك، ان كا تغير اور ان كا زوال وہ عظيم الشان تجربات ہيں، جو ان افكار كي قدر و قيمت كو ہمارے لئے واضح كرتے ہيں اور بتدريج ان سے متعلق ابدي اور ناقابل تغير حقيقت رونما ہوتي ہے، ليكن ہم يہ ديكھتے ہيں كہ تمام سياسى ادارے لازماً حتمي موت سے بچنے كے لئے معاشرتي شرائط كو ہموار بنانے كے لئے اس كي طرف جھكتے ہيں ۔“(۳۱)
ان سب كے باوجود ماركس يہ دعويٰ كرتا ہے كہ:
”ہر سماجي انقلاب تمام چيزوں سے بڑھ كر ايك معاشي سماجي ضرورت ہے، جو معاشرے كي ماہيت و شكل اور پىدواري قوتوں اور اجتماعى روابط كي متضاد اور غير ہم آہنگ كيفيت كي وجہ سے پىدا ہوتي ہے ۔“(۳۲)
ماركس يہ كہنا چاہتا ہے كہ:
يہ جدت پسندي كي جبلت يا ايمان و عقائد كي ولولہ خيزي نہيں جو سماجي انقلابات كو جنم ديتي ہے بلكہ معاشى، سماجي ضرورت جدت پسندي كے رجحان يا عقائد اور ايمان كي ولولہ انگيزي كو پىدا كرتي ہے ۔“
پس ماديت تاريخ سے اس طرح كا نتيجہ اخذ كركے اگر ہم مثلاً يہ چاہيں كہ ايران و يونان كي لڑائي يا صليبي جنگوں يا اسلامي فتوحات يا مغرب كے صنعتي انقلاب يا پھر ايران كے دستوري انقلاب كا تجزيہ كريں تو يہ غلط ہوگا كہ ہم واقعات كي ظاہري صورتوں كو جو سياسى، مذہبى اور ثقافتي ہوتي ہيں، كا مطالعہ كرنے لگيں، اور ان پر حكم لگانے لگيں اور يا حتيٰ انقلاب لانے والے افراد كے احساس كو معيار قرار ديں، جو اسے سياسى، مذہبى يا ثقافتي تحريك سمجھتے تھے۔ ہميں چاہيے كہ ہم ان تحريكوں كي اس حقيقي ماہيت اور ہويت پر توجہ ديں، جو معاشي اور مادي ہے، تاكہ حقيقت كا اصلي رخ ہمارے سامنے آئے۔ آج بھي ہم ديكھتے ہيں كہ دور حاضر كے ماركسٹ بونے جس تاريخي تحريك كے بارے ميں كچھ كہنا چاہتے ہيں، كچھ نہ جانتے ہوئے بھي ادھر اُدھر سے چند جملے لے كر اس تحريك كے دور كے معاشي پہلو پر بحث فرمانے لگتے ہيں ۔
۲۔ تاريخ پر تسلط ركھنے والا قانون ايك جبرى، حتمي اور انسان اور انسان كے ارادے سے ماوراء قانون ہے۔ ہم پچھلے ابواب ميں اس موضوع پر گفتگو كر چكے ہيں كہ كيا تاريخ پر قوانين كي علت حكم فرما ہے؟ جس كا لازمہ ايك لحاظ سے علت و معلول كا ناگزير ہونا ہے، ہم وضاحت كر چكے ہيں كہ بعض نے اتفاق كے عنوان سے اور بعض نے اس عنوان سے كہ انسان ايك آزاد اور خودمختار مخلوق ہے۔ قانون عليت كي حكمراني كا انكار ہے اور اس كے نتيجے ميں معاشرے اور تاريخ كے لئے اس قانون اور ناقابل تغير ضوابط كي نفي كي ہے، ليكن ہم نے ثابت كيا ہے كہ يہ نظريے بے بنياد ہے اور قانون عليت اور اس كے نتيجے ميں معاشرے اور تاريخ پر علت و معلول كي ضرورت اسي طرح حكم فرما ہے جيسے ديگر امور پر۔ دوسري طرف ہم نے يہ ثابت كيا ہے كہ معاشرے اور تاريخ پر لاگو قوانين، ضروري اور كلي ہوتے ہيں كيوں كہ ان ميں حقيقي وحدت ہوتي ہے تو يہ حقيقي وجود كے حامل ہيں۔ پس گذشتہ بيان كے مطابق معاشرے اور تاريخ پر ”ضروري“ اور ”كلي“ قوانين حكم فرما ہيں۔ ہم اس نوعيت كي ضرورت كو اصطلاحاً فلسفي ضرورت كہتے ہيں۔ يہ ضرورت تاريخي عمل كو قطعي اور ضروري قوانين كے تحت جاري رہنے كا حكم ديتي ہے ۔
ليكن ماركسٹي جبر تاريخ جسے معاشي جبر بھي كہا جاتا ہے۔ فلسفي ضرورت كي ايك خاص تعبير ہے۔ يہ نظريہ دو اور نظريوں سے مل كر بنا ہے۔ جن ميں سے ايك فلسفي ضرورت ہي ہے جس كے مطابق كوئي واقعہ بغير ضرورت (يعني ضروري ہونے) كے وقوع پذير نہيں ہوتا۔ وقوع ميں آنے والا ہر واقعہ اپنے خاص پىدائشي اسباب كي بنياد پر حتمي اورناقابل اجتناب امر ہے اور اگر وہ علل نہ ہوتيں، تو محال اور ممتنع ہوتا۔ دوسرا نظريہ معاشرے كي مادي بنياد كا ديگر بنيادوں پر مقدم ہونا ہے، جس كي ہم وضاحت كر چكے ہيں۔ ان دونظريوں كا لازمہ تاريخ كا مادي جبر ہے يعني ناگزير ہے كہ عمارت بنياد كے مطابق ہو، بنياد بدل جائے تو عمارت كا بدلنا قطعي و حتمي ہے، اگر بنياد تبديل نہ ہو تو ناممكن ہے كہ عمارت بدل جائے، ماركسزم كے دعوے كے مطابق وہ چيز جو ماركسزي سوشلزم كو سائنسي بنا ديتي ہے اور عالم طبيعت كے ديگر قوانين كي طرح كا ايك طبيعي قانون بنا ديتي ہے، وہ يہي اصول ہے كيوں كہ اس اصول كے مطابق پىداواري آلات جو معاشرے كي معاشي ساخت كا سب سے اہم حصہ ہيں، طبيعي قوانين كے مطابق اپني ترقي اور پىشرفت كو جاري ركھتے ہيں۔ بالكل اسي طرح جس طرح مختلف پودوں اور حيوانات نے كئي سو كروڑ ملين سال كے تاريخي تسلسل كے دوران اپني تدريجي ترقي كو جاري ركھا اور خاص مراحل ميں نئي نوع ميں داخل ہوئے اور جس طرح پودوں اور جانوروں ميں رشد و كمال اور نوعي تبديلي كا عمل كسي كے ارادے، خواہش اور آرزو سے آزاد ہے، اسي طرح پىداواري آلات كے رشد و تكامل كي بھي يہي صورت ہے ۔
پيداواري آلات اپني تدريجي ترقي كے ساتھ كچھ مراحل طے كرتے ہيں اور جس مرحلے پر بھي پہنچتے ہيں جبراً اپنے ساتھ معاشرے كے تمام امور كو بھي بدل ديتے ہيں اور كوئي ان كا راستہ نہيں روك سكتا اور قبل اس كے كہ وہ اپني ترقي كے خاص مرحلے تك پہنچيں، سماجي ڈھانچے ميں تبديلي يا انقلاب ممكن نہيں تمام سوشلسٹ بلكہ كلي طور پر ہر وہ انصاف پسند انسان جو ان امكانات كو مدنظر ركھے بغير جو پىداواري آلات كي ترقي سے پىدا ہوتے ہيں، صرف انصاف كے قيام، جو سوشلزم اور معاشرے كو اجتماعى شكل دينے كے جذبے اور آرزو كو لے كر كوششوں ميں مصروف ہے، عبث كام انجام ديتا ہے۔ كارل ماركس ”سرمايہ“ نامي كتاب كے مقدمے ميں لكھتا ہے:
”وہ ملك جس نے صنعت كے اعتبار سے سب سے زيادہ پىش رفت كي ہے، ان ملكوں كے مستقبل كے لئے ايك نمونہ ہے، جو صنعت كے ميدان ميں اس سے پىچھے ہوں(۳۳)
حتيٰ اگر كوئي معاشرہ اس مرحلے تك پہنچ جائے كہ وہ اپني حركت پر حكمراني كرنے والے قانون طبيعت كي راہ بھانپ لے تو جب بھي وہ نہ تو اپني طبيعي پىش رفت سے متعلق مراحل كو پھلانگ سكے گا اور نہ ہي صدور فرامين كے ذريعے انہيں ختم كر سكے گا، ليكن وہ حاملگي كے دور اور پىدائش كي اذيت كو كم تر اور خفيف كر سكتا ہے۔“
ماركس اپني گفتگو كے آخري حصے ميں ايك ايسے نكتے كو پىش كرتا ہے جس كي طرف يا تو توجہ نہيں كي گئي يا بہت كم لوگوں نے اسے سمجھنے كي كوشش كي ہے، وہ دراصل ايك مفروضہ، سوال يا اعتراض كا جواب دينا چاہتا ہے ۔
ممكن ہے كوئي يہ كہے طبيعت كي منظم اور مرحلہ وار پىش رفت كے زير اثر معاشرے كي درجہ بدرجہ پىش رفت اس وقت تك جبري اور تخلف ناپذير ہے جب تك انسان اسے نہ پہچانے اور قانون طبيعي كے راستے كو كشف نہ كرے۔ ليكن جونہي انسان كو اس كا علم ہو گيا، يہ انسان كے قابو ميں آجائے گي اور انسان كو اس پر حكومت حاصل ہوجائے گى، لہٰذا كہتے ہيں: طبيعت جب تك سمجھ ميں نہ آئے انسان پر حاكم ہے اور جس قدر اس كي شناخت ہوجائے اسي قدر انسان كي خدمت گذار بن جاتي ہے۔ مثلاً كوئي وبائي بيماري جب تك مشخص نہ ہو اور يہ معلوم نہ ہو كہ كن چيزوں سے وجود ميں آتي ہے اور كن چيزوں سے اسے ختم كيا جا سكتا ہے، اس وقت تك انسان كي زندگي پر حكم علي الاطلاق ہوتي ہے، ليكن جونہي اس كي شناخت عمل ميں آئي جيسا كہ آج كل پہچاني جاتي ہے، وہيں اس پر قابو پاليا جاتا ہے، ايسي بيماريوں كے نقصانات سے بچا جا سكتا ہے۔ يہي صورت سيلاب اور طوفان وغيرہ كي بھي ہے۔
ماركس يہ كہنا چاہتا ہے كہ معاشرے كي منظم اور مرحلہ وار پىش رفت ڈائنا ميكي تغيرات اورحركات كي طرح ہے، يعني جو اشياء ميں اندروني طور پر خود بخود پىدا ہونے والي حركات ہيں۔ جيسے پودوں اور جانوروں كي منظم نشوونما، يہ ميكانياتي حركات و تغيرات ميں سے نہيں ہيں جو بيروني عوامل كے تحت اشياء ميں پىدا ہوتي ہيں، جيسے عالم طبيعت ميں تمام فني اور صنعتي تغيرات ہيں۔ كيڑے مار دواؤں كے ذريعے كيڑوں كا خاتمہ يا دوا كے ذريعے بيماري كے جراثيم كا خاتمہ اسي طرح كي چيز ہے۔ وہ مقام جہاں طبيعي قانون كي دريافت طبيعت كو كنٹرول كرنے كا سبب بنتي ہے اور انسان كے اختيار ميں آتي ہے۔ ميكانياتي روابط اور قوانين ہوتے ہيں ليكن ڈائناميكل تبديليوں اور اشياء كي اندروني اور ذاتي حركات كے بارے ميں انسان كے علم و آگاہي كا كردار زيادہ سے زيادہ يہ ہے كہ انسان اپنے آپ كو ان قوانين سے ہم آہنگ كر كےان سے استفادہ كرے ۔
انسان پودوں كے اگنے، جانوروں كے تكامل اور رحم ميں جين پر حكم فرما قوانين كو دريافت كرنے كے بعد ايسے جبري اور ناقابل انحراف قوانين كو اخذ كر ليتا ہے، جن كے سامنے گردن جھكانے اور جنہيں تسليم كرنے پر وہ مجبور ہے۔ ماركس كہنا چاہتا ہے كہ انسان كي معاشرتي پىش رفت جس كا انحصار پىداواري آلات كي ترقي اور تكامل پر ہے۔ ايك طرح كے ڈائنامك اندرونى، ذاتي اور خود بخود ہونے والي ترقي ہے، جسے علم و آگاہي كے ذريعے نہيں بدلا جا سكتا اور جسے اپني مرضي كي شكل نہيں دي جا سكتي۔ انسان كو جبراً سماجي تكامل كے خاص مراحل سے اسي طرح گذرنا پڑتا ہے جس طرح نطفہ رحم مادر ميں مقرر اور معين مراحل سے گذرتا ہے۔ اس خيال كو ذہن سے نكالنا پڑے گا كہ ہم معاشرے كو وسطي مراحل سے نكال كر ايك دم آخري مرحلے تك لے جا سكيں گے يا يہ كہ اسے تاريخ كے بتائے ہوئے معين راستے سے ہٹا كر دوسري راہوں سے منزل مقصود تك پہنچا سكيں گے۔ ماركسزم سماجي تكاملي رفتار كو ايك نا آگہانہ طبيعي اور جبري رفتار جاننے كے باعث ايسي بات كرتا ہے، جيسي سقراط نے ذہن بشر اور اس كي تخليق فطري كے بارے ميں كي تھي۔ سقراط اپني تعليمات ميں استفہامي روش سے استفادہ كرتا تھا او راس بات كا معتقد تھا كہ اگر سوالات مرحلہ بمرحلہ منظم اور ذہني عمل كي مكمل شناخت كے ساتھ ہو تو ذہن اپني فطري اور قہري حركت كے ذريعے خود ہي اس كا جواب فراہم كرتا ہے اور باہر سے تعليم كي ضرورت پىش نہيں آتي۔ سقراط ايك دايہ كا بيٹا تھا، وہ كہتا تھا:ميں انسان كے ساتھ وہي كچھ كرتا ہوں، جو مير ماں حاملہ عورتوں كے بارے ميں انجام ديتي تھي۔ دايہ بچے كو نہيںجناتي ماں كي طبيعت خود اپنے وقت پر بچے كو جنم ديتي ہے۔ اس كے باوجود دايہ كا وجود ضروري ہے۔ دايہ خيال ركھتي ہے كہ كوئي غير طبيعي واقعہ رونما نہ ہو، جو ماں يا بچے كي تكليف كا باعث ہے ۔
ماركسزم كے اعتبار سے اگرچہ عمرانيات كے قوانين كي دريافت اور فلسفہ و تاريخ دونوں كا معاشرت كي تبديلي پر كوئي اثر نہيں، پھر بھي انہيں اہميت ديني چاہيے۔ سائنٹفك سوشلزم انہي قوانين كي دريافت كا نام ہے۔ كم سے كم جو اثر ان سے رونما ہوتا ہے، وہ يہ ہے كہ يہ تخيلي سوشلزم اور خواہشاتي عدل پرستي سے نجات ديتا ہے، كيونكہ ڈائنامك قوانين اس خصوصيت كے باوجود كہ ان سے تبديلي ناممكن ہے، ايك امتياز كے حامل ہيں اور وہ امتياز پىش گوئي ہے۔ سائنٹفك عمرانيات اور سوشلزم كے پرتو ميں ہر معاشرے كي وضيعت كو پركھا جا سكتا ہے كہ وہ كس مرحلے ميں ہے اور اس كے بارے ميں پىش گوئي كي جا سكتي ہے اور نتيجاً يہ معلوم ہو سكتا ہے كہ سوشلزم كا نطفہ ہر معاشرے كے رحم ميں كس مرحلے ميں ہے اور ہر مرحلہ ميں وہي توقع كي جاني چاہيے، جو اس كا تقاضا ہے اور بے جا توقعات نہيں كرنا چاہيے۔ ايك ايسي سوسائٹي جو ابھي جاگير دارانہ نظام كے مرحلے ميں ہے اس سے يہ توقع نہيں ركھنا چاہئے كہ وہ سوشلزم ميں منتقل ہو جائے، بالكل اسي طرح جس طرح چار مہينے كے جين كي پىدائش كے انتظار ميں نہيں بيٹھا جاتا ۔
ماركسزم كي يہ كوشش ہے كہ وہ معاشروں كي قدرتي مخفي توانائي كے مراحل كو سمجھے اور ان كا تعارف كروائے اور معاشروں كو ايك دور سے دوسرے دور ميں بدلنے كے جبري قوانين دريافت كرے ۔
ماركسزم كے نظريے كے مطابق معاشروں كو چار مراحل سے گذر كر سوشلزم تك پہنچنا پڑتا ہے۔ ابتدائي اشتراكي دور، دور غلامى، دور سرمايہ داري اور دور سوشلزم بعض اوقات چار كے بجائے پانچ، چھ يا سات دور بھي ذكر كئے جاتے ہيں، يعني دور غلامى، دور سرمايہ داري اور دور سوشلزم ميں سے ہر دور مزيد دو ادوار ميں تقسيم ہو سكتا ہے ۔
۳۔ ہر تاريخي دور دوسرے دور سے با اعتبار ماہيت و نوعيت مختلف ہے، جس طرح بيالوجي كے اعتبار سے جانور ايك نوع سے دوسري نوع ميں بدل جاتے ہيں اور ان كي ماہيت تبديل ہوجاتي ہے۔ ادوار تاريخي بھي يہي كيفيت لئے ہوئے ہيں۔ اس رو سے ہر تاريخي دور اپنے سے متعلق مخصوص قوانين كا حامل ہے۔ كسي دور كے لئے اس سے قبل كے دور يا اس كے بعد كے دور كے قوانين كو اس كے مناسب حال نہيں جاننا چاہيے۔ جيسے پانى جب تك پانى ہے، مائعات سے متعلق خاص قوانين كے تابع ہے، ليكن جونہي وہ بھاپ ميں تبديل ہوا، وہ گذشتہ قوانين كے تابع نہيں رہتا بلكہ اب وہ گيسوں سے متعلق مخصوص قوانين كے تابع ہو جاتا ہے۔ معاشرہ بھي مثلاً جب تك فيوڈلزم كے مرحلے ميں ہوتا ہے، خاص قوانين سے اس كي وابستگي ہوتي ہے اور جب اس مرحلے سے گذر كر سرمايہ داري كے مرحلے ميں قدم ركھتا ہے تو پھر جاگير دارانہ نظام كے دور كے قوانين كو اس كے لئے باقي ركھنے كي كوشش كرنا فعل عبث ہے ۔
اس اعتبار سے معاشرہ ايك ہي طرح كے ابدي اور جاوداني قوانين كا حامل نہيں ہو سكتا۔ تاريخي ميٹريالزم اور معاشرے كي بنياد اقتصادي ہونے كي بناء پر جاودانيت كا دعويٰ كرنے والا ہر قانون ناقابل قبول ہے اور يہي وہ جگہ ہے، جہاں تاريخي ماديت اور مذہب كي آپس ميں نہيں بنتى، خاص طور پر اسلام سے جو بعض جاوداني قوانين كا قائل ہے ۔
كتاب ”تجديد نظر طلبي“ ميں ”سرمايہ“ كے دوسرے ايڈيشن كے ملحقات سے نقل كيا گيا ہے كہ
”ہر تاريخي دور، اپنے سے متعلق خاص قوانين كا حامل ہوتا ہے۔جونہي زندگي ايك مرحلے سے دوسرے مرحلے ميں پہنچتي ہے، دوسرے قوانين اس پر لاگو ہوتے ہيں۔ معاشي زندگي اپني تاريخي پىش رفت ميں وہي صورت اختيار كرتي ہے، جيسے ہم بيالوجي كي ديگر شاخوں ميں پاتے ہيں ۔۔۔ معاشرتي آرگنزم اسي طرح ايك دوسرے سے مختلف و ممتاز ہوتے ہيں، جس طرح حيواني اور نباتاتي آرگنزم ۔“(۳۴)
۴. پيداواري آلات كي پىش رفت اس بات كا باعث بني كہ آغاز تاريخ ميں اختصاصي مالكيت وجود ميں آئي اور معاشرہ استحصال كرنے والے اور ہونے والے دو طبقوں ميں منقسم ہوگيا اور يہ دو طبقے ابتدائي تاريخ سے اب تك معاشرے كے دو بنيادي قطب ( Pole ) بنے ہوئے ہيں۔ ان دو طبقوں كے درميان تضاد و كشمكش كا ايك دائمي سلسلہ جاري ہے۔ البتہ معاشرے كے دو قطبي ہونے كا يہ مطلب نہيں كہ تمام كے تمام گروہ لازماً يا استحصال كرنے والے يا ہونے والے ہيں، ممكن ہے ان ميں ايسے گروہ بھي ہوں، جو نہ استحصال كنندہ ہوں نہ استحصال يافتہ۔ مقصد يہ ہے كہ معاشروں كي تقدير ميں موثر واقعہ ہونے والے يہي وہ دو گروہ ہيں، جو دو اصلي قطب ہيں۔ باقي تمام گروہ ان دو اصلي گروہوں ميں سے ايك كي پىروي كرتے ہيں ۔
”تجديد نظر طلبي“ ميں ہے:
”ماركس اور اينجلز كے پاس معاشرے ميں طبقات كي تقسيم اور ان كي آويزش سے متعلق ہميں دو طرح كے نمونے ملتے ہيں، ايك دو قطبي اور دوسرا كئي قطبي۔ طبقے كي تعريف ان دونوں نمونوں ميں مختلف ہے۔پہلے نمونے ميں طبقہ مزاجي اور دوسرے ميں حقيقي ۔“(۳۵)
طبقہ كے پى دائشي ضوابط بھي مختلف ہيں۔ اينجلز ”جرمني كے كاشت كاروں كي جنگ“ كے مقدمے ميں ان دونوں نمونوں كي آپس ميں دوستي كروانے اور ان سے ايك ہم جنس نمونہ بنانے كي كوشش كرتا ہے۔ وہ معاشرے ميں متعدد طبقات اور ان طبقات ميں مختلف گروہوں كي تشكيل كرتا ہے، ليكن اس كے عقيدہ كے مطابق ان طبقوں ميں سے فقط دو طبقے قطعي تاريخي ذمہ داري كو پورا كر سكتے ہيں۔ ايك ”بورژوائي“ (سرمايہ دارانہ نظام) اور دوسرا ”پرولتاريائي“ (مزدورانہ نظام) كيونكہ يہ دونوں طبقے حقيقتاً معاشرے كے متضاد قطب ہيں۔(۳۶)
ماركسزم كے فلسفہ كے مطابق جس طرح يہ بات محال ہے كہ معاشرے كي عمارت اس كي بنياد پر مقدم ہو، اسي طرح يہ بات بھي محال ہے كہ معاشرہ كي بنياد (يعني معاشى، معاشرتي اور مالكيت سے متعلق تعلقات) كے اعتبار سے استحصال گر اور استحصال شدہ دو طبقوں ميں تقسيم ہو اور عمارت كے اعتبار سے اس ميں وحدت باقي رہے۔ معاشرتي وجدان بھي اپني جگہ دو حصوں ميں تقسيم ہوگا، ايك استحصال گر وجدان اور دوسرا استحصال شدہ اور اس اعتبار سے معاشرے ميں دو تصور كائنات دو آئيڈيالوجىز، دو اخلاقى نظام اور دو قسم كا فلسفہ وجود ميں آئے گا ۔
كوئي طبقہ، وجدان، ذوق اور طرز فكر كے اعتبار سے اپنے معاشي موقف پر سبقت نہيں لے جا سكتا۔ صرف جو چيز دو قطبي نہيں ہوگي وہ استحصال گر طبقے كے مختصات ميں سے ہے۔وہ ايك ”دين“ اور دوسري ”حكومت“ ہے۔ دين اور حكومت استحصال شدہ طبقہ پر تسلط جمانے كے لئے استحصال گر طبقہ كي خاص ايجادات ہيں۔ استحصال گر طبقہ معاشرے كے مادي ذرائع كا مالك ہونے كے اعتبار سے اپنے كلچر كو جس ميں مذہب بھي شامل ہے۔ ، استحصال شدہ طبقے پر ٹھونستا ہے۔ اس رو سے ہميشہ حاكم ثقافت يعني حاكم تصور كائنات، حاكم آئيڈيالوجى، حاكم اخلاق، حاكم ذوق و احساس اور سب سے بڑھ كر حاكم مذہب استحصال گر طبقے ہي كي ثقافت ہوا كرتا ہے۔ استحصال شدہ طبقے كي ثقافت اسي كي طرح ہميشہ محكوم ہوتي ہے، اس كي ترقي اور راہوں كو روك ديا جاتا ہے۔ ماركس ”جرمن آئيڈيالوجى“ ميں كہتا ہے:
حاكم افكار، حاكم مادي تعلقات كے دانش مندانہ بيان سے ہٹ كر كوئي شے نہيں، يعني مادي تعلقات بزبان افكار، يعني وہي روابط جنہوں نے اس طبقے كو حاكم بنايا ہے۔ اس كي حاكميت كے افكار، وہ افراد جو حكمران طبقہ سے تعلق ركھتے ہيں۔ ديگر چيزوں كے علاوہ ان كے پاس آگاہي بھي ہوتي ہے، لہٰذا وہ سوچتے بھي ہيں جب تك ان كي حكومت ہے، وہ عصر تاريخ كا تعين بھي كرتے ہيں۔ واضح رہے كہ يہ كام وہ تمام سطحوں پر انجام ديتے ہيں، يعني علاوہ ديگر چيزوں كے چونكہ سوچنے والے اور افكار كي تخليق كرنے والے حكومت كر رہے ہوتے ہيں اور ان كے افكار وقت كے حاكم افكار ہوتے ہيں۔“(۳۷)
حاكم اور استحصال گر طبقہ بالذات، رجعت پسند، قدامت پسند اور روايت پرست ہوتا ہے اور اس كا كلچر بھي حاكم اور ٹھونسا ہوا كلچر ہوتا ہے، جو ايك رجعت پسندانہ اور روايت پرستانہ كلچر ہوتا ہے، ليكن استحصال شدہ طبقہ بالذات انقلابى، جمود شكن، پىش قدم اور مستقبل پر نظر ركھنے والا ہوتا ہے اور اس كا كلچر بھي محكوم ہوتا ہے جو ايك انقلابى، روايت شكن اور مستقبل پر نظر ركھنے والا كلچر ہوتا ہے۔ انقلابى ہونے كي لازمي شرط استعمار شدگي ہے يعني صرف يہي طبقہ ہے جو انقلابى بننے كي استعداد ركھتا ہے ۔
”تجديد نظر طلبي“ ميں اينجلز كي اس عبارت كے بعد جو ”جرمن ميںكاشت كاروں كي جنگ“ كے مقدمہ سے منقول ہے، لكھتا ہے:
”اس كے مقدمہ كے چھپنے كے ايك سال بعد جرمن سوشلسٹوں كي انجمن نے گواہ ميں اپنے ايك پروگرام ميں لكھا كہ مزدور كے مقابل تمام طبقے ايك رجعت پسند گروہ ہيں۔
ماركس نے اس جملے پر بڑي شدت سے تنقيد كى، ليكن اگر ہم حقيقت پسندي سے كام ليں تو ہميں يہ اعتراف كرنا ہوگا كہ ماركس نے جو كچھ اپنے قول ميں كہا تھا، يہ بيچارے سوشلسٹ چونكہ اس كے دو قطبي اور كئي قطبي نمونے كے درميان فرق كو سمجھنے سے قاصر تھے، اس لئے وہي كچھ كہہ سكتے تھے، جو انہوں نے كہا ہے اور اس كے علاوہ كوئي اور فيصلہ نہيں كر سكتے تھے، ماركس نے (كميونسٹ پارٹي كے منشور سے متعلق) بيان ميں طبقات كي موجودہ جنگ كو پرولتاريائي اور بورژوائي طبقات كي آپس ميں جنگ سے مماثلت دي تھي اور كہا تھا كہ ان طبقات كے درميان جو بورژوائي كے مخالف ہيں، صرف پرولتاريائي ايسا طبقہ ہے، جو حقيقتاً انقلابى ہے ۔“(۳۸)
ماركس نے بعض مقامات پر كہا كہ صرف پرولتاري طبقہ ايسا ہے جواپنے اندرانقلابي ہونے كي تمام شرائط اور خصوصيات ركھتا ہے اور وہ شرائط و خصوصيات يہ ہيں:
۱) استحصال شدگي جس كے لئے ضروري ہے كہ وہ طبقہ پىداوار دينے والا بھي ہو ۔
۲) مالكيت نہ ركھنا(يہ اور پہلي خصوصيت كسانوں كے بھي شامل حال ہے)۔
۳) تنظيم جس كا لازمہ ايك مركزيت ہے (يہ خصوصيت پرولتاري طبقہ كے لئے مخصوص ہے، جو ايك كارخانے ميں باہمي تعاون سے كام كرتا ہے، ليكن كسان اس خصوصيت ميں شامل نہيں ہيں، كيوں كہ وہ زمين كے مختلف حصوں ميں بٹے اور بكھرے ہوئے ہيں)۔
ماركس نے دوسري خصوصيت كے بارے ميں كہا ہے، مزدور دو اعتبار سے آزاد ہے: ”ايك قوت كار بيچنے كے اعتبار سے اور دوسرے ہر طرح كي مالكيت سے آزاد ہے ۔“
پھر تيسري خصوصيت كے بارے ميں ايك بيان ميں كہتا ہے:
”صنعت كي ترقي يہي نہيں كہ پرولتار ياؤں كي تعداد كو بڑھاتي ہے بلكہ انہيں قابل توجہ عوامي گروہ كي صورت ميں متمركز بھي كرتي ہے، ان كي طاقت كو بڑھاتي ہے اور وہ خود بھي اپني طاقت كو سمجھنے لگتے ہيں ۔“(۳۹)
مذكورہ بالا اصول كو ”آئيڈيالوجي كي بنياد او ر طبقاتي و اجتماعى بنياد كے درميان اصول مطابقت“ كا نام ديا جا سكتا ہے اور اصول كي بنياد پر ہر طبقہ ايك خاص طرح كي سوچ، فكر، اخلاق، فن اور شعر و ادب وغيرہ كي تخليق كرتا ہے، جو اس كي زندگى، معاش اور اس كے مفادات كي كيفيت كا تقاضا كرتي ہے۔ اسي طرح ہم اس اصول كو ”ہر فكر و نظر كي آرزو اور اس فكر و نظر كي سمت كے درميان اصول مطابقت“ كا نام بھي دے سكتے ہيں، يعني ہر فكر و نظر اور ہر اخلاقى يا مذہبى سسٹم جو كسي بھي طبقے سے ابھرتا ہے، اسي طبقے كے مفاد ميں ہوتا ہے، محال ہے كہ كسي طبقے كا كوئي فكرى سسٹم كسي دوسرے طبقے كي خير و صلاح اور فائدے ميں يا پھر كسي طبقے سے انسانيت كي خير و صلاح ميں كوئي فكرى نظام ابھرے اور كوئي خاص طبقاتي رجحان اس ميں نہ ہو، فكر و نظر ميں اس وقت انسانيت كا پہلو اور طبقات سے ماورائيت ہو سكتي ہے، جب پىداواري آلات كا تكامل سب طبقات كي نفي كا متقاضي ہو، يعني طبقاتي بنياد كے تضاد كي نفي سے ہي آئيڈيالوجىز كے تضاد كي نفي ہوگي اور فكرى مطمع نظر كے تضاد كي نفي سے ہي فكرى سمتوں كے تضاد كي نفي ہوگي ۔
ماركس اپني جواني كے زمانے كي بعض تحريروں (مثلاً ہيگل كے ”فلسفہ قانون پر انتقاد“ كے مقدے) ميں طبقات كے معاشي پہلو (منافع طلبي اور منافع دہي) سے زيادہ ان كے سياسى پہلو (فرمانروائي اور فرمانبرداري) كا زيادہ قائل تھا اور اسي لئے اس نے طبقاتي كشمكشوں كي ماہيت كو آزادى اور ظلم سے نجات كي جنگ سے تعبير كيا ہے۔ اس جنگ كے لئے اس نے دو مرحلوں كا ذكر كيا ہے:
ايك جزوي اور سياسى مرحلہ اور دوسراكلي اور انساني مرحلہ۔وہ كہتا ہے كہ پرولتاريائي انقلاب جو ”تاريخ كے قيديوں“ كا آخري مرحلہ انقلاب ہے، بنيادي اہميت كا حامل ہے، يعني يہ وہ انقلاب ہے، جو انسان كو مكمل آزادى بخشنے، فرمانروائي اور غلامي كي تمام شكلوں كو مٹانے كے لئے وجود ميں آتا ہے۔ ماركس اس مفہوم كي توجيہ ميں كہ كس طرح ايك طبقہ اپنے اجتماعى موقف ميں اپنے طبقاتي موقف سے آگے بڑھتا ہے اور اس كا مقصد كلي اور انساني بن جاتا ہے، جو تاريخي ميٹريالزم كے مطابق بھي درست ہے، اس طرح بيان كرتا ہے كہ چونكہ اس طبقے كي قيد اور غلامي بنيادي ہے، لہٰذا اس كا انقلاب بھي بنيادي ہے۔ اس طبقے پر بطور خاص ناانصافي نہيں ہوئي بلكہ ناانصافي اس پر مسلط ہوئي ہے ۔
اس رو سے وہ بھي صرف انصاف اور انسان كي نجات كا خواستار ہے، يہ بيان اولاً ”شاعري“ ہے سائنسي نہيں۔ ”بس نا انصافي اس پر مسلط ہوئي ہے“ كا مفہوم كيا ہے؟ كيا استحصال گر طبقہ قبلاً اپنے طبقے سے كسي طرح آگے بڑھ گيا اور اس نے ظلم كو حصول مفاد كے لئے نہيں بلكہ ظلم كي خاطر اور ناانصافي كو استحصال كے لئے نہيں بلكہ نا انصافي كي خاطر چاہا كہ پرولتاريائي طبقہ اس كے رد عمل ميں صرف انصاف كا خواہاں ہو؟
مزيد بر آں بالفرض استحصال گر طبقہ، سرمايہ داري كے دور ميں ايك ايسي صورت اختيار كر ليتا ہے، جو تاريخي ميٹريالزم سے ٹكراتي ہے اور يہ ايك طرح كا مثاليت پسندانہ ( Idealistic ) نظريہ ہے۔ ”مكتبي اور طبقاتي بنياد كے درميان مطابقت“ كا اصول اس بات كا متقاضي ہے كہ كسي فكر كے مطمع نظر اور اس كي سمت كے درميان مطابقت ہو، نيز يہ بھي كہ كسي فرد كا كسي عقيدے كي طرف جھكاؤ اس فرد كے طبقاتي ميلانات كے ساتھ مطابقت ركھتا ہو، يعني ہر فرد كا طبيعي ميلان اسي مكتب فكر كي جانب ہوتا ہے، جو اس كے اپنے طبقے سے ابھرتا ہے اور اس مكتب كو اپنانا اس كے اپنے طبقے كے مفاد ميں ہے ۔
ماركسسي منطق كے مطابق يہ اصول معاشرتي شناخت ميں يعني آئيڈيالوجى كي ماہيت كي شناخت اور ميلانات كے اعتبار سے سماجي طبقات كي شناخت ميں غير معمولي طور پر مفيد اور رہنما ہے۔
۵۔ تاريخي ميٹريالزم كا پانچواں نتيجہ يہ ہے كہ آئيڈيالوجى، دعوت وتبليغ اور پند و نصائح جيسے امور كا كردار معاشرے يا طبقاتي سماج كو كوئي جہت دينے ميں بہت محدود ہے، عام طور پر يہ خيال كيا جاتا ہے كہ مكتب، دعوت، برہان، استدلال، تعليم و تربيت، تبليغ، موعظہ اور نصيحت انسان كے وجدان كو مرضي كے مطابق ڈھال سكتے ہيں۔ يہ بات سامنے ركھتے ہوئے كہ ہر فرد، ہر گروہ اور ہر طبقے كا وجدان سماجي اور طبقاتي موقف كا بنايا ہوا ہے اور درحقيقت اس كے طبقاتي موقف كا جبري اور لازمي انعكاس ہے اور اس سے آگے يا پىچھے نہيں ہوسكتا، يہ سوچ كہ بنياد كے اوپر كي عمارت سے متعلق مسائل جن كا ابھي تذكرہ ہو چكا ہے، سماجي انقلاب كا مبداء بن سكتے ہيں، معاشرے اور تاريخ كے بارے ميں ايك آئيڈيالسٹك تصور ہے اور اس كا مفہوم يہ ہے كہ كہا جائے كہ ”روشن فكرى“، ”اصلاح طلبي“ اور”انقلابي ہونا“، ”خود انگيختي“ كا پہلو ركھتا ہے، يعني طبقاتي محروميت خودبخود روشن فكرى، اصلاح طلبي اور انقلابى ہونا ہے اور بيروني تعليم و تربيت وغيرہ كا اس ميں كوئي دخل نہيں ہوتا، كم از كم يہ بات كہي جا سكتي ہے كہ ان امور كي حقيقي داغ بيل طبقاتي موقف سے خودبخود پڑتي ہے۔ آئيڈيالوجى، رہنمائي اور باقي تمام روشن فكرانہ باتوں كا زيادہ سے زيادہ كردار يہ ہے كہ وہ طبقاتي تضاد اور درحقيقت محروم طبقے كے طبقاتي موقف كو ان سے متعارف كروائے اور بس۔ بتعبير ديگر ان كي اپني اصطلاح ميں ”طبقہ في نفسہ“ كو يعني اس طبقے كو جو اپني ذات ميں خاص طبقہ ہے۔ ”طبقہ لنفسہ“ ميں تبديل كرے يعني اس طبقے ميں تبديل كرے، جو اس كے علاوہ طبقاتي آگاہي بھي ركھتا ہو۔ بہرحال وہ تنہا فكرى ليور ( Lever ) جو طبقاتي معاشرے ميں كسي طبقے كو انقلاب كے لئے ابھار سكتا ہے، طبقہ كے اپنے موقف اور اپنے استحصال كے بارے ميں آگاہي ہے ليكن ان طبقاتي معاشروں ميں جہاں انسان استحصال گر اور استحصال شدہ گروہوں ميں بٹا ہوا ہے اور ہر گروہ ايك طرح سے اپنے آپ سے بيگانہ بنا بيٹھا ہے اور معاشرتي وجدان دو حصوں ميں بٹ گيا ہے، عدالت پسندي اور انسان دوستي جيسے انساني اصول كوئي كردار ادا نہيں كر سكتے ۔
ہاں البتہ جس دم پىداواري آلات كا تكامل جبراً پرولتاريائي حكومت كو جنم دے، طبقات معدوم ہو جائيں، انسان خود اپني حقيقت كو طبقاتي سرحدوں سے الگ ہو كر پالے اور مالكيت سے دو حصوں ميں تقسيم ہونے والا وجدان اپني وحدت كو حاصل كر لے، تب انسان دوستي كے فكرى اصول جو پىداواري آلات كي اشتراكي صور ت كے آئينہ دار ہيں اپنا كردار ادا كر سكتے ہيں، پس جس طرح تاريخي ادوار كے اعتبار سے سوشلزم كو جو ايك خاص تاريخي دور سے ابھرنے والي حقيقت ہے، اپني مرضي كے مطابق آگے يا پىچھے كے دور ميں نہيں لايا جا سكتا (جيسا كہ خيالي پلاؤ پكانے والے سوشلسٹ اس امر كے خواہاں تھے) اسي طرح ايك خاص تاريخي دور ميں بھي جہاں معاشرہ دو طبقوں ميں تقسيم ہے، كسي طبقے كي مخصوص آگاہي كو دوسرے طبقے پر نہيں ٹھونسا جا سكتا اور مشترك انساني آگاہي كا كوئي وجود نہيں ہوتا ۔
لہٰذا طبقاتي معاشرے ميں وہ عام اور كلي آئيڈيالوجى نہيں ابھر سكتي جو طبقاتي موقف كي حامل نہ ہو، ہر وہ آئيڈيالوجى جو طبقاتي معاشرے ميں ظہور پذير ہوتي ہے، بہرحال كوئي نہ كوئي طبقاتي رنگ ضرور ركھتي ہے اور نہ بفرض محال وجود پذير ہوتو عملاً كوئي كردار ادا كر سكتي ہے۔ اس اعتبار سے مذاہب و اديان كي تبليغات يا كم از كم وہ باتيں جو اديان و مذہب كے نام پر بصورت ہدايت و تبليغ يا پند و نصيحت كي جاتي ہيں اور جن ميں انصاف پسندى، عدل خواہى، انصاف طلبي اور انساني مساوات كا پىغام ہوتا ہے، اگر فريب نہيں تو كم از كم خيالي اور تصوراتي ضرور ہے ۔
۶۔ ايك اور نتيجہ جسے ترتيب كے ساتھ آنا چاہيے، يہ ہے كہ ليڈروں، مجاہدوں اور انقلابى رہنمائوں كا مركز آرزو جبراً اور لازماً استحصال شدہ طبقہ ہے ۔
اب جبكہ يہ بات پايہ ثبوت كو پہنچي كہ صرف استحصال شدہ طبقہ ہي وہ طبقہ ہے، جو روشن فكرى، اصلاح طلبي اور انقلاب كے لئے آمادگي ركھتا ہے اور يہ سب چيزيں استحصال شدگي اور محروميت سے وجود ميں آتي ہيں اور بنياد سے اوپر كے عوامل زيادہ سے زيادہ خود آگاہي ميں طبقاتي تضاد كو داخل كرنے كے لئے ہوتے ہيں، تو بطريق اوليٰ ان ممتاز شخصيتوں كو جو اس روشن فكرى كو استحصال شدہ طبقے كي خود آگاہي ميں داخل كرتي ہيں ان كا اور اس طبقے كا درد ہونا چاہيے اور ان سب كو ايك زنجير كے حلقے ميں ہونا چاہيے تاكہ اس طرح كي خود آگاہي ان ميں پىدا ہو سكے، جيسے كسي معاشرے كي عمارت كا تاريخي دور كے اعتبار سے اپني بنياد پر سبقت حاصل كرنا محال ہے اور جس طرح يہ محال ہے كہ ايك طبقے كا سماجي وجدان اپنے سماجي موقف پر مقدم ہو، اسي طرح يہ بھي محال ہے كہ ايك شخص رہنما كي حيثيت سے اپنے طبقے پر مقدم ہو اور اپنے طبقے كے تقاضوں سے بڑھ كر تقاضے پىش كرے، اس اعتبار سے محال ہے كہ استحصال پسند طبقوں ميں سے كوئي فردا اگرچہ استثنائي طور پر سہى، اپنے طبقے كے خلاف اور استحصال شدہ طبقے كے حق ميں قيام كرے ۔
كتاب ”تجديد نظر طلبي“ ميں ہے:
”كتاب” جرمن آئيڈيالوجى كي ايك جدت“، طبقاتي آگاہي پر ايك نيا تجزيہ ہے۔ اس كتاب ميں ماركس اپنے گذشتہ تمام آثار(۴۰) كے برخلاف طبقاتي آگاہي كو طبقے كي اپني پىداوار جانتا ہے، نہ يہ كہ باہر سے يہ چيز اس پر وارد ہوئي ہے۔ حقيقي آگاہي ايك آئيڈيالوجى كے سوا كچھ نہيں كيوں كہ حتمي طور پر طبقے كے مفادات كو ايك عمومي شكل دينے كي ضرورت ہوتي ہے، ليكن يہ امر اس بات كو نہيں روكتا كہ يہ آگاہي طبقے كے اپنے اندر سے پىدا ہونے والي آگاہي كي بنياد پر اس كے مفادات پر استوار ہو، بہرحال طبقہ اس وقت تك پختگي حاصل نہيں كرسكتا جب تك وہ اپني مخصوص آگاہي كو پا نہ لے ۔“
”يہ امر ماركس كے نظر ميں، طبقہ كے اندر فكرى كام(نظرياتي كام اور رہنمائي كا كام)اور مادي كام كي تقسيم كرتا ہے۔ بعض افراد اس طبقے كے مفكر اور دانشور بن جاتے ہيں جب كہ ديگر افراد ان افكار اور ان اوہام كے مقابل زيادہ خود سپردگي ركھتے ہيں اور انہيں زيادہ مقبول كرتے ہيں ۔“(۴۱)
كتاب ”فقر فلسفہ“ اور ايك بيان ميں ماركس كے مذكورہ نظريے كا تجزيہ كرتے ہوئے اسي كتاب ميں مرقوم ہے:
”اس طرح طبقاتي آگاہي كا حصول اور ايك ”طبقہ لنفسہ“ كي صورت اختيار كرنا پرولتاريا كا اپنا كام ہے۔ اقتصادي كشمكش كا خود انگيز نتيجہ ہے۔ اس انقلاب كو نہ تو وہ نظرياتي ماہرين لے كر آئے ہيں، جو مزدور تحريك سے باہر ہوتے ہيں اور باہر سے يہ نظريات لاتے ہيں اور نہ سياسى پارٹياں۔ماركس خيال پردازي كرنے والے سوشلسٹوں كي مذمت كرتا ہے كہ وہ اپني پرولتاريائي خصلت كے باوجود ”پرولتاريا“ كي تاريخي خود انگيختگي اور اس كي خاص سياسى تحريك كو نہيں ديكھتے اور اپنے خيالي تانوں بانوں كو پرولتاريا كي خود انگيختہ اور تدريجي تنظيم كي جگہ بصورت طبقہ ديكھنا چاہتے ہيں ۔“(۴۲)
يہ اصول بھي معاشرے، اس كے ميلانات اور افراد كي شناخت ميں كہ ان كا ميلان كيا ہے؟اور خاص طور پر قيادت اور معاشرے كي اصلاح كے دعويداروں كي شناخت ميں ماركسسٹي منطق كے حوالے سے خاص اہميت كا حامل ہے اور اسے ايك رہنما اصول قرار پانا چاہيے۔
اس گفتگو سے يہ بات سامنے آئي كہ ماركس اور اينجلز كسي ايسے روشن فكر گروہ كے قائل نہيں جو اپنے طبقے سے جدا اور بالاتر ہو اور نہ ہي ايسے گروہ كے قائل ہو سكتے ہيں، يعني ماركسزم كے اصول انہيں اس كي اجازت نہيں ديتے اور اگر كہيں ماركس نے اپنے بعض آثار ميں اس كے خلاف كچھ كہا ہے تو يہ ان موارد ميں سے ہے، جو يہ ظاہر كرتے ہيں كہ ماركس وہاں پر ماركسسٹ نہيں رہنا چاہتا۔ ہم بعد ميں يہ بتائيں گے كہ ايسے موارد كچھ كم نہيں، في الحال يہ سوال سامنے آتا ہے كہ ماركس اور اينجلز ماركسزم كے اصول كو سامنے ركھتے ہوئے، اپنے روشن فكرانہ موقف كي كس طرح توجيہ كريں گے۔ ان ميں سے كوئي بھي پرولتاريا طبقے سے تعلق نہيں ركھتا، يہ دونوں فلسفي ہيں، مزدور نہيں۔ پھر بھي انہوں نے محنت كشوں كے لئے ايك عظيم نظريے كو وجود بخشا، اس سلسلے ميں ماركس كا جواب سننے سے تعلق ركھتا ہے ۔ ”تجديد نظر طلبي“ ميں ہے:
”ماركس نے بہت كم روشن فكروں كے بارے ميں گفتگو كي ہے، ظاہراً وہ انہيں كسي خاص طبقہ ميں شمار نہيں كرتا بلكہ ديگر طبقات كا ايك حصہ جانتا ہے۔خاص طور پر انہيں بورژوائي طبقے سے نسبت ديتا ہے ۔
كتاب ”۱۸ برومر“ ميں ماركس خبر نگاروں، پروفيسروں، عدالت كے قاضيوں اور اكيڈمي كے اركان كو بھي پادريوں اور فوجي افسروں كي طرح بورژوائي طبقے ميں سے قرار ديتا ہے، اپنے بيان ميں جب وہ محنت كش طبقے كے لئے كام كرنے والے نظرياتي ماہرين كا نام لينا چاہتا ہے، جن ميں وہ خود اور اينجلز شامل ہيں اور جو پرولتاري بنياد نہيں ركھتے، ان كا ذكر روشن فكروں كي حيثيت سے نہيں كرتا بلكہ وہ انہيں فرمانروا گروہ كا ايك طبقہ جو پرولتاريوں ميں آگيا ہے اور ان كي تعليم و تربيت كے لئے بہت سے عناصر لايا ہے، قرار ديتا ہے ۔“(۴۳)
ماركس ايسي كوئي توضيح پىش نہيں كرتا كہ آخر وہ اور اينجلز كس طرح حكمران طبقے كے آسمان سے لڑھكے اور محكوم طبقے كي زمين پر ہيوط كر گئے اور قيمتي تحفے ان كي تعليم و تربيت كے لئے آكاش سے دھرتي پر گرے اور وہ بہ تعبير قرآن ”ذا مَترَ بَہ“ (جلد ۱۶) اپنے ساتھ لائے، حق يہ ہے كہ جو كچھ ماركس، اينجلز اور ان كے وسيلے سے خاص افتادہ نچلے طبقے پرولتر كے نصيب ميں آيا ہے، ابوالبشر آدم كے نصيب ميں نہيں آيا، مذہبى روايات كے مطابق جنہوں نے آسمان سے زمين پر ہيوط كيا، وہ آدم اپنے ساتھ اس طرح كا تحفہ نہيں لائے ۔
ماركس اس بات كي وضاحت نہيں كرتا كہ آخر كيونكر پرولتر طبقے كا آزادى بخش نظريہ حيات فرمانروا طبقہ ميں پروان چڑھا، اس كے علاوہ وہ اس كي وضاحت بھي نہيں كرتا كہ ”ہبوط“ اور يہ نيچے اتر آنا ان دو حضرات كے لئے استثنائي طور پر امكان پذير ہوا ہے يا دوسروں كے لئے بھي يہ بات ممكن ہے اور نيز وہ يہ بھي نہيں بتاتا كہ اب جب يہ بات معلوم ہوگئي كہ آسمان اور زمين كے دروازے بعض اوقات ايك دوسرے پر كھلتے ہيں، تو كيا اس سے صرف ”ہبوط“ كا عمل ہوتا ہے اور لوگ عرش و آسمان سے فرش و زمين كي طرف آتے ہيں يا كبھي ”معراج“ كي صورت رونما ہوتي ہے اور كيا بعض افراد زمين سے آسمان كي طرف بھي ”عروج“ پاتے ہيں؟
اور ايسا عروج عمل ميں آئے تو آسمان والوں كے شايان شان ايسا كوئي تحفہ نہيں ہو گا، جسے اوپر جانے والے لوگ اپنے ساتھ لے جائيں۔ بنيادي طور پر زمين سے آسمان كو تحفہ لے جانے كي بات بے معني ہے، بلكہ اگر معراج كي توفيق حاصل ہو اور آسمان ميں جذب ہو كر نہ رہ جائيں اور پھر انہيں دوبارہ زمين كي طرف لوٹنا پڑے تو وہ بھي ماركس اور اينجلز كي طرح آسمان سے تحفے اپنے ساتھ لائيں گے ۔
انتقادات
اب جب كہ نظريات ماديت تاريخ كے ”اصول“ اور ”نتائج“ پر سير حاصل گفتگو ہو چكي ہو تو ضرورت اس بات كي ہے كہ اس پر تنقيد اور تبصرہ ہوجائے ۔
سب سے پہلے ہميں اس نكتے كي وضاحت كرنا ہوگي كہ ہم يہاں نہ تو ماركس كي تمام كتب ميں اس كے نظريات پر تنقيد كے درپے ہيں اور نہ ہي كلي طور پر ماركسزم پر كوئي تنقيد كرنا چاہتے ہيں، اس وقت ہم ”ماديت تاريخ“ يا بااصطلاح ديگر ”تاريخي ميٹريالزم“ پر تنقيد كرنا چاہتے ہيں، جو ماركسزم كا ايك ستون ہے او ر بنيادي اعتبار سے ماركس كے نظريات پر مطلق تنقيد كچھ اور چيز ہے اور ”ماديت تاريخ“ كي طرح ماركسزم كے كسي اصول پر تنقيد اور چيز ہے ۔
ماركس كے نظريات پر تنقيد يعني اس كے ان مجموعي نظريات كا جائزہ جسے اس نے زندگي كے مختلف ادوار ميں مختلف كتابوں اور مختلف تحريروں ميں قلم بند كيا ہے اور جس ميں بے شمار تناقضات ہيں، اہل مغرب نے اس پر بڑي محنت سے كام كيا ہے۔ ايران ميں جہاں تك مجھے معلوم ہے، ”تجديد نظر طلبي“ اس موضوع پر سب سے اچھي تحرير ہے، جس كے حوالے ہم نے اپني كتاب ميں جابجا پىش كئے ہيں ۔(۴۴) ليكن ماركسزم يا اس كے اصولوں ميں سے كسي ايك پر تنقيد يا باالفاظ ديگر اس كے ايك اصول يا ان كئي اصولوں جو ماركسزم كي اساس سمجھے جاتے ہيں اور خود ماركس كي نظر ميں بھي ناقابل تامل ہيں، يا پھر ايك يا چند ايسے اصولوں پر تنقيد جو ہر چند خود اس كي نظر ميں قطعي نہيں ہيں اور خود اس نے اپنے بعض آثار ميں ان كے خلاف بھي كچھ كہا ہے، ليكن ان كا قطعي لازمہ ماركسزم كے اصول ہيں اور ماركس كا ان كے خلاف كچھ كہنا گويا ماركس كي ماركسزم سے ايك طرح كي عليحدگي ہے، ماركس كے نظريہ تاريخي ماديت كو پىش نظر ركھتے ہوئے ہم نے اس كتاب ميں يہي كام كيا ہے، ہم نے يہاں ماركس كے قطعي اور مسلمہ اصولوں يا ان سے حاصل ہونے والے قطعي نتائج كو سامنے ركھتے ہوئے تنقيد و تحقيق كي ہے ۔
يہ بات تاريخ كے عجائبات ميں سے ہے كہ ماركس جو اپني فلسفى، معاشرتي اور معاشياتي كتابوں ميں كم و بيش ہر جگہ تاريخي ميٹريالزم كا دم بھرتا تھا، اپنے زمانے كے بعض تاريخي واقعات كي تحليل و تعليل ميں بہت كم نظريہ ماديت تاريخ كي طرف متوجہ ہوا، ايسا كيوں ہے؟ اس سوال كے مختلف جوابات ديئے گئے ہيں۔ بات صرف مذكورہ موضوع پر ختم نہيں ہوتى، ماركسزم كے بہت سے مسائل ميں ماركس كي روش متناقص ہے، يعني نظرياتي اور عملي طور پر ماركسزم سے ايك طرح كي برگشتگي خود ماركس كي طرف سے مشاہدے ميں آتي ہے، پس اس كے لئے كسي زيادہ جامع جواب كي ضرورت ہے ۔
بعض افراد نے اس كا سبب ان كي زندگي كے مختلف ادوار كي خامي اور ناپختگي كو قرار ديا ہے ليكن يہ توجيہ كم از كم ماركسزم كے نقطہ نظر سے قابل قبول نہيں ہے۔ اس لئے آج ماركسزم كے جو كچھ اصول ہمارے سامنے ہيں، ان ميں سے بہت سے ماركس كي جواني يا درمياني عمر كے دور سے متعلق ہيں جب كہ بہت سي وہ باتيں جو انحرافي سمجھي جاتي ہيں، جن ميں سے اس كے اپنے سامنے كے بعض واقعات كي تحليل بھي شامل ہے، اس كي زندگي كے آخري دور سے متعلق ہيں ۔
بعض افراد نے اس اختلاف كو اس كي دوہري شخصيت پر محمول كيا ہے اور كہا ہے كہ وہ ايك طرف سے ايك فلسفى، صاحب نظر اور صاحب مكتب شخص تھا، جسے قطعي طور پر ايك يقين كا حامل ہونا چاہيے تھا، تاكہ وہ اصولوں كو قطعي اور ناقابل ترديد گردانے اور پوري قوت سے واقعات كو اپنے ذہن ميں اترتے ہوئے افكار كے مطابق ڈھالے۔ دوسري طرف وہ ايك علمي شخصيت اور علمي باطن كا حامل تھا اور اس كا علمي باطن اس بات متقاضي تھا كہ وہ ہميشہ حقائق كے سامنے سرتسليم خم كر دے اور كسي يقيني اصول كا پاپند نہ ہو ۔
بعض نے ماركس اور ماركسزم ميں فرق روا ركھا ہے، ان كا دعويٰ ہے كہ ماركس اور ماركس كي فكر، ماركسزم كا ايك مرحلہ ہيں، ماركسزم اپنے جوہر ميں ايك ترقي پذيرمكتب ہے۔ پس اگر ماركسزم نے ماركس كو پى چھے چھوڑ ديا ہو، تو اس ميں مضائقہ كي كون سي بات ہے؟
بعبارت ديگر اگر ماركس كا ماركسزم جو ماركسزم كا دور طفلي ہونے كے باعث قابل ترديد ہے تو يہ اس بات كي دليل نہيں كہ ماركسزم قابل ترديد ہے، ليكن اس عقيدے كے حامل افراد اس بات كي وضاحت نہيں كرتے كہ ماركسزم كا اصلي جوہر كيا ہے؟ كسي مكتب كے ارتقاء پذير ہونے كي شرط يہ ہے كہ اس كے اولين بنيادي اصول مستقل اور ناقابل تغير ہوں اور جو كچھ اعتراض ہو، فروع ميں ہو، اصول اپني جگہ ثابت رہيں وگرنہ كسي نظريہ كي تنسيخ اور اس كے كمال پذير ہونے ميں كوئي فرق باقي نہيں رہتا، اگر ہم كسي ثابت اور باقي رہنے والے اصول كو شرط تكامل نہ جانيں تو پھر بات كيا رہ جاتي ہے، پھر كيوں نہ ہم ہيگل ازم، سن سيمون، پروڈون يا ان جيسي ديگر ماقبل ماركس شخصيتوں سے اپني گفتگو كا آغاز كريں اور ہيگل، سن سيمونزم يا پروڈنزم كو ايك تكامل پذير مكتب جانيں؟ اور ماركسزم كو ان مكاتب كے مراحل ميں سے ايك مرحلہ قرار ديں؟
ہمارے خيال ميں ماركس كے تناقصات كا سبب يہ ہے كہ ماركس بيش تر ماركسٹوں كي نسبت كم تر ماركسٹ ہے، كہتے ہيں كہ اس نے ماركسٹوں كے ايك مجمع ميں جہاں وہ اپنے پچھلے نظريہ كے برخلاف نئے نظريہ كي حمايت ميں بول رہا تھا اور سننے والے اس كي گفتگو برداشت نہيں كر رہے تھے، كہا: ”ميں اس پائے كا ماركسٹ نہيں ہوں جس پائے كے ماركسٹ آپ لوگ ہيں“ نيز يہ بھي كہا جاتا ہے كہ اس نے اپني عمر كے آخري حصے ميں كہا: ”ميں قطعاً ماركسٹ نہيں ہوں ۔“
اپنے بعض نظريات ميں ماركسزم سے ماركس كي جدائي كا سبب يہ تھا كہ ماركس كي ہوشمندي اور اس كے فكر و فہم كي بلندي سے يہ بات دور تھي كہ وہ سو فيصد ماركسٹ بن جائے۔ مكمل ماركسٹ بننا كسي قدر حماقت كا متقاضي ہے، تاريخي ميٹريالزم جو ماركسزم كا ايك حصہ ہے اور جس پر ہماري گفتگو جاري ہے۔ جيسا كہ پہلے عرض كيا جا چكا ہے، كچھ ”اصول“ اور ”نتائج“ كا حامل ہے اور صرف ماركس كا ”عالم ہونا“ ہي نہيں بلكہ اس كا فلسفي ہونا اور اس كا مفكر ہونا، اسے اس بات كي اجازت نہيں ديتا تھا كہ وہ ان اصولوں اور نتائج كا ہميشہ پاپند رہے، اب ہم تنقيدات كي طرف آتے ہيں:
۱۔ بے دليل ہونا
سب سے پہلے تنقيد يہ ہے كہ نظريہ ايك بلا دليل تھيوري كي حد سے آگے نہيں بڑھتا۔ ہونا يوں چاہيے كہ ايك تاريخي فلسفي نظريہ يا تو اپنے زمانے كے عيني تاريخي حقائق كے تجربے پر مبني ہو اور اسے دوسرے ادوار پر عموميت دي جائے يا پھر يہ نظريہ ايسا ہو، جو ثابت اور مسلمہ فلسفى، منطقي اور علمي اصولوں كي بنياد پر علم منطق كے قياس و استدلال كے انداز پر ثابت ہو سكے ۔
تاريخي ميٹريالزم كي تھيوري ان ميں سے كسي روش ميں مبني نہيں۔ اس راستے سے نہ تو ان حقائق كي توضيح ہوتي ہے، جو ماركس اور اينجلز كے زمانے سے متعلق ہيں، يہاں تك كہ اينجلز خود اس بات كي تصريح كرتا ہے كہ ميں نے اور ماركس نے اہميت معاشيات كے بارے ميں اپني بعض كتابوں ميں وہاں غلطي كا ارتكاب كيا ہے، جہاں ہم نے اپنے زمانے كے حقائق كا تجزيہ كيا ہے، چونكہ ہم خود حقائق كا سامنا كر رہے ہيں، ان غلطيوں سے مبرا ہيں، چند ہزار سالہ انساني تاريخ بھي ان كي تائيد نہيں كرتى، يہاں تك كہ انسان جب فلسفي فرمودات كي كتب كا مطالعہ كرتا ہے، جن ميں گذشتہ تاريخ كي ماديت تاريخ كے حوالے سے توجيہ ٹھونسي گئي ہے، تو ان لوگوں كي توجيہ و تاويل پر سخت حيرت ہوتي ہے، مثلاً كتاب تاريخ جہان ميں ۔۔۔(۴۵)
۲۔ بانيان مكتب كي تجديد نظر
جيسا كہ ہم بار بار عرض كر چكے ہيں، ماركس معاشرے كي معاشي بنياد كو اصلي اور باقي پہلوؤں كو اس بنياد پر تعميرات سے تعبير كرتا ہے اور اس تعبير سے معاشي بنياد پر تمام بنيادوں كي يكجانبہ وابستگي كا پتہ چلتا ہے، علاوہ بريں ماركس اپنے متعدد مذكورہ بيانات ميں اس بات كي تصريح كرتا ہے كہ تاثير اور وابستگي يك جانبہ ہے، يعني معاشي عوامل تاثير مرتب كرنے والے عوامل ہيں اور باقي تمام شعبے تاثير لينے والے ہيں۔ معاشي عوامل خود سے آزادانہ طور پر عمل كرتے ہيں اور ديگر عوامل وابستہ عوامل ہيں ۔
حقيقت تو يہ ہے كہ ماركس نے يہ تصريح كي ہو يا نہ كي ہو، مادے كي روح پر، مادي ضروريات كي معنوي ضروريات پر، سوشيالوجي كي نفسيات پر اور كام كرنے كي فكر پر برتري سے متعلق ماركس كے خاص نظريات اسي نقطہ نظر كا تقاضا كرتے ہيں۔ ليكن ماركس نے اپني بہت سي تحريروں ميں جدلياتي منطق كي بنياد پر ايك اور مسئلے كو پىش كيا ہے، جسے ايك طرح كا تجديد نظر اور كسي حد تك تاريخ كي مطلق ماديت سے انحراف كہا جا سكتا ہے اور وہ ہے مسئلہ تاثير متقابل، تاثير متقابل كے اصول كي رو سے عليت كے رابطے كو يك طرفہ سمجھنا چاہيے، جس طرح ”الف“، ”ب“ كي علت اور اس ميں موثر ہے۔ اسي طرح ”ب“ بھي اپني جگہ ”الف“ كي علت اور اس كا موثر ہے بلكہ اس اصول كي بنياد پر عالم طبيعت اور معاشرے كے تمام اجزاء كے درميان ايك طرح كي وابستگي اور ايك طرح كي متقابل تاثير پائي جاتي ہے۔ مجھے في الحال اس سے كوئي بحث نہيں كہ اس صورت ميں پىش كيا جانے والا جدلياتي قانون درست بھي ہے كہ نہيں ليكن ميں يہ كہوں گا كہ اس قانون كي بنياد پر مادہ روح، كام اور فكر يا معاشي پہلو اور ديگر پہلوؤں ميں سے ايك كي دوسرے پر ترجيح كي بحث ہي بے معني ہو جاتي ہے كيوں كہ اگر دو چيزيں ايك دوسرے سے وابستہ رہيں اور ايك وجود دوسرے كے لئے ضروري ہو اور دونوں كا رہنا شرط وجود بن جائے تو پھر كسي كي ترجيح و تقدم ركھنے اور بنيادي ہونے كي بات بے معني ہے ۔
ماركس نے اپنے بعض بيانات ميں اصلي اور غير اصلي تمام امور كو معاشي بنياد كے حوالے كيا ہے اور بنياد اور عمارت كا ہرگز تذكرہ نہيں كيا، جيسا كہ ہم پہلے عرض كر چكے ہيں، وہ اپنے بعض بيانات ميں بنياد اور اس پر عمارت دونوں كي ايك دوسرے پر تاثير كا قائل ہوا ہے، تاہم اس نے اصلي اور آخري كردار انبياء كے حوالے كيا ہے، ”تجديد نظر طلبي“ ميں ماركس كي دو كتابوں ”سرمايہ“ اور ”علم اقتصاد پر تنقيد“ كے درميان موازنہ كيا گيا ہے اور يہ بتايا گيا ہے كہ كتاب ”سرمايہ“ ميں كتاب ”علم اقتصاد رپر تنقيد“ كي طرح يك طرفہ طور پر اقتصاد كي فيصلہ كن حيثيت كا ذكر كيا گيا ہے ۔ مصنف لكھتا ہے:
”اس كے باوجود ماركس نے شعوري يا غير شعوري طور پراس تعريف پر اضافہ كيا ہے اور وہ يہ ہے كہ بنياد پر عمارت بنياد كي ترجيح كے باوجود معاشرے ميں اس كے لئے بنيادي كردار ادا كر سكتي ہے ۔“(۴۶)
مولف مزيد لكھتا ہے كہ آخر حاكم اور فيصلہ كن كردار كي حامل ہونے كي حيثيت سے اقتصادي بنياد ہميشہ جو كردار ادا كرتي ہے اور اس بنيادي كردار ميں كہ جو عمارت ادا كرتي ہے، فرق كي نوعيت كيا ہے؟ يعني اگر عمارت كبھي بنيادي كردار ادا كرتي ہے، تو ايسي حالت ميں وہ حكم فرما اور فيصلہ كن حيثيت كي بھي حامل ہوگي بلكہ پھر جسے ہم عمارت كہتے ہيں، وہ عمارت نہيں رہتي بلكہ بنياد بن جاتي ہے اور بنياد عمارت كي جگہ لے ليتي ہے۔ اينجلز نے اپني عمر كے آخري حصے ميں جوزف بلاك نامي ايك شخص كے نام جو خط لكھا ہے، اس ميں وہ اس طرح گويا ہے:
”تاريخ كے مادي نظريے كے مطابق آخري مرحلے ميں تاريخ كي فيصلہ كن عامل پىداوار اور زندگي كي حقيقي تجديد ہے ۔“(۴۷)
”ميں نے اور ماركس نے اس سے زيادہ كچھ نہيں كہا ہے، اب اگر كوئي ماركس كے بعد اس گفتگو كو مسخ كر كے اس سے يہ مطلب نكالتا ہے كہ معاشي عامل ہي بطور مطلق فيصلہ كن عامل ہے، تو وہ اس عبارت كو ايك مجرد، پھيكي اور بےہودہ عبارت بناتا ہے۔ اقتصادي حالت بنياد ہے جب كہ ديگر عناصر عمارت ميں طبقاتي كشمكش كي سياسى شكل اور اس كے نتائج يعني كائناتي غلبے كے بعد كے حالات قانوني صورتيں، يہاں تك كہ شركت كرنے والوں كے ذہن ميں حقيقي كشمكشوں كے انعكاس، سياسى، قانوني اور فلسفي نظريات، مذہبى اعتقادات اور اس سے رونما ہونے والے انقلابات، تاريخي واقعات پر اثر انداز ہوتے ہيں اور اكثر حالات ميں حقيقي طور پر اس كي صورت گري كرتے ہيں۔ يہ تمام عوامل آپس ميں عمل اور رد عمل كي حيثيت ركھتے ہيں اور ان كے درميان محروم عوام كي اقتصادي تحريك اپني راہ كے تضادات كو لازماً دور كر ليتي ہے۔“(۴۸)
اس سے زيادہ تعجب خيز بات يہ ہے كہ اينجلز نے اپنے اسي خط ميں اس غلطي اور بقول خود اس كے مسخ كو ايك حد تك اپني اور ماركس كي ذمہ داري قرار ديا ہے۔ كہتا ہے:
”مجھے اور ماركس كو اس امر كے كچھ حصے كي ذمہ داري قبول كرني چاہيے كہ جو بعض اوقات اس عامل اقتصادي كو ضرورت سے زيادہ اہميت ديتے ہيں۔ ہم نے اپنے حريفوں كے مقابل بحالت مجبوري اس اقتصادي عامل كي تاكيد كي پھر ہمارے پاس اتنا وقت تھا اور نہ موقع كہ ہم ان تمام عوامل كا حق ادا كر سكيں، جو متقابل عمل ميں ان كے حصہ دار تھے ۔“(۴۹)
ليكن دوسرے لوگوں نے ماركس اور اينجلزكے اقتصادي عوامل پر انتہا پسندانہ تاكيد كو اينجلز كے اظہار خيال كے بالكل برعكس پىش كيا ہے، وہ كہتے ہيں كہ يہ انتہا پسندانہ تاكيد مخالف حريفوں كے سامنے نہيں بلكہ اس نظريے كے طرف دار قيبوں كے سامنے ان سے ان كے اسلحہ كو ہتھيانے كے لئے كي گئي ہے۔ تجديد نظر طلبي ميں ”علم اقتصاد پر تنقيد“ كي وجہ نگارش بيان كي گئي ہے، اس كتاب ميں ہر دوسري كتاب سے زيادہ عوامل اقتصادي كے يك طرفہ كردار پر زور ديا گيا ہے، ہم اس كتاب كے مقدمے كي معروف عبارت قبل ازيں نقل كر چكے ہيں، بہرحال تجديد نظر طلبي ميں ہے:
”علم اقتصاد پر تنقيد“ كي تحرير كا دوسرا سبب پروڈون كي ہنڈي سے متعلق بنيادي قوانين پر مبني كتاب تھى، اس كے علاوہ ڈاريمون پىٹر اور پروڈون كي ايك اور كتاب بھي مذكورہ كتاب كي اشاعت كا سبب بني۔ ماركس نے جس وقت ديكھا كہ ايك طرف سے اس كے رقيب يعني پروڈون كے حامي افراد اور دوسري طرف سے لاسال كے معتقدين اقتصادي عوامل پر (انقلابانہ انداز ميں نہيں بلكہ) اصلاح طلبانہ ڈھب سے زور دے رہے ہيں، تو اس نے چاہا كہ اس اسلحہ كو ان كے ہاتھوں سے چھين كر اسے انقلابى صورت ميں بروئے كار لائے۔اس كا لازمہ اس كے عقائدكي ”خشك شدگي“ اور ان كا عوام پسند ہونا تھا۔“(۵۰)
مائو نے تاريخي ماديت كے مفہوم ميں تجديد نظر اور اقتصاد كے اصل بنياد ہونے كو چين كے حالات كي صورت اور اس كردار كي توجيہ كے لئے جو انقلاب چين اور اس كي اپني قيادت نے عملاً انجام ديا ہے، يہاں تك پہنچايا ہے كہ اب يہ كہنا پڑتا ہے كہ تاريخي ميٹريالزم اور اقتصاد كي اصل بنياد ہونے كا مفہوم اور اس كے نتيجے ميں گويا سائنسي سوشلزم جو تاريخي ميٹريالزم پر مبني ہے، سوائے لفظ اور جملہ بنديوں كے اور كچھ نہيں رہا ہے ۔
مائو رسالہ تضاد ميں ”اصلي تضاد اور اس كي حقيقي سمت“ كے عنوان سے لكھتا ہے:
” ۔۔۔ كسي تضاد كي اصلي اور غير اصلي سمتيں ايك دوسرے كي جگہ لے ليتي ہيں اور اس تبديلي كے ساتھ واقعات اور اشياء كي خصلتوں ميں بھي تبديلي آجاتي ہے، كسي تضاد سے متعلق پراسيس ( Process ) يا اس كے تكامل سے متعلق كسي معين مرحلے ميں A اس كي اصلي سمت اور B غير اصلي سمت كو تشكيل ديتي ہے۔ پراسيس كے دوسرے مرحلے يا دوسرے حصے ميں كسي شے يا كسي واقعہ كے تكامل كے عمل ميں جب كوئي سمت تضاد دوسري سمت سے ٹكر ليتے ہوئے كمزور يا طاقت ور ہو جاتي ہے، تو اس كے نتيجے ميں ان دونوں سمتوں كے مقررہ مقامات ايك دوسرے سے بدل جاتے ہيں ۔“(۵۱)
اس كے بعد وہ لكھتا ہے:
”۔۔۔بعض لوگوں كا خيال ہے كہ يہ نظريہ (اصلي جہت كا بدل جانا) بعض تضادات كے سلسلے ميں درست نہيں۔ مثلاً وہ كہتے ہيں كہ پىداواري قوتيں(پىداواري قوتوں اور پىداواري روابط كے درميان تضاد ميں) كام (تھيوري اور پريكٹيكل كے مابين تضاد ميں) اور اقتصادي بنياد (اقتصادي بنياد اور عمارت كے تضاد ميں) تضاد كي اہم اور اصلي جہت كي تشكيل كرتے ہيں۔ گو تضاد كي دو سمتيں ايك دوسري سے اپني جگہ نہيں بدلتيں۔ يہ فكر صرف ميكانياتي ماديت سے مختص ہے كہ جو جدلياتي ماديت كے ساتھ كسي قسم كي قربت نہيں ركھتى، ظاہر ہے كہ پىداواري طاقتيں، كام اور اقتصادي بنياد كلي طور پر اہم اور فيصلہ كن كردار كي حامل ہيں اور اس حقيقت كا منكر شخص ميٹريالسٹ نہيں ہے۔ تاہم ہميں اس طرح ماننا ہوگا كہ پىداواري تعلقات، تھيوري اور عمارت معين شرائط كے تحت اپنے مقام پر ”اصلي اور فيصلہ كن كردار“ كے حامل ہو سكتے ہيں۔ اگر پىداواري تعلقات ميں تبديلي كے بغير رشد و تكامل تك نہيں پہنچ سكتے، تو پھر پىداواري تعلقات كي تبديلي ازلي اور فيصلہ كن كردار كي حامل ہو سكتي ہے۔ اگر لينن كي اس گفتگو كو كہ ”انقلابي تھيوري كے بغير كسي انقلابى تحريك كا وجود نا ممكن ہے ۔“ آج كے دستور ميں شامل كر ليا جائے، تو انقلابى نظريے كي تخليق اور اشاعت بنياد ي اور فيصلہ كن كردار حاصل كر لے گي۔ اگر عمارت(سياست اور كلچر وغيرہ) اقتصادي بنياد كي رشد و تكامل ميں ركاوٹ بن جائے تو اس منزل پر سياسى اور ثقافتي تحولات اصلي اور فيصلہ كن كردار كے حامل ہوجائيں گے، كيا ہم نے اس اصول كے تحت ميٹريالزم كي تنقيض و نفي كر دي ہے؟ ہرگز نہيں، اس لئے كہ ہم اس بات كو مانتے ہيں كہ تاريخ كي پىش رفت كے عمومي راستے ميں مادہ، روح كے لئے فيصلہ كن كردار ادا كرتا ہے اور وجود اجتماعى، اجتماعى شعور كو معين كرتا ہے، ليكن ساتھ ہي ہم اس بات كو بھي مانتے ہيں اور ماننا بھي چاہيے كہ روح، مادہ پر، اجتماعى شعور، اجتماعى وجود پر، اقتصادي بنياد، عمارت پر متقابل اثرات كے حامل ہيں، اس طرح نہ صرف يہ كہ ہم ميٹريالزم كي تنقيض و نفي نہيں كرتے، بلكہ ميكانياتي ماديت كو رد كر كے جدلياتي ماديت كي حمايت كرتے ہيں ۔“۵۲
جناب مائو نے اپني گفتگو ميں تاريخي ميٹريالزم كي مكمل تنقيض كي ہے۔ جناب مائو كہتے ہيں:
”اگر پىداواري تعلقات پىداواري قوتوں كے رشد و كمال كے آڑے آتے ہيں ۔“ يا پھر ان كي يہ بات: ”جس دم انقلابى تحريك انقلابى نظريے كي محتاج ہو“، يا يہ گفتگو كہ”اگر عمارت بنياد كي ترقي و تكامل كي راہ ميں حائل ہو“ يہ تمام باتيں وہ ہيں جو ہميشہ سے ہوتي چلي آئي ہيں اور انہيں ہونا بھي چاہيے ليكن تاريخي ميٹريالزم كے مطابق پىداواري قوتوں كا ارتقاء لازمي طور پر پىداواري تعلقات ميں تبديلي پىدا كرتا ہے۔ انقلابى تبديلي جبراً از خود پىدا ہو جاتي ہے اور عمارت جبراً بنياد كي پىروي ميں دگر گوں ہوجاتي ہے ۔“
كيا ماركس نے كمال صراحت كے ساتھ ”انتقاد بر اقتصاد“ كے مقدمہ ميں يہ نہيں كہا:
”معاشرے كي پىداواري طاقتيں، ترقي و تكامل كے ايك خاص مرحلے ميں موجود پىداواري روابط يا روابط مالكيت جو پىداواري قانوني اصطلاح ہے اور پىداواري قوتيں اب تك جن تعلقات ميں اپنا عمل جاري ركھے ہوئے تھيں، سے ٹكرا جاتے ہيں۔ يہ تعلقات جو ماضي ميں توليدي طاقتوں كي ترقي كا ذريعہ تھے، اب ان كي راہ ميں حائل ہو جاتے ہيں اور پھر معاشرتي انقلاب كا دور شروع ہوجاتا ہے اور معاشي يا اقتصادي اساس ميں تبديلي ساري عمارت كو كسي قدر سرعت كے ساتھ تباہ كر ديتي ہے ۔“(۵۳)
پيداواري طاقتوں كي ترقي كي راہ كھولنے كے لئے پىداواري روابط كي تبديلي كا پىداواري قوتوں ميں رشد كا تقدم، انقلابى فكر كو انقلابى عمل ميں بدلنے كے لئے انقلابى تھيورى كي تدوين كا تقدم، بنياد ميں تبديلي لانے كے لئے عمارت ميں تبديلى، كام پر فكر اور مادہ پر روح كے تقدم كے معني سے واضح ہوتا ہے كہ اقتصادي شعبے كے مقابلے ميں سياسى اور فكرى شعبے كو اصالت اور استقلال حاصل ہے اور اس سے ماديت كي نفي ہوتي ہے ۔
مائو كا يہ كہنا كہ ”تاثير كو يك طرف جاننے كا مطلب جدلياتي ماديت كي تنقيض ہے ۔“
درست ہے ليكن اس كا كيا كيا جائے كہ سوشلزم كي اساس اسي كي ضد پر قائم ہے، لہٰذا مجبوراً يا تو علمي سوشلزم كو ماننا اور جدلياتي منطق كي ترديد كرنا ہوگي يا پھر جدلياتي منطق كو ماننا اور علمي سوشلزم كو رد كرنا ہوگا ۔
علاوہ بر يں جناب مائو كہتے ہيں:
”ہم جانتے ہيں كہ تاريخ كي پىش رفت كے عمومي عمل ميں مادہ روح كے لئے معاشرتي وجود، معاشرتي شعور كے لئے فيصلہ كن كردار ادا كرتے ہيں، اس سے وہ كيا كہنا چاہتے ہيں! جب يہ بات تسليم كر لي گئي كہ اصلي تضادات كي سمتيں آپس ميں بدلتي رہتي ہيں، تو پھر كبھي پىداواري طاقتيں پىداواري تعلقات كو معين كرتي ہيں اور كبھي اس كے برعكس، كبھي سياست، كلچر، طاقت، مذہب اور ان جيسي چيزيں معاشرے كي اقتصادي بنياد كو تبديل كرتي ہيں اور كبھي اس كے برعكس، پس كبھي مادہ، روح كو معين كرتا ہے اور كبھي اس كے برعكس، كبھي سماجي وجود، سماجي شعور كا خلق ہے اور كبھي برعكس ۔“
حقيقت تو يہ ہے كہ جناب مائو نے جو كچھ تضادات كي بنيادي سمتوں كے تبديل ہونے كے بارے ميں كہا ہے، وہ دراصل مائوازم كي توجيہ ہے كہ جو ماركسزم كے تاريخي ميٹريالزم كي توجيہ كے بجائے عملاً اس كي ضد بن گئي ہے۔ ہر چند كہ وہ اسے بظاہر توجيہ ہي كي صورت ديتے ہيں، مائو نے عملاً يہ ثابت كيا ہے كہ وہ بھي ماركس كي طرح اس سے زيادہ سمجھ دار ہے كہ ہميشہ ماركسٹ رہے، مائو كي قيادت ميں آنے والے انقلاب چين نے عملي طور پر سائنٹفك سوشلزم اور تاريخي ميٹريالزم اور بالآخر ماركسزم كي نفي كر دي ہے ۔
چين نے مائو كي قيادت ميں كسانوں كے ذريعے چين كے قديم جاگيردارانہ نظام كو الٹ ديا اور اس كي جگہ سوشلزم كو رائج كيا، حالانكہ سائنٹفك سوشلزم اور تاريخي ميٹريالزم كي رو سے اس ملك كو جو جاگير دارانہ نظام كے مرحلے سے گذر رہا ہو، بااعتبار ترتيب كيپٹل ازم اور صنعتي مرحلے ميں داخل ہونا چاہيے اور اس مرحلے ميں ترقي كي معراج پر پہنچنے كے بعد سوشلزم كي طرف بڑھنا چاہيے۔ تاريخي ميٹريالزم كي رو سے جس طرح نطفہ ماں كے رحم ميں دو مرحلے ايك ساتھ طے نہيں كر سكتا، معاشرہ بھي منظم اور سلسلہ وار مراحل سے گذرے بغيرآخري مرحلے تك نہيں پہنچ سكتا، ليكن مائو نے عملاً دكھا ديا كہ وہ ايسي دايہ ہے، جو چار مہينے كے جين كو صحيح وسالم مكمل اور بے عيب دنيا ميں لا سكتي ہے۔ اس نے دكھا ديا كہ ماركس كے دعوے كے برخلاف، قيادت، جماعتي ترتيب، سياسى سرگرمياں، انقلابى تھيورى، معاشرتي معلومات گويا وہ تمام چيزيں جنہيں ماركس شعوري نوعيت ديتا ہے، وجودي نہيں، عمارت سمجھتا ہے، بنياد نہيں اور جن كے لئے وہ اصالت كا قائل نہيں پىداواري تعلقات كو بدل سكتي ہيں اور ملك كو صنعتي بنا سكتي ہيں اور اس طرح عملاً سائنٹفك سوشلزم كو نظر انداز كر سكتي ہيں ۔
مائو نے ايك اور طرح سے بھي تاريخ كے ماركسي نظريے كي تنقيض كي ہے:
”ماركسي نظريے يا كم از كم خود ماركس كے اعتبار سے، كسان طبقے كے پاس اگرچہ انقلابى ہونے كي پہلي اور دوسري شرط جو استحصال يافتہ ہونے اور مالكيت نہ ركھنے سے عبارت ہے، موجود ہے ليكن اس ميں تمركز، تعاون، تفاہم اور اپني طاقت سے آگاہي پر مبني تيسري شرط موجود نہيں، لہٰذا كسان طبقہ كبھي بھي كسي انقلابى جدوجہد كو اپنے ذمہ نہيں لے سكتا، زيادہ سے زيادہ يہ ہو سكتا ہے كہ كسي نيم زرعي اور نيم صنعتي معاشرے ميں كسان طبقہ پرولتاريا كے انقلابى طبقے كا پىروكار بن جائے، بلكہ ماركس كي نظر ميں كسان طبقہ ذاتاً پست، رجعت پسند اور ہر طرح كي انقلابى تخليق سے خالي ہے۔(۵۴)
ماركس اينجلز كے نام اپنے ايك خط ميں پولينڈ كے انقلاب سے متعلق موضوع ميں ديہاتيوں كے بارے ميں لكھتا ہے:
”ديہاتيوں، ذاتاً رجعت پسند، ان پست لوگوں كو۔۔كبھي جنگ ميں نہيں بلانا چاہيے ۔“(۵۵)
ليكن مائو نے اسي بالذات رجعت پسند طبقے اور انہيں پست فطرتوں كو جنہيں جنگ اور پىكار ميں نہيں بلانا چاہيے، ايك انقلابى طبقہ بنايا اور ايك قديم حكومت كا تختہ الٹ ديا۔ ماركس كي نگاہ ميں كسان صرف يہي نہيں كہ كسي ملك كو سوشلزم كي طرف نہيں لے جا سكتے بلكہ جاگيردارانہ نظام كي كيپٹل ازم ميں منتقلي ميں بھي ان كا كوئي حصہ نہيں، وہ طبقہ جو معاشرے كو فيوڈالزم سے كيپٹل ازم ميں منتقل كرتا ہے اور اس تاريخي لمحے ميں انقلابى خصلت كا حامل ہوتا ہے، بورژوائي طبقہ ہے نہ كہ كسان، ليكن مائو نے اسي پست اور بذاتہ رجعت پسند طبقے كے ذريعے دو منزلوں كو ايك ساتھ طے كر ليا اور فيوڈالزم سے ايك دم سوشلزم ميں آپہنچا۔
پس مائو كو يہ حق پہنچتا ہے كہ وہ ماركسزم سے اتني دوري اختيار كرنے كے ساتھ مائوازم كي توجيہ كے لئے تضادات كي اصلي سمتوں كے تبديل ہونے كي بات كرے اور زبان پر لائے بغير اس طرح ظاہر كرے كہ گويا وہ ماركسزم، تاريخي ميٹريالزم اور سائنٹفك سوشلزم كي عالمانہ تفسير كر رہا ہے ۔
مائو نے اس درس كو كہ”ايك ماركسٹ كے لئے ضروري ہے وہ بوقت ضرورت عملاً ماركسزم سے عليحدہ ہوجائے، اپنے معتبر پىش رو ”لينن“ سے سيكھا۔لينن نے مائو سے پہلے روس ميں انقلاب بپا كيا اور يہ وہ وقت تھا جب روس ايك نيم صنعتي اور نيم زرعي ملك تھا، اس نے پہلي بار ايك سوشلسٹ ملك كي بنياد ڈالي۔ لينن نے ديكھا كہ اس كي عمر اس بات كے لئے كافي نہيں ہے كہ وہ اتنا صبر كرے كہ روس ايك مكمل صنعتي ملك بن جائے اور كيپٹل ازم اور محنت كشوں كا استحصال آخري مرحلہ تك پہنچ جائے اور شعور كو بيدار كرنے والي تحريك بطور خود ايك انقلاب برپا كر دے اور ايك مكمل تبديلي سامنے آئے، اس نے ديكھا كہ اگر وہ اس انتظار ميں بيٹھا رہے كہ اس حاملہ عورت كي حاملگي كا دور ختم ہو، اسے درد زہ رونما ہوا اور پھر وہ دايہ كے فرائض انجام دے تو اسے دير ہوجائے گي لہٰذا اس نے عمارت سے اپنا كام شروع كيا، اس نے پارٹى، سياست، انقلابى نظريے، جنگ اور طاقت سے كام لے كر روس كے نيم صنعتي ملك كو آج كا ايك سوشلسٹ ملك بنا ديا ۔
لينن نے عملي طور پر اس ضرب المثل كو سچ كر دكھايا كہ ”ايك گرہ سينگ ايك گز لمبي دم سے بدر جہا بہتر ہے“ وہ ماركس كي ايك گز لمبي دم كے انتظار ميں نہيں بيٹھا كہ روسي معاشرے كي اقتصادي بنياد اپنے آپ ڈائنامك تحريك سے كبھي كوئي شورش بپا كرے اور انقلاب رونما ہو، اس نے اپني زرد سياست، جماعتي تعليمات اور سياسى آگاہي پر مبني ايك گرہ والي ”سينگ“ سے استفادہ كيا اور كامياب رہا۔
۳۔ بنياد اور عمارت كے جبري تطابق كا بطلان
تاريخ ماديت كے نظريے كي رو سے معاشروں ميں ہميشہ يہ ضروري ہے كہ عمارت اور بنياد كے درميان ايك طرح كي مطابقت پائي جائے اور وہ اس طرح ہو كہ عمارت سے بنياد اور بنياد سے عمارت كي شناخت ہو سكے۔ (جيسے علم منطق ميں برہان اني ہوتي ہے، جس سے حاصل ہونيوالي معرفت نيم كامل ہوتي ہے اور برہان لمي سے حاصل ہونيوالي معرفت كامل ہوتي ہے) اگر بنياد دگرگوں ہو اور عمارت و بنياد كا تطابق بگڑ جائے تو لازماً معاشرے كا توازن بھي بگڑ جائے گا اور ايك بحران رونما ہوگا جس كے نتيجے ميں بہرحال عمارت كم و بيش تيزي كے ساتھ تباہي سے دوچار ہوگى، مگر جب تك بنياد اپني پہلي حالت پر باقي رہے گي۔ عمارت بھي لازمي طور پر اپني جگہ پر مستحكم رہے گى، دور حاضر كے تاريخي واقعات نے عملاً اس كے اُلٹ ثابت كيا ہے، ماركس اور اينجلز نے اقتصادي بحرانات جو ۱۸۲۷ء سے ۱۸۴۷ء كے دوران رہے، كے بعد سياسى اور اجتماعى انقلابات ديكھے اور يہ سمجھے كہ معاشرتي انقلابات اقتصادي بحرانوں كا ضروري اور لاينفك نتيجہ ہوتے ہيں ۔
ليكن مولف ”تجديد نظر طلبي“ كہتا ہے كہ:
”تاريخ كا مذاق ديكھئے كہ ۱۸۴۷ء سے آج تك صنعتي ممالك ميں ہميں كوئي ايسا اقتصادي بحران نظر نہيں آيا، جو انقلاب ساتھ لايا ہو، اسي ماركس كے زمانے ميں اور اس كي موت سے پہلے چار مرتبہ پىداواري طاقتيں پىداواري تعلقات سے ٹكرائيں اور كوئي انقلاب نہيں آيا اور بعد ميں جے شويسٹر جيسے بعض ماہرين معاشيات اس نتيجے پر پہنچے كہ انہوں نے ان بحرانات كو ”تعميري تباہي“ كہا اور معاشي توازن اور ترقي كو واپس پلٹانے كے لئے انہيں ايك قابل اطمينان دريچہ قرار ديا ۔“
انگلينڈ، جرمنى، فرانس اور امريكہ جيسے ملكوں نے عظيم صنعتي ترقياں حاصل كيں اور سرمايہ داري كو اپني انتہائي بلندي تك پہنچايا۔
ماركس كا خيال تھا كہ يہ وہ ممالك ہوں گے، جن ميں سب سے پہلے مزدور رہنما انقلاب رونما ہوگا اور يہ سب سوشلسٹ بن جائيں گے، مگر اس كے برعكس ان كے سياسى، قانوني اور مذہبى نظام اور وہ كچھ كہ جسے وہ عمارت كہتا تھا، ميں كوئي تبديلي نہيں آئى، جس بچے كي پىدائش كا ماركس كو انتظار تھا اس نے اپنے نو ماہ پورے كر لئے اور نو سال بھي گذار ديئے بلكہ ۹۰ سال بھي بيت گئے، مگر ابھي تك پىدا نہيں ہوا اور اب آئندہ بھي اس كے پيدا ہونے كي اميد نہيں ہے۔
البتہ يہ حكومتيں جلد يا بدير ختم ہونے والي ہيں، ليكن ان ملكوں ميں جس انقلاب كي اميد كي جارہي ہے، وہ قطعاً مزدور انقلاب نہيں ہوگا اور تاريخ كا ماركسي نظريہ كسي طرح بھي درست ثابت نہيں ہوگا اور يہي حال سوشلسٹ ممالك اور ان پر حكومت كرنے والوں كا بھي ہوگا، يہ بھي اپنے اس حال ميںباقي نہيں رہيں گے، ليكن آئندہ آنے والي حكومت ہرگز سرمايہ دارانہ حكومت نہيں ہوگي ۔
ان كے مقابلے ميں ہم ديكھتے ہيں كہ مشرقي يورپ، ايشياء اور جنوبي امريكہ ميں بعض ممالك سوشلزم تك آپہنچے ہيں، جب كہ ابھي ان كے جننے كا موقع نہيں آيا تھا، آج ايسے ممالك بھي ہمارے سامنے ہيں، جو بنياد، كے اعتبار سے ايك دوسرے كے مشابہ اور برابر ہيں، ليكن عمارت كے لحاظ سے ايك دوسرے سے مختلف ہيں، اس كي بہترين مثال امريكہ اور روس ہيں، امريكہ اور جاپان بھي ايك جيسي حكومت (سرمايہ دارانہ نطام) كے حامل ہيں، ليكن سياست، مذہب، اخلاق، آداب اور فنون ميں يہ دونوں ايك دوسرے سے مختلف ہيں، ليكن ان كے مقابل ايسے ممالك بھي ہيں جو مكمل طور پر معاشي حالات كے ساتھ مذہبى اور سياسى نظام كے اعتبار سے يكساں اور مشابہ عمارت كے حامل ہيں۔ يہ باتيں ہميں بتاتي ہيں كہ بنياد اور اس پر قائم عمارت كے درميان وہ ضروري تطابق جو تاريخي ميٹريالزم كا لازمہ ہے، سوائے توہم كے اور كچھ نہيں ۔
۴۔ آئيڈيالوجى كي اپنے دور سے عدم مطابقت
جيسا كہ ہم پہلے بيان كر چكے ہيں، تاريخي ماديت كي رو سے تاريخ كے كسي بھي دور ميں عمارت، بنيادپر سبقت نہيں لي جا سكتي۔ لہٰذا ہر دور كي معلومات لازماً اسي دور سے وابستہ ہوتي ہيں اور جب وہ دور ختم ہوجاتا ہے، تو وہ معلومات بھي كہنہ اور منسوخ ہوجاتي ہيں اور تاريخ كے ريكارڈ ميں محفوظ كر لي جاتي ہيں۔ معلومات، فلسفے، منصوبے، پىش گوئياں اور مذاہب سب اسي دور كے تقاضوں كي جبري پىداوار ہيں، جس ميں وہ ظہور پذير ہوئي ہيں اور دوسرے دور كے تقاضوں كے ساتھ ميل نہيں كھاتيں، ليكن عملاً اس كے برعكس ثابت ہوا ہے، اديان و مذاہب كا ذكر كيا! بہت سے فلسفے، بہت سے شخصيتيں، بہت سے افكار اور كتنے ہي ايسے افكار ہيں، جنہوں نے وقت كے مادي تقاضوں كو وجود بخشا، ليكن وہ آج بھي تاريخ بشريت كے افق پر تابندہ ہيں، عجيب بات يہ ہے كہ ماركس يہاں بھي اپني بعض باتوں ميں ماركسزم سے عليحدہ ہو گيا ہے، وہ اپني معروف كتاب ”جرمن آئيڈيالوجى“ ميں لكھا ہے:
”كبھي كبھار يوں لگتا ہے كہ آگاہي اپنے ہم عصر تجربي تعلقات پر مقدم ہوگئي ہے۔ اس طرح ايك زمانہ بعد كي كشمكشوں ميں دور ماقبل كے مفكرين كي باتوں سے حجت كي حيثيت سے استفادہ كيا جا سكتا ہے ۔“(۵۶)
۵۔ ثقافتي ترقي كا استقلال
تاريخي ماديت كي رو سے معاشرے كي علمي و ثقافتي بنياد، سياست، قضاوت اور مذہب كي طرح اقتصادي بنياد سے وابستہ ہے اور اس سے ہٹ كر بطور جداگانہ اور مستقل حيثيت سے اس كي ترقي كا امكان نہيں۔ معاشرے كے پىداواري آلات اور اقتصادي بنياد كي ترقي ہي علم كو آگے بڑھاتي ہے۔ اولاً ہميں معلوم ہے كہ پىداواري آلات انساني وجود كے بغير ہرگز از خود ترقي نہيں كرتے۔ انساني عالم طبيعت اور انسان كي محنت طلب، جستجو مل جل كر پىداواري آلات كو ترقي اور تكامل سے ہمكنار كرتے ہيں۔ پىداواري آلات اور انسان كي ترقي و تكامل باہم مربوط ہيں، ليكن يہاں موضوع گفتگو يہ ہے كہ ان ميں كون كس پر مقدم ہے؟ كيا انسان پہلے كچھ دريافت كرتا ہے اور پھر اسے عمل كي منزل ميں لاكر صنعت كو وجود عطا كرتا ہے يا پہلے صنعت وجود ميں آتي ہے اور پھر انسان كچھ دريافت كرتا ہے؟ بلاشبہ دوسري بات درست ہے ۔
ظاہر ہے كہ فني اصولوں اور سائنسي قوانين كي دريافت انسان كے تجربہ اور تجسس سے ہوتي ہے، اگر انسان عالم طبيعت كو سمجھنے كي كوشش نہ كرے، تجسس اور تجربے سے كام نہ لے تو وہ فطرت كے قوانين ميں سے كسي سائنسي قانون كو دريافت نہيں كر سكتا اور كوئي فني اصول اس كے ہاتھ نہيں لگ سكتا، بات يہ نہيں ہے، گفتگو اس امر ميں ہے كہ كيا تجسس اور تجربے كے بعد انسان كے اپنے اندر عملي نشوونما ہوتي ہے اور پھر وہ اپنے وجود كے باہر فني آلات كي تخليق كرتا ہے يا معاملہ اس كے برعكس ہے؟ بلاشبہ پہلي صورت درست ہے۔ علاوہ بريں ”رشد“ يا ”تكامل“ كي تعبير انسان كے لئے ”حقيقي“ ہے اور فني اور پيداواري آلات كے لئے ايك ”مجازي“ تعبير ہے۔ حقيقي رشد و تكامل وہ ہے، جس ميں ايك عيني حقيقت ادنيٰ سے اعليٰ مرحلے ميں آئے اور مجازي رشد وہ ہوتا ہے، جہاں ايك عيني حقيقت اپنے آپ كو تبديل نہ كرے، ايك مرحلے سے دوسرے مرحلے ميں نہ جائے بلكہ معدوم و منسوخ ہوجائے اور اس سے مختلف حقيقت اس كي جگہ لے لے۔
مثلاً بچے كا بڑا ہونا درحقيقت ايك حقيقي رشد و تكامل ہے، ليكن جب كوئي استاد كسي كلاس كو پڑھا رہا ہو اور بعد ميں اس سے زيادہ فاضل اور زيادہ تجربہ كار استاد اس كي جگہ لے لے، تو كلاس كي تدريسي حالت ميں ترقي ہوگي اور جماعت تكامل پائے گى، ليكن يہ تكامل ايك مجازي تكامل ہوگا، اوزار سازي كے دوران انساني تكامل ايك حقيقي تكامل ہے۔ واقعاً انسان روحاني طور پر نشوونما پاتا ہے اور تكامل سے ہمكنار ہوتا ہے، ليكن صنعتي تكامل موٹر كاروں كے تكامل كي طرح جس ميں ہر سال ايك نيا كامل ماڈل نئي ٹيكنيك كے ساتھ بازار ميں آجاتا ہے۔ ايك مجازي تكامل ہے يعني اس ميں ايك عيني حقيقت ادنيٰ سے اعليٰ مرحلے ميں نہيں پہنچتى، گذشتہ سال كي موٹر موجودہ سال ميں زيادہ آسائشات كي حامل نہيں ہوتى، بلكہ معدوم و منسوخ ہو جاتي ہے اور ميدان سے نكل جاتي ہے اور اس كي جگہ دوسري گاڑياں لے ليتي ہيں ۔
بعبارت ديگر ايك ”ناقص“ چيز كا خاتمہ ہوتا ہے اور دوسري ”كامل“ چيز اس كي جگہ لے ليتي ہے۔ ايسا نہيں ہوتا كہ ايك چيز دو ادوار ميں نقص سے كمال كي طرف آئے، وہاں جہاں حقيقي اور مجازي تكامل ايك دوسرے كے دوش بدوش ہوں، ظاہر ہے كہ حقيقي تكامل اور مجازي فروغ ہوگا۔ مزيد يہ كہ يہ امر صرف فني علوم كے سلسلے ميں ہے۔ طب، نفسيات، عمرانيات، منطق، فلسفہ، رياضي اور ان جيسے علوم ميں ہرگز اس طرح كي يك طرفہ وابستگي كي تائيد نہيں ہو سكتى، علوم كي پيش رفت كي اقتصادي اور مادي حالات سے وابستگي ايسي ہي ہے، جيسي اقتصادي اور مالي حالات كي علوم كي پيش رفت سے وابستگي جيسا كہ كشملر، ماركسزم كے خلاف لكھتے ہوئے كہتا ہے:
”يقينا مادي اور معاشي حالت كلچر كے عالى شان مظاہر كي لازمي شرط ہے، ليكن اتني ہي يہ بات بھي مسلم ہے كہ روحاني اور اخلاقى زندگي بذات خود بھي ايك پىش رفت كي حامل ہے ۔“(۵۷)
فرانس كا اگسٹ كانٹ انسان اور انسانيت كا خلاصہ ”ذہن“ كو قرار ديتا ہے جو انسان كي انساني صلاحيتوں كا ايك حصہ ہے اور انسان كي روحانيت كا نصف ہے۔ اگر اس كے اس بيان كا نقص دور كر ديا جائے تو اجتماعى تكامل ميں اس كا نظريہ ماركس كے نظريے سے بدرجہا بہتر اور برتر ہے۔ اگسٹ كانٹ كہتا ہے:
”تاريخ كي اجتماعى اور معاشرتيں صورتيں ايك ايسے دقيق علمي جبر كے تابع ہيں جو انسان معاشروں كے ناقابل اجتناب انقلاب كي صورت ميں انساني ذہن كے ترقياتي فرمان كے تحت ظاہر ہوتے ہيں ۔“(۵۸)
۶۔ تاريخي ميٹريالزم خود اپني تنسيخ كرتا ہے
تاريخي ماديت كي رو سے ہرفكر، ہر سوچ، ہر علمي يا فلسفي نظريہ اور ہر اخلاقى نظام چونكہ ايك خاص مادي اور معاشي شرائط كا نتيجہ ہے اور اپني مخصوص عيني شرائط سے وابستہ ہے، لہٰذا اس كي اپني كوئي مطلق حيثيت اور ساكھ نہيں ہو سكتي بلكہ اس كا تعلق اس كے اپنے خاص زمانے سے ہے اور جب وہ زمانہ بيت جاتا ہے اور مادي اور معاشي شرائط ميں تبديلي آجاتي ہے، جو جبري اور ناگزير ہوتي ہے، تو وہ فكر، وہ سوچ، وہ فلسفي يا علمي نظريہ اور وہ اخلاقى نظام بھي اپني صحت اور اپني افاديت كھو ديتا ہے اور اس كي جگہ دوسري فكر اور دوسرا نظريہ لے ليتا ہے ۔
اس بناء پر تاريخي ميٹريالزم بھي جو فلسفيوں اور بعض ماہرين عمرانيات كي طرف سے پىش كياگيا ہے، اسي كلي قانون كے دائرے ميں آتا ہے، كيونكہ يہ قانون اگر اس كے شامل حال نہ ہو تو پھر استثناء واقع ہوجاتا ہے۔ لہٰذا ايسا سائنسي اور فلسفي قانون يا قوانين موجود ہيں، جو اصالت ركھتے ہيں اور كسي معاشي بنياد كے تابع نہيں ہيں اور اگر خود اس قانون كے تابع ہے، تو پھر تاريخي ميٹريالزم قدر و قيمت، صحت اور افاديت كي رو سے فقط اس خاص اور محدود دور ميں صادق آتا ہے، جس ميں اس نے جنم ليا ہے، نہ اس سے پہلے كا دور اس كا ہوتا ہے اور نہ بعد كا۔ يہ تاريخي ميٹريالزم بہرحال نقص شدہ ہے، يعني تاريخي ميٹريالزم ايك تھيورى، ايك فلسفي نظريے اور بنياد كي بالائي تعمير كے عنوان سے يا تو اپنے غير ميں شامل ہے اور اپنے آپ ميں شامل نہيں كہ جس كي رو سے وہ خود اپني تنقيض كرنے والا ہے يا پھر خود اپنے ساتھ اپنے غير ميں بھي شامل ہے، ليكن ايك محدود دور كي قيد كے ساتھ، دوسرے ادوار ميں وہ نہ تو خود اپنے ميں شامل ہے اور نہ غير ميں۔عين يہي اعتراض جدلياتي پر بھي وارد ہے، جو اصول حركت اور اصول پىوستگي متقابل ہر چيز ميں حتيٰ كہ علمي اور فلسفي اصولوں ميں بھي شامل جانتا ہے اور ہم نے ”اصول فلسفہ اور روش ريالزم“ كي پہلي اور دوسري جلد ميں اس پر اچھي خاصي گفتگو كي ہے۔
يہاں سے يہ بات واضح ہوجاتي ہے كہ يہ جو كہا جاتا ہے كہ دنيا جدلياتي ماديت اور معاشرہ تاريخي ماديت كي نمائشگاہ ہے، كس قدر بے بنياد ہے، تاريخي ماديت پر دوسرے اعتراضات بھي عائد ہوتے ہيں۔ ہم في الحال اس سے صرف نظر كرتے ہيں، ميں حقيقتاً اظہار تعجب كئے بغير نہيں رہ سكتا كہ كوئي نظريہ اس حد تك بے اساس، بے بنياد اور غير سائنسي ہو اور اسي قدر اس كے سائنسي ہونے كا چرچا ہو، يہ سب پبلسٹي كے آرٹ كي كارفرمائي ہے ۔
____________________
۴.تفسير الميزان، جلد۴، ص۱۰۶.
۵.تفسير الميزان، جلد۴، ص۱۳۲ ۔۱۳۳.
۶.تفسير الميزان، جلد۴، ص۱۴.
۷.فلسفہ تاريخ ميں معروف صاحب نظر اور ماہر عمرانيات اسپنگلر كا قول جسے ”مراحل اساسي در جامعہ شناسي“ ميں ”ريمون آرون“ نے نقل كيا ہے، ملاحظہ ہو، ص۱۰۷.
۸. ڈارون كا مشہور نظريہ ”مترجم“.
۹.” تاريخ چيست؟“ ترجمہ فارسى: حسن كامشاد، مطبوعہ خوارزمى ، ص۸.
۱۰.ماركس اور ماركسزم، تاليف اينڈريو پىٹر، ترجمہ فارسى: شجاع الدين ضيائيان، ص۲۷ ، ۳۸، پانچواں ضميمہ.
۱۱.” تاريخ چيست؟“ ترجمہ فارسى: حسن كامشاد، مطبوعہ خوارزمى، ص۱۱۴، ۱۴۵.
۱۲.” تاريخ چيست؟“ ترجمہ فارسى: حسن كامشاد، مطبوعہ خوارزمى، ص۱۴۶.
۱۳.مراحل اساسي انديشہ در جامعه شناسي .فارسى.، ص۲۷.
۱۴.ماركس اور ماركسزم، تاليف اينڈريو پىٹر، ترجمہ فارسى: شجاع الدين ضيائيان، ص۳۹.
۱۵.ديكھئے: اصول فلسفہ وروش ريلزم، تقرير: علامه طباطبايى، تدوين: استاد شهيد مطہرى، جلد اول و دوم.
۱۶.ميٹريالزم تاريخى، تاليف: پى. رويان، ص۳۷.
۱۷.ديكھئے: قيام اور انقلاب مہدي از ديدگاہ فلسفہ تاريخ، تاليف استاد شهيد مطہرى.
۱۸.ماركس اور ماركسزم، تاليف اينڈريو پىٹر، ترجمہ فارسى: شجاع الدين ضيائيان، ص۴۰، ۴۱.
۱۹.مصدر سابق، ص۴۰، ۴۱.
۲۰.مصدر سابق، ص۳۹.
۲۱.فطرت كے بارے ميں مزيد تفصيل كے لئے ديكھئے اصول فلسفہ و روش رياليسم خصوصاً پانچواں مقالہ .پيدائش كثرت در ادراكات. نيز تفسير الميزان .ترجمہ فارسى. ج۱۶، ص۱۹۰ ”اخذ ميثاق“ كے بارے ميں بحث نيز استاد مطہري رحمۃ اللہ عليہ كي كتاب ”فطرت“ ديكھئے.
۲۲.ماركس و ماركسزم، ص ۲۴۶ .ضميمہ سوم. نيز ديكھئے، مراحل اساسي انديشہ در جامعہ شناسى، ص۱۶۳ اور تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو، ص۲۴۶.
۲۳.ماركس و ماركسزم، ۲۴۷۱، ضميمہ سوم.
۲۴.ماركس و ماركسزم، ص۳۳.
۲۵.ماركس و ماركسزم، ص۴۰.
۲۶.تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو، ص۱۵۳.
۲۷.تجديد نظرطلبي از ماركس تا مائو، ۱:۲۲۳، بحوالہ كتاب ”آثار برگزيدہ ماركس و انگلس“ ، ماركس اور اينجلز كے منتخب افكار.
۲۸.تجديد نظرطلبي از ماركس تا مائو، ص ۱۶۷.
۲۹.مصدر سابق، ص۱۵۵.
۳۰.مصدر سابق، ۱:۱۸۱.
۳۱.مصدر سابق، ص۱۹۸.
۳۲.مصدر سابق، ص۱۸۳.
۳۳.يعني صنعتي ممالك كي صنعت اور ٹيكنالوجي اور نتيجتاً ان كي سماجي عمارت ايك معين اور ناقبل انحراف راہ ميں آگے بڑھتي ہے، معاشروں كي راہ حركت ايك معين اور مخصوص راہ ہے، موجودہ ترقي يافتہ ممالك ہر اعتبار سے ان ممالك كے لئے نمونہ ہيں، جو ابھي اس مرحلے تك نہيں پہنچے، يہ بات ناممكن ہے كہ يہ ممالك صنعتي ممالك كے موجودہ مرحلے سے گزرے بغير كسي دوسرے راستے سے تكامل كي راہ طے كريں۔
۳۴.تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو، ۱:۲۲۵
۳۵.حقيقي طبيہ سے مراد گروہ ہے كہ جو مشترك معاشي زندگي اور مشترك مسائل كا حامل ہے، ليكن مزاجي طبقہ اس گروہ سے عبارت ہے جس كي زندگي ميں ہم آہنگي نہيں پائي جاتي اس كے باوجود وہ سب ايك آئيڈيالوجى كي پىروي كرتے ہيں۔
۳۶.تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو، ص ۳۴۵.
۳۷.ايدئولوژي آلمانى، ترجمہ فارسى، ۱:۶۱.
۳۸.تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو ، ص۳۴۷.
۳۹.مصدر سابق، ص۳۵۶.
۴۰.ديكھئے كتاب ”تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو“ صفحہ ۳۰۸ ، ۳۰۹، يہاں مذہب كے بارے ميں ماركس اور اينجلز كے مختلف نظريات نقل كئے گئے ہيں.
۴۱.تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو، ۳۱۹:۳۲۰
۴۲.مصدر سابق، ص۳۱۹، ۳۲۰.
۴۳.مصدر سابق، ص۳۴۰.
۴۴. ڈاكٹر انور رضامہ اي نے اس كتاب كو فرانسيسي زبان ميں لكھا اور پھر فارسى زبان ميں خود اس كا ترجمہ بھي كيا۔ ڈاكٹر صاحب نے اس سليبس ميں بڑي قابل تعريف كاوش كي ہے اور مسائل كے تحليل و تجزيہ ميں بڑي شائستگي سے كام ليا ہے، وہ برسوں اسي مكتب كے معتقد اور مبلغ رہے ہيں۔
۴۵. يہاں پر استاد شہيد مطہري رحمۃ اللہ عليہ كے ہاتھ كے لكھے ہوئے نسخے ميں غالباً اس كتاب سے نقل قول كئے لئے جو باحتمال قوي ”تاريخ جہاں باستان“ سے ہے، سات سطريں چھوڑ دي گئي ہيں، ہم نے مذكورہ كتاب كو ان كے كتاب خانہ ميں تلاش كرنے كي كوششيں كي تاكہ مخصوص علامات اور سياق موضوع سے نقل قول كو ان چھوڑي ہوئي سطروں ميں جگہ دي جائے، ليكن ہميں افسوس ہے كہ اس كتاب كي چوتھي جلد جو استاد شہيد مطہري رحمۃ اللہ عليہ كے استفادہ ميں رہي ہے، كتاب خانہ ميں موجود نہ تھى، اسي لئے ہميں ان خالي سطروں كو اسي طرح خالي چھوڑنا پڑا۔ہماري درخواست ہے كہ جن صاحب نے استاد مطہري رحمۃ اللہ عليہ كي لائبريري سے اس كتاب كو بطور امانت حاصل كيا ہے، اسے لوٹا ديں تاكہ بعد كي طباعت ميں ان اسناد كو پىش كيا جا سكے ۔.ناشر.
۴۶.تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو، ۱:۲۲۲.
۴۷.جيسا كہ مولف نے ياد دلايا ہے كہ يہاں اينجلز نے پىداوار اور زندگي كي حقيقي تجديد كے الفاظ استعمال كئے ہيں اور مادي و اقتصادي پىداوار كے نہيں كہے، جيسا كہ اينجلز نے كتاب”منشا خانوادہ، دولت، ماليت خصوصي“ميں وضاحت كي ہے كہ پىداوار فقط وسائل معيشت كي پىداوار نہيں بلكہ انسانوں كي پىداوار بھي اس ميں شامل ہے اس طرح اس نے گويا اشارتاً معاشيات كے فيصلہ كن عامل ہونے كي نفي كي ہے اور جنسي عامل كو بھي ساتھ شامل كيا ہے، يہ بھي تاريخي ماديت سے ايك طرح كا عدل ہے۔
۴۸.تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو، ص۲۸۱۔۲۸۲.
۴۹.ماركس و ماركسزم، ص ۲۴۵، يہ عذر گناہ بدتر از گناہ كے مصداق پر ايك طرح كي ڈھٹائي ہے يا كم از كم مصلحت پر حقيقت كو قربان كرنا ہے.
۵۰.تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو، ص۲۱۸، ۲۱۹.
۵۱.چہار رسالہ فلسفى، ص۵۴ - ۵۵.
۵۲.مصدر سابق، ص۵۴، ۵۵.
۵۳.ماركس و ماركسزم، ۲۴۳.
۵۴.تجديد نظر طلبي از ماركس تا مائو، ص۲۶۸.
۵۵.مصدر سابق، ص۳۴۸.
۵۶.مصدر سابق، ۱۷۲
۵۷.مصدر سابق، ص۲۳۹.
۵۸.عمرانيات ميں فكر كے اساسي مراحل، ص۱۰۲.
اسلام اور تاريخي ماديت
كيا اسلام تاريخي ماديت كا حامي ہے؟ كيا ان تاريخي واقعات كي توجيہ و تحليل ميں جو قرآن ميں آئے ہيں، قرآن كي منطق تاريخي ماديت پر مبني ہے؟بعض لوگوں كا خيال يہي ہے۔ ان كا دعويٰ ہے كہ ماركس سے كم از كم ہزار سال پہلے قرآن محمدي صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم ميں تاريخ كي توجيہ و تحليل اسي بنياد پر ہوئي ہے۔ عراق كے شيعہ اساتيد ميں ڈاكٹر علي الوردي جنہوں نے كئي ہنگامہ خيز كتابيں لكھي ہيں، جن ميں مشہور كتاب ”منزل العقل البشري“ بھي شامل ہے، انہي لوگوں ميں سے ہيں اور شايد يہ وہ پہلے شخص ہيں، جنہوں نے اس مسئلے كو چھيڑا ہے، آج كل بعض مسلمان صاحبان قلم كے نزديك زبان اسلام سے اس طرح كا تاريخي جائزہ ايك طرح كي روشن فكرى سمجھي جاتي ہے اور يہ اس دور كا ايك مشن ہوگيا ہے ۔
ہماري نگاہ ميں جو لوگ اس طرح سوچتے ہيں، وہ اسلام كو صحيح طرح سے سمجھ نہيں پائے يا تاريخي ماديت صحيح طور پر ان كے مطالعے سے نہيں گذري يا پھر دونوں كو سمجھنے سے قاصر ہيں ۔
تاريخي ميٹريالزم كے جن ”پانچ مباني“ اور ”چھ نتائج“ كي ہم پہلے تشريح كر چكے ہيں، وہ اسلامي منطق سے واقف افراد كو يہ بتانے كے لئے كافي ہے كہ اسلامي منطق اور تاريخي ماديت دو بالكل مختلف اور متضاد چيزيں ہيں ۔
معاشرے اور تاريخ كے بارے ميں يہ طرز فكر، خاص طور پر اس وقت جب اس پر جھوٹا اسلامي رنگ چڑھ جائے اور اسلام كي مہر تائيد اس پر ثبت ہوجائے، اسلامي كلچر، معارف اور نظريے كے لئے انتہائي خطرناك ہے۔ ہم يہ ضروري سمجھتے ہيں كہ جن مسائل نے اس توہم كو پيدا كيا ہے يا ممكن ہے، جن كي وجہ سے لوگ اس توہم كا شكار ہو كر يہ سمجھ بيٹھيں كہ اسلام اقتصاد كو معاشرے كي بنياد سمجھتا ہے اور تاريخ كي ہويت كو مادي گردانتا ہے، انہيں سامنے لائيں اور ان كا جائزہ ليں ۔
يہاں اس بات كي وضاحت بھي ضروري ہے كہ جن مسائل كو ابھي ہم پيش كريں گے، وہ ان سے كہيں زيادہ ہمہ گير ہيں، جنہيں خود انہوں نے پيش كيا ہے۔ ان افراد نے دو تين آيتوں اور دو تين حديثوں كا سہارا ليا ہے، ليكن ہم ان مسائل كو بھي پيش كريں گے، جنہيں ان لوگوں نے پيش نہيں كيا اور ممكن ہے بعد ميں كبھي انہيں دليل بنايا جائے ۔اس طرح ہم اپني بحث ايك جامع اور كامل صورت ميں آپ كے سامنے پيش كريں گے:
۱۔ قرآن نے بہت سے معاشرتي يا اجتماعي مسائل پيش كئے ہيں۔ معاشرتي بحثوں ميں ہم نے قرآن كے وہ الفاظ جو اجتماعي مفہوم ركھتے ہيں، تقريباً پچاس ذكر كئے تھے۔ قرآن كي ان آيات كے مطالعے سے جن ميں يہ الفاظ استعمال ہوئے ہيں، معاشرہ كچھ دو طبقاتي نوعيت كا دكھائي ديتا ہے۔ قرآن ايك طرف سے معاشرے ميں دو طبقاتي كيفيت كو مادي اساس پر يعني مادي استفادہ اور مادي محروميوں كي بنياد پر پيش كرتا ہے اور ان ميں سے ايك طبقے كو ” مََلَأ “ (صاحب جاہ و جلال و تمكنت) ”مستكبر“، ”مسرف“ اور ”مُترف“ اور دوسرے طبقے كو”مستضعف“ (ضعيف و كمزور قرار ديئے جانے والا، ”ناس“، عوام، ”ذريہ“ (چھوٹے، ناقابل وجہ اور ”ملا“ كے مقابل قرار پانے والے)، ”اراذل“ اور ”ارذلون“ (پست اور بے سروپا لوگ) (بہ تعبير قرآن اپني زبان سے نہيں بلكہ مخالفين كي زبان سے نقل كرتا ہے) كے عناوين سے ياد كرتا ہے اور ان دو طبقوں كو ايك دوسرے كے مقابل قرار ديتا ہے اور دوسري طرف معاشرے كي دو طبقاتي كيفيت كو معنوي مفاہيم كي بنياد پر پيش كرتا ہے، ان ميں سے ايك طبقہ كافروں، مشركوں، منافقوں، فاسقوں اور مفسدوں كا ہے اور دوسرے طبقے ميں مومنين، موحدين، متقين، صالحين، مجاہدين اور شہداء شامل ہيں۔ اگر ہم قرآن مجيد كي آيتوں پر غور كريں، جن ميں دو مادي اور دو معنوي طبقات كو پيش كيا گيا ہے، تو ہم ديكھيں گے كہ پہلے مادي طبقے، پہلے معنوي طبقے اور اسي طرح دوسرے مادي طبقے، دوسرے معنوي طبقے كے درميان ايك طرح كا تطابق پايا جاتا ہے، يعني كافروں، مشركوں، منافقوں كا گروہ مستكبروں، مسرفوں، مترفوں، طاغوتوں اور ملاء كے مفہوم ميں آنے والے لوگوں كا گروہ ہے، كوئي اور نہيں اور نہ يہ ہے كہ كوئي الگ گروہ ہو، ان سے اور ان كے علاوہ دوسرے لوگوں سے مركب ہو اور مومنين، موحدين، صالحين اور مجاہدين كا گروہ فقراء، مساكين، خدمت گار، مظلوم، اور محروم اور مستضعف لوگوں كا گروہ ہي ہے، كوئي اور نہيں اور نہ ان سے اور ان كے علاوہ دوسرے لوگوں سے تشكيل پانے والا كوئي گروہ ہے۔
پس مجموعي طور پر معاشرہ سے زيادہ طبقات كا حامل نہيں، ايك بہرہ مند، ظالم اور استعمار گر طبقہ، جس ميں تمام كافرين آتے ہيں اور دوسرا مستضعف گروہ جو مومنين سے مركب ہے اور اس سے يہ بات واضح ہوتي ہے كہ معاشرہ اس استضعاف گر اور استضعاف شدہ طبقوں ميں منقسم ہے اور اسي سے كافر اور مومنين گروہوں كي تشكيل ہوئي ہے۔ مستضعف بنانے كا عمل شرك، كفر، نفاق اور فسخ و فجور سے ابھرتا ہے اور استضعاف شدگي ايمان، توحيد، صلاح، اصلاح اور تقويٰ سے ظہور پذير ہوتي ہے، اس تطابق كي وضاحت كے لئے كافي ہے كہ ہم سورہ اعراف كي ان چاليس آيتوں كا مطالعہ كريں، جو انسٹھويں آيت ”لقد ارسلنا نو حا الي قومہ“ سے شروع ہو كر۱۳۷ويں آيت، ”ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومہ وما كانوا يعرشون“ پر ختم ہوتي ہيں، ان چاليس آيتوں ميں حضرات نوح، ہود، صالح، لوط، شعيب اور موسيٰ عليہ السلام كے واقعات كا تذكرہ ہے۔ ان تمام واقعات ميں (سوائے لوط عليہ السلام كے واقعہ كے) يہ بات ديكھنے ميں آتي ہے كہ ان تمام پيغمبروں پر ايمان لانے والے لوگ مستضعف طبقے سے تعلق ركھنے والے ہيں، جب كہ جنہوں نے ان كي مخالفت كي ہے اور كفر اختيار كيا ہے۔ ان كا تعلق ملاء و مستكبر طبقہ سے ہے۔(۵۹) اس تطابق كي سوائے طبقاتي وجدان كے جو تاريخي ماديت كا لازمہ اور اس كا مستلزم ہے، دوسري كوئي دليل و توجيح نہيں، پس درحقيقت قرآن كي روح سے ايمان اور كفر كي ايك دوسرے كے مقابل محاظ آرائي دراصل اس محاظ آرائي كا پرتو ہے، جو استضعاف شدگي اور استضعاف گري كے درميان واقع ہے۔
قرآن اس بات كي تصريح كرتا ہے كہ مالكيت جيسے وہ لفظ ”غنا“ سے تعبير كرتا ہے، طغيان اور سركشي كا باعث ہے، يعني يہ چيز تواضح، فروتني اور ”سلم“ كي ضد ہے، جسے قرآن يوں بيان كرتا ہے:
( ان الانسان ليطغي ان رآه استغنى ) . (سورہ علق، آيت ۔۷)
”اور جب انسان اپنے آپ كو بے نياز اور دولت مند محسوس كرنے لگتا ہے، تو باغي ہو جاتا ہے ۔“
پھر ہم كہتے ہيں كہ قرآن ”مالكيت“ كے بارے اثرات كو واضح كرنے كے لئے قانون كي داستان ذكر كرتا ہے:
”قارون قبطي نہيں سبطي تھا، يعني اس كا تعلق موسيٰ كي قوم سے تھا اور انہيں ميں سے تھا، جنہيں فرعون نے مستضعف بنايا ہوا تھا، ليكن يہي استضعاف شدہ شخص جب كسي نہ كسي طرح بہت زيادہ دولت كا مالك بن گيا، تو اسي مستضعف قوم كے خلاف كام كرنے لگا، جس ميں كل تك وہ خود تھا۔“
قرآن كہتا ہے:
( ان قارون كان من قوم موسيٰ فبغي عليهم ) .
”قارون، موسيٰ كي قوم كا ايك فرد تھا، جس سے بني اسرائيل كي اپني مستضعف قوم كے خلاف ظلم كيا ۔“
كيا يہ بات خود وضاحت نہيں كرتي كہ ظلم كے خلاف پيغمبروں كا قيام خود مالكيت، سرمايہ داري اور سرمايہ داري كے خلاف قيام تھا ۔
قرآن اپني بعض آيتوں ميں اس بات كي تصريح كرتا ہے كہ پيغمبروں كے مخالف ليڈروں كا تعلق ”مترفين“ كے طبقے سے تھا، يعني اس طبقے سے جو ناز و نعمت ميں غرق تھا ۔۴۳ ويں آيت ميں اس مفہوم كو ايك كلي اور بنيادي قانون كي صورت ميں پيش كيا گيا ہے:
وما ارسلنا في قريۃ من نذير الا قال مترفوھا انا بما ارسلتم بہ كافرون
”ہم نے كسي گروہ ميں كوئي ايسا ڈرانے والا نہيں بھيجا كہ وہاں كے مترفين نے جس كي مخالفت نہ كي ہو اور يہ نہ كہا ہو كہ ہم تمہاري رسالت اور تمہارے پيغام كے سرے سے مخالف اور انكاري ہيں ۔“
يہ تمام باتيں اس چيز كو ظاہر كرتي ہيں كہ انبياء اور ان كے مخالفين كي آپس ميں محاذ آرائي اور كفر و ايمان كي ايك دوسرے كے خلاف صف آرائي تھى، جو دراصل دو سماجي طبقوں استضعاف شدہ اور اشتضعاف گر كي جنگ تھي ۔
۲۔ قرآن نے اپنے مخاطبين كو ”ناس“ قرار ديا ہے اور ”ناس“ سے مراد عام اور محروم لوگ ہيں۔ قرآن كا يہ طريقہ اس بات كي دليل ہے كہ قرآن طبقاتي فكر كا قائل ہے اور دعوت اسلام كي قبوليت كا حامل، فقط محروم طبقے كو جانتا ہے اور اسلامي آئيڈيالوجي صرف اور صرف محروم طبقے كو مخاطب كرتي ہے۔ يہ ايك اور دليل ہے كہ اسلام كي نظر ميں اقتصاد معاشرے كي بنياد ہے اور تاريخ، مادي ہويت كي حامل ہے۔
۳۔ قرآن نے اس كي تصريح كي ہے كہ تمام مصلحين، تمام مجاہدين، تمام شہداء حتيٰ كہ تمام انبياء عليہم السلام عوام الناس كے درميان سے ابھرے ہيں، نہ كہ نعمتوں ميں غرق اور خوشحال طبقے سے۔ قرآن مجيد جناب رسول اكرم صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كے بارے ميں ارشاد فرماتا ہے:
( هوالذي بعث في الاميين رسولا ) (سورہ جمعہ، آيت۲)
”اسي نے لوگوں كے درميان جنہيں امت سے منسوب كيا گيا ہے، ايك رسول بھيجا۔ امت بجز محروم طبقے كے اور كوئي نہيں ۔“
اور اسي طرح شہداء راہ حق كے بارے ميں ارشاد ہوتا ہے:
( و نزعنا من كل امة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم ) . (سورہ القصص، آيت۷۵)
”يعني ہر امت ميں سے جو عوام الناس كا محروم طبقہ ہي ہے، ہم ايك شہيد كو اٹھائيں گے اور ان سے كہيں گے كہ اپني دليل اور اپنے گواہ ساتھ لاؤ ۔“
اقتصادي اور طبقاتي مقام كے ساتھ اعتقادي اور اجتماعي مقام كے تطابق كي ضرورت دراصل تحريكات اور انقلابات كے قائدين كو محروم طبقے ميں سے ابھارتي ہے اور يہ ضرورت صرف ہويت تاريخ كو ماديت اور اقتصاد كو بنياد قرار دينے كي صورت ميں ہي قابل توجيہ ہے۔
۴۔ قرآن كے مطابق انبياء عليھم السلام كے قيام كي ماہيت اور معاشرے كے لئے ان كي راہ متعين كرنا عمارت نہيں بلكہ خود بنياد ہے ۔
قرآن سے استنباط ہوتا ہے كہ انبياء عليہم السلام كي رسالت اور بعثت كا مقصد معاشرے ميں عدل، قسط، برابرى اور مساوات قائم كرنا اور طبقاتي فاصلوں اور ان كے درميان حائل ديواروں كو توڑنا ہے۔ تمام انبياء عليہم السلام ہميشہ بنياد سے چل كر، جو ان كي بعثت كا مقصد رہا ہے۔ عمارت تك پہنچے ہيں، عمارت يعني عقائد، ايمان، اخلاقي اصطلاحات اور راہ و روش، انبياء عليہم السلام كا دوسرا مقصد رہے ہيں، جس كے لئے وہ بنياد كي اصلاح كے بعد جستجو كرتے ہيں۔ جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا:
من لا معاش له لا معادله
”جس كے پاس معاش اور مادي زندگي نہيں ہے، اس كے پاس معنوي زندگي كا سرمايہ معاد بھي نہيں ۔“
يہ جملہ معاد و آخرت پر معاش اور معنوي زندگي پر مادي زندگي كے تقدم كو ظاہر كرتا ہے اور معنوي زندگي كو عمارت اور مادي زندگي كو بنياد كے عنوان سے پيش كرتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كي ايك اور حديث يہ بھي ہے:
اللهم بارك لنا في الخبز، لو لا الخبز ما تصدقنا ولا اصلينا
”خداوندا! ہماري روٹي ميں بركت دے كہ اگر روٹي نہيں، تو زكوٰۃ ہے، نہ نماز ۔“
يہ جملہ بھي معنويت كي ماديت سے وابستگي اور اس كي ثانويت كو ظاہر كرتا ہے ۔
آج اكثر لوگوں كا خيال ہے كہ انبياء عليہم السلام كي كوششيں صرف عمارت كي حد تك رہي ہيں۔ وہ لوگوں كے عقيدہ، اخلاق اور رفتار و كردار كو سنوارنا چاہتے تھے اور انہيں مومن بنانا چاہتے تھے۔ بنياد سے انہيں كوئي غرض نہ تھي اور يا بنيادي امور كي حيثيت ان كے نزديك ثانوي تھي يا پھر وہ يہ چاہتے تھے كہ لوگ مومن اور معتقد بنيں۔ ان كا خيال تھا كہ جب لوگ ايمان اور اعتقاد ميں پختہ ہو جائيں گے تو پھر تمام كام خود بخود سنورنے لگيں گے۔ عدالت اور مساوات كا بول بالا ہوگا، استحصال پسند لوگ درست ہوجائيں گے اور محروموں اور مستضعفوں كے حقوق خود اپنے ہاتھ سے انہيں ديں گے۔ غرض يہ كہ انبياء عليہم السلام نے اپنے ايمان اور عقيدے كے زور سے تمام مقاصد ميں كاميابي حاصل كي ہے اور ان كے پيروكاروں كے لئے بھي ضروري ہے كہ وہ ان كي راہ اختيار كريں۔ يہ خيال اور سوچ ايك فريب اور دھوكا ہے، جسے استحصال پسند افراد اور ان سے وابستہ علماء نے انبياء عليھم السلام كي تعليمات كو بے اثر كرنے كے لئے گھڑ كر اس معاشرے پر ٹھونسا ہے كہ اب لوگوں كي اكثريت ان باتوں پر يقين كرنے لگي ہے۔ بقول ماركس:
”جو لوگ مادي مصنوعات برآمد كرتے ہيں، وہ معاشرے كے لئے فكرى مصنوعات برآمد كرنے كي صلاحيت بھي ركھتے ہيں، جن كے ہاتھ ميں معاشرے كي باگ دوڑ ہوتي ہے، وہ معاشرے كي سوچ پر بھي حكومت كرتے ہيں اور معنوي فرمانروائي بھي ان كے ہاتھ ميں ہوتي ہے ۔“ (جرمن آئيڈيالوجي)انبياء عليھم السلام كا طريقہ كار اور ان كا ميتھڈ ( Method ) اكثريت كي موجودہ سوچ كے بالكل برعكس رہا ہے۔ انبياء عليھم السلام نے پہلے معاشرے كو اجتماعي شرك، بے جا امتيازات، استحصال اور استضعاف شدگي جيسے اخلاقى، عملي اور اعتقادي شرك سے نجات دلائي اور اس كے بعد اعتقادي توحيد اور اخلاقي اور عملي تقويٰ تك پہنچے۔
۵۔ قرآن انبياء عليھم السلام كے مخالفين كي منطق كو پوري تاريخ ميں انبياء عليھم السلام اور ان كے پيروكاروں كي منطق كے مقابل قرار ديتا ہے۔وہ بڑي وضاحت سے اس بات كي نشاندہي كرتا ہے كہ مخالفين كي منطق ہميشہ سے قدامت پرستانہ، روايت پسندانہ اور رجعت پسندانہ رہي ہے، جب كہ انبياء عليھم السلام اور ان كے پيروكار مخالفين كے برعكس ہميشہ تجدد پسند، روايت شكن اور مستقبل پر نظر ركھنے والے رہے ہيں۔
قرآن واضح كرتا ہے كہ پہلے گروہ نے ہميشہ وہي منطق استعمال كي ہے جسے عمرانيات كي رو سے استحصال گر اور استحصال شدہ طبقوں ميں بٹے ہوئے معاشرے ميں استحصال گر طبقہ اپنے مفاد كے پيش نظر استعمال كرتا ہے، ليكن انبياء عليھم السلام اور ان كے ماننے والوں كي منطق وہي رہي ہے، جو تاريخ كے محروم اور مظلوم لوگوں كي منطق ہے ۔
قرآن كا گويا يہ التفات ہے كہ اس نے گذشتہ سے متعلق مخالفين اور موافقين كي منطق كو ہمارے لئے پيش كيا ہے اور بتايا ہے كہ ان دونوں گروہوں كي منطق كيا تھي۔ صرف اس لئے كہ يہ دونوں نقطہ ہائے نظر خود ان دو گروہوں كي طرح پوري تاريخ ميں آج تك ايك دوسرے كے سامنے كھڑے رہے ہيں اور قرآن مخالفين اور موافقين كي منطق كو آشكار كر كے آج كے لئے ہمارے سامنے ايك معيار پيش كرنا چاہتا ہے۔
قرآن ميں ايسے بہت سے مقامات كا ذكر ہے، جہاں يہ دونقطہ ہائے نظر ايك دوسرے كے آمنے سامنے آتے رہتے ہيں۔ اہل تحقيق سورہ زخرف كي چاليسويں سے پچاسويں آيت تك سورہ مومن كي۲۳ويں سے ۴۴ويں آيت تك، سورہ طہٰ كي ۴۹ويں سے ۷۱ ويں آيت تك، سورہ شعراء كي ۱۶ويں سے ۴۹آيت تك اور سورہ قصص كي ۳۶ويں سے ۳۹ويں آيت تك كي طرف اس موضوع كے سلسلے ميں رجوع فرما سكتے ہيں۔ يہاں ہم سورہ زخرف كي ۲۰سے ۲۴ تك كي آيتوں كو بطور نمونہ ذكر كر كے ان كے بارے ميں كچھ وضاحت پيش كرنا چاہتے ہيں:
( وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم، ما لهم بذالك من علم ان هم الا يخرصون؛ ام آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون؛ بل قالوا انا وجدنا آبائنا علي امة وانا علي آثارهم مهتدون؛ وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا ابائنا علي امة وانا علي اثارهم مهتدون قال اولو جئتكم باهدي مما وجدتم عليه آبائكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون. )
”اور انہوں نے كہا، اگر خدا چاہتا ہے كہ ہم فرشتوں كي عبادت نہ كريں تو ہم نہيں كرتے (ليكن اب جو كر رہے ہيں، اس سے معلوم ہوتا ہے كہ خدا كي مرضي يہي ہے، يعني مطلق جبر)يہ لوگ اس قسم كي (جبر پسندانہ) گفتگو از روئے دانائي و ادراك يا علمي و منطقي بنياد پر نہيں كرتے، يہ تو صرف فرض و تخمين سے كام ليتے ہيں۔ كيا ہم نے اس سے پہلے ان كے لئے كوئي ايسي آسماني كتاب نازل كي ہے، جس ميں كسي قسم كي جبريت پر مبني بات ہو اور انہوں نے اسے اختيار كيا ہو (ايسا كچھ بھي نہيں، اس ميں نہ كسي سنجيدہ جبري اعتقاد كا دخل ہے اور نہ كوئي ايسي آسماني كتاب ہے، جسے اس سلسلے ميں دليل بنايا جا سكے) بلكہ ان كا اصلي قول يہ ہے كہ ہم نے اپنے باپ دادا كو جس راہ پر چلتے ديكھا ہے، بس وہي ہماري راہ ہے ۔“
(پيغمبر صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم نے) ان سے فرمايا:
”اب اگر ميں تمہارے لئے كوئي ايسي راہ اور كوئي ايسا طريقہ پيش كروں، جو تمہارے باپ دادا كي راہ سے بہتر اور برتر ہو، تو (كيا يہ جانتے ہوئے كہ منطقي اعتبار سے ميرا راستہ زيادہ صحيح اور زيادہ اصولي ہے) پھر بھي تم اپنے باپ، دادا كي روش پر قائم رہو گے؟انہوں نے كہا: ہم بہرحال تمہارے پيغام اور تمہارے رسالت كے منكر ہيں۔“
ہم ديكھ رہے ہيں كہ انبياء عليھم السلام كے مخالفين بعض اوقات اس جبري منطق اور جبري قضاء و قدر كے نظريے سے كام ليتے ہيں، جس كے مطابق ہمارا كوئي اختيار نہيں، جيسا كہ عمراني حوالے سے پتہ چلتا ہے كہ يہ منطق موجود حالت سے ان فائدہ اٹھانے والوں كي منطق ہے، جو نہيں چاہتے كہ حالات ميں كسي قسم كي تبديلي واقعہ ہو اور اسي لئے وہ قضاء و قدر كو بہانہ بناتے ہيں اور كبھي يہ باپ دادا كي سنت كا سہارا ليتے ہيں اور گذشتہ دور كو مقدس اور قابل پيروي گردانتے ہيں اور گذشتہ سے كسي چيز كے تعلق كو ہدايت يافتہ اور صحيح ہونے كے لئے كافي سمجھتے ہيں۔ ہميشہ سے قدامت پسند اور حالات سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں كي يہي منطق رہي ہے ۔
ان كے مقابلے پر انبياء عليھم السلام روايت پرستي اور جبر پسندي كي بجائے زيادہ منطقى، زيادہ علمي اور زيادہ نجات بخش بات كرتے رہے ہيں، موجودہ حالات سے بيزار اور انقلابي لوگوں كي منطق ہے۔ انبياء عليھم السلام كي پيش كردہ حجت و دليل كے مقابل مخالفين كي بن نہيں پڑتى، تو پھر وہ آخري بات كرتے ہيں اور كہتے ہيں، بہرحال جبر ہو يا نہ ہو، روايتوں كا احترام كريں يا نہ كريں، تمہارا پيغام، تمہاري رسالت اور تمہاري آئيڈيالوجي ہمارے لئے ناقابل قبول ہے آخر كيوں؟ اس لئے كہ تمہارا پيغام ہماري طبقاتي اور اجتماعي موجوديت كي ضد ہے ۔
۶۔ مستضعفين اور مستكبرين كے جھگڑے ميں قرآن كا سب سے روشن اور سب سے واضح فيصلہ يہ ہے كہ كاميابي (جيسا كہ تاريخي ماديت، جدلياتي نظريے كي بنياد پر خوشخبري ديتي ہے) مستضعفين كے لئے ہے۔ قرآن اپنے اس فيصلے ميں تاريخ كے جبري اور لازمي راستے كو پيش كرتا ہے اور بتاتا ہے كہ وہ طبقہ جو بالذات انقلابي خصلت كا حامل ہے، اس طبقے كے ساتھ اپنے جھگڑے ميں كہ جو بالذات اور اپنے طبقاتي موقف كي بناء پر قدامت پسند واقع ہوا ہے، كاميابي سے ہمكنار ہوگا اور زمين كا وارث بنے گا۔
( ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ) . (سورہ قصص، آيت۵)
”ہم نے يہ ارادہ كر ليا ہے كہ مستضعفين پر احسان سے كام ليں اور انہيں پيشوا اور زمين كا وارث قرار ديں ۔“
سورہ اعراف كي ۱۳۷ويں آيت ميں بھي يہي بات ہے:
( واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت كلمة ربك الحسني علي بني اسرائيل بما صبروا و دمّرنا ماكان يصنع فرعون و قومه وما كانوا يعرشون ) .
”ہم نے موعودہ بركت والي سرزمين كو ايك كنارے سے دوسرے كنارے تك ان لوگوں كے حوالے كيا، جنہيں زمين پر كمزور بنا ديا گيا تھا ۔
بني اسرائيل كے بارے ميں اللہ كا وعدہ ان كے صبر كے مظاہرے كي بناء پر بحسن خوبي پورا ہوا اور جو كچھ فرعون اور اس كي قوم نے انجام ديا تھا، ان كي تمام بنائي اور پيش كي ہوئي چيزوں كو ہم نے نيست و نابود كر ديا ۔“
قرآن كا يہ نظريہ كہ تاريخ كا دھارا محروم، مصيبت زدہ اور استحصال شدہ لوگوں كي كاميابي كي راہ ميں آگے بڑھتا ہے، مكمل طور پر اس اصول پر منطبق، جسے ہم نے پہلے ماديت تاريخ سے اخذ كيا تھا كہ رجعت پسندي اور فرسودہ خيالي استحصال پسندي كي ذاتي خصلتيں ہيں اور چونكہ يہ خصلتيں عالم خلقت كي تكاملي روايات كے خلاف ہيں، لہٰذا مٹنے والي ہيں، ليكن استحصال شدگي كي ذاتي خصلت، روشن فكرى، حركت اور انقلاب ہے اور چونكہ يہ خصلت خلقت كي تكاملي روايات سے ہم آہنگ ہے، اس لئے كامياب ہ ے۔
يہاں ايك مقالے كے ايك حصے اور اس سے حاصل شدہ نتائج كا تذكرہ مناسب نہيں ہوگا جسے روشن فكر مسلمانوں نے مرتب كيا ہے اور ايك كتابچے كي شكل ميں حال ہي ميں شائع كيا ہے۔ يہ گروہ روشن فكرى سے بھي آگے بڑھ گيا ہے اور ماركس زدہ ہوگيا ہے۔ اس مقالہ ميں مذكورہ بالا آيت كو عنوان قرار دے كر نيچے لكھا ہے:
”۔۔۔ يہاں سب سے زيادہ جاذب توجہ چيز اللہ اور تمام مظاہر وجود كا مستضعفين كے حق ميں موقف اختيار كرنا ہے، اس ميں كوئي شك نہيں كہ زمين كے مستضعف يا كمزور لوگ قرآني نظريے كي بنياد پر ايك ايسا محروم و بے بس طبقہ ہے، جو اپني تقدير كے بارے ميں جبري اور قہري اعتبار سے كسي كردار كا حامل نہيں ۔۔۔ اس مفہوم كو سامنے ركھتے ہوئے، نيز اللہ اور اس كے تمام مظاہر وجود كے موقف كو ديكھتے ہوئے، يعني وجود پر اس كے مطلق ارادے كي حكمراني اور احسان كے پيش نظر سوال پيدا ہوتا ہے كہ آخر وہ كون لوگ ہيں، جو اس كے ارادے كو عملي جامہ پہنانے والے ہيں؟ اس سوال كا جواب بڑا واضح ہے۔ جب ہم معاشرے كو كمزور اور طاقت ور طبقوں ميں تقسيم كرتے ہيں اور پھر يہ بھي جانتے ہيں كہ خداوند عالم كا ارادہ ايك طرف تو زمين ميں كمزور افراد كي وراثت و امامت سے پورا ہوتا ہے اور دوسري طرف استحصالي يا طاقت ور نظام كي تباہي اس كے مقصد كو پورا كرتي ہے، تو پھر صاف ظاہر ہوتا ہے كہ ارادہ الٰہي كو نمود عيني بخشنے والے لوگ يہي مستضعفين، ان كے انبياء عليھم السلام اور وہ باعزم روشن فكر افراد ہيں، جو انہي ميں سے اٹھتے ہيں۔ ايك اور بيان كے مطابق مستضعفين كے درميان سے چنے گئے يہي وہ انبياء عليھم السلام(۶۰) اور شہداء(۶۱) ہيں، جو طاغوتي اور غارت گر نظام سے ٹكرانے كے لئے پہلا قدم اٹھاتے ہيں اور يہ وہ قدم ہوتا ہے، جو مستضعفين كو امامت اور وراثت تك پہنچانے كے لئے راہ ہموار كرتا ہے، يہ مفہوم درحقيقت توحيدي انقلابات اور تاريخي تبديليوں كے بارے ميں ہماري شناخت كا انعكاس ہے(۶۲) اور وہ يوں ہے كہ جس طرح توحيدي انقلابات اجتماعي اعتبار سے زمين پر مستضعفين كي امامت اور ان كي وراثت كے گرد گھومتے ہيں، اسي طرح اس تحريك كے رہبروں اور اس كام ميں سبقت لے جانے والوں كے لئے بھي ضروري ہے كہ وہ مستضعفين ميں سے ہوں اور معاشرے كا موقف اور اس كي آئيڈيالوجي بھي مستضعفين ہي كا موقف اور ان كي آئيڈيالوجي ہو ۔“
الف) قرآن كي رو سے معاشرہ دو طبقات پر مشتمل ہے اور ہميشہ استحصالي اور استحصال شدہ طبقوں ميں تقسيم ہوتا ہے۔
ب) ارادہ الٰہي (كہ جو اس مقالہ كي رو سے خدا اور تمام مظاہر وجود كي طرف سے موقف اختيار كرنے سے عبارت ہے) يہ ہے كہ مستضعفين اور تاريخ كے بے بس لوگوں كو بطور كلي امامت و وراثت عطا كرے ۔
اس ميں موحد، مشرك، بت پرست اور مومن وغيرمومن كي كوئي قيد و شرط نہيں، يعني آيت ميں لفظ ”والذين“ استغراق كے لئے ہے اور عموميت ركھتا ہے اور سنت الٰہي استحصال كرنے والے پر مستضعف كي مستضعف ہونے كے ناطے كاميابي سے عبارت ہے۔ باالفاظ ديگر وہ جھگڑا جو پوري تاريخ كا احاطہ كئے ہوئے ہے، اس كي اصلي ماہيت محرومين اور ستم گروں كا ايك دوسرے كے ساتھ مناقشہ ہے اور كائنات كا تكاملي قانون يہ ہے كہ محروم لوگ ستم گروں پر كاميابي حاصل كريں ۔
ج) ارادہ الٰہي خود معاشرے كے مستضعفين كے ذريعے پورا ہوتا ہے اور تمام رہبر، تمام پيشوا، تمام پيغمبر اور تمام شہداء لازمي طور پر مستضعف طبقے سے ابھرتے ہيں، كسي اور طبقہ سے نہيں ۔
د) ہميشہ فكرى مركزوں، اجتماعي بنيادوں اور طبقاتي موقفوں كے درميان تطابق اور ہم آہنگي پائي جاتي ہے ۔
پس ہم ديكھتے ہيں كہ اس آيت سے كس طرح تاريخ كے بارے ميں كئي ماركسي اصول نكلتے ہيں اور كس طر ح قرآن نے ماركس سے۱۲۰۰ پہلے اس فكر اور اس كے فلسفے كو قلم بند كيا ہے؟
اب جب كہ تاريخ كے بارے ميں اس طرح كا نام نہاد قرآني نظريہ برآمد ہوا ہے، تو ہم اپنے دور كي تاريخ كے تجربے ميں اس نظريے سے كيا نتيجہ اخذ كر سكتے ہيں؟ ان حضرات نے بطور نمونہ ايك فوري امر كي صورت ميں اس نام نہاد قرآني اصول كے سہارے نتيجہ حاصل كرنے كي كوشش كي ہے اور علماء كي موجودہ تحريك سے آزمائش كے طور پر استفادہ كيا ہے۔ وہ كہتے ہيں، قرآن نے ہميں تعليم دي ہے كہ انقلاب كے رہبروں اور پيشواؤں كو لازمي طور پر مستضعف طبقے سے ہونا چاہيے۔ ليكن آج ہم ديكھتے ہيں كہ وہ علماء جو تاريخ كو تباہي سے ہمكنار كرنے والي مثلث كا ايك كونہ تھے، آج اپني اجتماعي پوزيشن بدل كر انقلابي ہوگئے ہيں، تو پھر معاملے كو كس طرح حل كيا جائے؟ آسان سي بات ہے، ہميں سختي كے ساتھ بغير ہچكچاہٹ كے اعلان كرنا ہوگا كہ دال ميں كچھ كالا ہے۔ حكمران طبقے نے اپنے آپ كو معرض خطر ميں ديكھ كر اپنے سے وابستہ علماء كو يہ حكم ديا ہے كہ وہ انقلابي كردار ادا كريں تاكہ اس طرح ان كي كرسي بچ جائے۔ يہ ہے وہ نتيجہ جو ماركسي نظريہ (معاف كيجئے گا بقول ان كے قرآني نظريہ) سے حاصل ہوا ہے اور يہ بات واضح ہے كہ اس كا فائدہ كسے پہنچ رہا ہے؟
اعتراض
ماديت تاريخ كي توجيہ ميں قرآن كي نسبت جو كچھ بھي كہا گيا ہے، وہ غلط ہے۔گذشتہ دلائل كا ہم ايك دفعہ پھر جائزہ لينا چاہتے ہيں:
اولاً: يہ بات خالص جھوٹ ہے كہ قرآن نے معاشرے كو دو مادي اور دو معنوي طبقات ميں تقسيم كيا ہے۔ يہ دو طبقے ايك دوسرے كے ساتھ مطابقت ركھتے ہيں، يعني قرآن كي رو سے كافرين، مشركين، منافقين، فاسقين اور مفسدين ہي ملاء، مستكبر اور جابر افراد ہيں اور اس كے برعكس مومن، موحد، صالح اور شہداء ہي مستضعف اور محروم طبقے ميں آتے ہيں۔ كافروں اور مومنوں كي آويزش ميں بنيادي طور پر ظالموں اور مطلوموں كے اختلاف كا انعكاس ہے۔ ہرگز ايسي كوئي مطابقت قرآن سے سمجھ ميں نہيں آتي بلكہ عدم مطابقت ظاہر كرتي ہے ۔
قرآن اپنے تذكرہ تاريخ ميں ايسے مومنوں كو پيش كرتا ہے، جنہوں نے ملاء و مستكبر طبقے سے ابھر كر اسي طبقے كے خلاف اور اس كي اقدار كے خلاف قيام كيا۔ مومن آل فرعون جس كا واقعہ اسي نام سے منسوب ايك سورہ، يعني سورہ ”مومن“ ميں آيا ہے، انہي مثالوں ميں سے ايك ہے، اس كے علاوہ فرعون كي بيوي جو فرعون كي شريك حيات تھي اور كوئي ايسي نعمت نہيں تھى، جس سے فرعون بہرہ مند نہ ہو اور يہ واقعہ بھي انہي واقعات ميں سے ہے، جس كي قرآن نے نشان دہي كي ہے۔ (سورہ تحريم، آيت۱۱)
قرآن نے فرعون كے جادوگروں كے بارے ميں كئي مقامات پر بڑے ولولہ خيز انداز ميں تذكرہ كيا ہے اور يہ بتايا ہے كہ كس طرح انسان كي فطرى حق جوئي اور حقيقت خواہى، حق و حقيقت كے ساتھ جھوٹ، زور، زبردستي اور گمراہي كے خلاف شورش كرتي ہے، اپنے مفادات كو ٹھوكر لگا ديتي ہے اور فرعون كي اس دھمكي سے نہيں ڈرتي كہ وہ ان كے ايك طرف كا ہاتھ اور دوسري طرف كي ٹانگ كاٹ كر سولي پر چڑھا دے گا۔
بنيادي طور پر حضرت موسيٰ عليہ السلام كا قيام از روئے قرآن ايك ايسا قدم ہے، جو ماديت تاريخ كي تنسيخ كرتا ہے، يہ ٹھيك ہے كہ حضرت موسيٰ عليہ السلام قبطي نہيں سبطي تھے ، مثلاً بني اسرائيل ميں سے تھے۔ آل فرعون سے ان كا تعلق نہيں تھا، ليكن وہ بچپن ہي سے فرعون كے گھر پروان چڑھے اور شہزادوں كي طرح ان كي پرورش ہوئى، اس كے باوجود انہوں نے اس فرعوني نظام كے خلاف بغاوت كي جس ميں وہ خود زندگي گذار رہے تھے۔ اس كي دي ہوئي آسائشوں سے بہرہ مند تھے، انہوں نے ان تمام آسائشات كو ترك كر ديا اور مدين كے ايك بزرگ كي گلہ باني كو اپني شاہزادگي پر ترجيح دي۔ يہاں تك كہ مبعوث برسالت ہوئے اور باضابطہ طور پر فرعون كے مقابل آكھڑے ہوئے۔
جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم بچپن ميں يتيم اور آغاز جواني تك غريب تھے۔ جناب خديجہ الكبريٰ سے شادي كے بعد آپ صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كي مالي حالت سنبھلي اور آپ صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم خوشحال ہوئے۔ قرآن مجيد اسي نكتے كي طرف اشارہ كرتا ہے اور كہتا ہے:( الم يجدك يتيما فاوي و وجدك ضالا فهدي و وجدك عائلا فاغني )
يہي خوشحالي كا زمانہ تھا، جب آپ صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم نے عبادت و خلوت اختيار كي۔ تاريخي ماديت كے اصول كے مطابق جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كو اس زمانے ميں ايك قد امت پسند فرد بن جانا چاہيے تھا، جو موجودہ حالت ہي پر راضي رہتا، ليكن يہي وہ دور تھا، جس ميں آپ صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم نے اپني تحريك كا آغاز كيااور مكہ كے سرمايہ داروں، سود خوروں، بردہ داروں اور اس بت پرستانہ نظام كے خلاف علم بلند كيا، جو اس زمانے كي زندگي كي علامت تھے۔ اسي طرح مومنين، موحدين اور توحيد پرست انقلابي سب كے سب مستضعفين ميں سے نہيں تھے، انبياء عليھم السلام استحصالي طبقوں ميں سے ان بيدار فطرت افراد كو بھي نكال لائے تھے، جو كھوٹ سے عاري تھے يا پھر نسبتاً ان ميں كم كھوٹ پايا جاتا تھا اور انہيں اپنے خلاف (عمل توبہ ميں) يا اپنے طبقے كے خلاف (انقلابي عمل ميں) ابھارتے تھے۔ مستضعفين كا طبقہ بھي تمام كا تمام مومنين اور توحيد پرست انقلابيوں كے زمرے ميں نہيں رہا ہے ۔
قرآن ميں ايسے مختلف مقامات ہيں، جہاں اس نے مستضعفين كے بعض گروہوں كي مذمت كي ہے اور انہيں كافروں كے زمرے ميں قرار دے كر مشمول عذاب گردانا ہے۔(۶۳)
پس نہ تمام مومنين كا تعلق مستضعف طبقے سے ہے اور نہ ہي تمام مستضعف مومنين كے طبقے ميں سے ہيں اور يہ مطابقت محض خالي اور بے معني دعويٰ ہے۔ البتہ يہ بات اپني جگہ درست ہے كہ بلاشبہ انبياء عليھم السلام پر ايمان لانے والے طبقے كي اكثريت كا تعلق ہميشہ مستضعف طبقے سے يا كم از كم اس طبقے سے رہا ہے، جو استحصال كرنے سے دور رہا ہے اور ان كے مخالفين كي اكثريت ان لوگوں كي رہي ہے، جو استحصال كرنے والے تھے، كيونكہ انسان فطرت ميں قبوليت كي جو صلاحيت ركھي گئي ہے۔ اگرچہ وہ سب ميں مشترك ہے اور ہر ايك ميں پائي جاتي ہے، ليكن كھوٹ اور موجودہ حالت كا عادي ہوجانے نے استحصالي سرمايہ دار اور خوشحال طبقے كے سامنے ايك ركاوٹ كھڑي كر دي ہے۔ ضرورت اس بات كي ہے كہ وہ اپنے آپ كو ان آلودگيوں كے انبار سے باہر نكاليں اور يہ ايك مشكل كام ہے اور بہت كم لوگوں كو اس ميں كاميابي نصيب ہوتي ہے، ليكن مستضعف طبقے كے سامنے ايسي كوئي چيز حائل نہيں، بلكہ وہ فطرت كي آواز پر لبيك كہنے كے علاوہ اپنے ان حقوق كو بھي حاصل كر ليتا ہے، جو اس سے چھن گئے تھے۔ان كا اہل ايمان كے گروہ سے ملحق ہونا ہم خرما، ہم ثواب كے مصداق ہے، يہي وجہ ہے كہ انبياء عليھم السلام پر ايمان لانے والوں كي اكثريت مستضعفين سے ہے جو غير اقليت ميں ہيں، ليكن مذكورہ صورت ميں تطابق اور مطابقت محض لغو اور بے معني ہے ۔
تاريخي ميٹريالزم كي بنيادوں اور ہويت تاريخ كے بارے ميں ميں قرآني نقطہ نظر كے درميان بڑا فرق ہے۔ بااعتبار قرآن روح ايك اصالت كي حامل ہے اور مادہ روح پر كسي طرح كا تقدم نہيں ركھتا۔ معنوي ضرورتيں اور معنوي ميلانات انساني وجود ميں اصالت كي حامل ہيں اور مادي ضرورتوں سے ان كي كوئي وابستگي نہيں، اسي طرح فكر بھي كام كے مقابل اصالت ركھتي ہے ۔
انسان كي روحاني و فطرى حيثيت اس كي اجتماعي حيثيت پر فوقيت ركھتي ہے۔ چونكہ قرآن فطرى اصالت كا قائل ہے اور ہر انسان كے اندر حتيٰ فرعون جيسے مسخ شدہ انسانوں ميں بھي ايك بالفطرت مقيد انسان كو ديكھتا ہے اور مسخ ترين انسانوں ميں بھي حق و حقيقت كي طرف ميلان كو ممكن جانتا ہے، اگرچہ يہ ميلان خفيف سا كيوں نہ ہو، اسي لئے پيغمبران الٰہي كا كام پہلے درجے ميں يہ تھا كہ وہ ظالموں اور ستم گروں كو نصيحت كرتے رہيں كہ شايد اس عمل سے ان كے اندر كا مقيد انسان اپني بندشوں كو توڑ كر باہر نكل آئے اور پليد اجتماعي حيثيت كے خلاف ان كي فطرى حيثيت كو بيدار كر لے اور ہم ديكھ چكے ہيں كہ بہت سے موارد ميں يہ كاميابي حاصل ہوئي ہے اور ”توبہ“ اسي كا نام ہے ۔
جناب موسيٰ عليہ السلام كو اپني رسالت كے پہلے مرحلے ميں يہ حكم ملا كہ فرعون كے پاس جائيں اور پہلے پند و نصيحت سے اس كي سوئي ہوئي فطرت كو بيدار كريں اور اگر اس ميں كاميابي نہ ہو، تو پھر مقابلے پر اتر آئيں۔ جناب موسيٰ عليہ السلام كي نظر ميں فرعون نے ايك انسان كو اپنے اندر اور بہت سے انسانوں كو باہر كي دنيا ميں قيد كر ركھا تھا۔ حضرت موسيٰ عليہ السلام نے پہلا كام يہ كيا، انہوں نے فرعون كے اندر چھپے ہوئے مقيد انسان كو اس كے خلاف ابھارا۔ دراصل جناب موسيٰ عليہ السلام اس فطرى فرعون كو كہ جو ايك انسان يا كم از كم اس كا بچا كھچا حصہ تھا، اسے اس اجتماعي حيثيت كے حامل فرعون كے خلاف ابھارنے پر مامور ہوئے تھے ۔
( اذهب الي فرعون انه طغي فقل هل لك الي ان تزكي و اهديك الي ربك فتخشيٰ )
قرآن ہدايت، ارشاد، تذكر، موعظہ، برہان اور منطقي استدلال (قرآن كي اصطلاح ميں حكمت) كے لئے اہميت اور قوت كا قائل ہے۔ قرآن كي رو سے يہ امور انسان كو متغير كر سكتے ہيں۔ اس كي زندگي اور شخصيت كو بدل سكتے ہيں اور اس ميں ايك معنوي انقلاب پيدا كر سكتے ہيں۔ قرآن فكر اور آئيڈيالوجي كے كردار كو محدود نہيں جانتا۔ اس كے برعكس ماركسزم اور ماديت قيادت اور ہدايت كے كردار كو في نفسہ طبقہ كے لنفسہ طبقہ ميں تبديل ہونے تك محدود جانتا ہے، يعني طبقاتي تضادات كو خود آگاہي كي منزل تك پہنچا كر اس كا كام ختم ہو جاتا ہے ۔
ثانياً: يہ جو كہا گيا ہے كہ قرآن كا مخاطب ”ناس“ ہيں اور ”ناس“ اور ”محروم طبقہ“ دونوں برابر ہيں اور اس رو سے مخاطب اسلام محروم طبقہ ہے اور اسلامي آئيڈيالوجى، محروم طبقہ كي آئيڈيالوجي ہے اور اسلام اپنے پيروكار اور جانثار صرف محروم طبقے سے چنتا ہے، بالكل غلط ہے۔ اس ميں كوئي شك نہيں كہ مخاطب اسلام ”ناس“ ہيں، ليكن ”ناس“ كا مطلب انسان ہيں۔ يہ ايك عمومي گفتگو ہے، جو تمام انسانوں كے لئے ہے، كسي لغت اور كسي مروجہ عربي زبان ميں ”ناس“ محروم طبقے كو نہيں كہا گيا بلكہ طبقے كا مفہوم اس ميں آتا ہي نہيں، قرآن كہتا ہے:
( لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. )
”يعني صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے كہ وہ حج بجا لائيں ۔“
كيا يہاں يہ مفہوم نكلتا ہے كہ اس سے مراد محروم طبقہ ہے؟ اسي طرح قرآن ميں اكثريت كے ساتھ ”يا ايھا الناس“ كے الفاظ آئے ہيں اور كہيں بھي اس سے مراد محروم طبقہ نہيں بلكہ عوام الناس ہيں، قرآن كے تمام عمومي خطابات اس نظريہ فطرت سے ہم آہنگ ہيں، جسے قرآن نے خود پيش كيا ہے ۔
ثالثاً: قرآن كے بارے ميں يہ بات بھي درست نہيں كہ وہ اس بات كا مدعي ہے كہ تمام انبياء عليھم السلام تمام قائدين اور تمام شہداء صرف مستضعف طبقے سے ابھرتے ہيں۔ قرآن نے ہرگز ايسي كوئي بات نہيں كي ہے ۔
”( هو الذي بعث في الاميين ) ۔۔۔“
كي آيت كو استدلال بنا كر جو كہا گيا ہے كہ پيغمبر ”امت“ سے ابھرتا ہے اور ”امت“ عام لوگوں كے مساعي ہے، بڑي مضحكہ خيز بات ہے، ”اميين“، ”اُمّي“ كي جمع ہے اور يہ لفظ ناخواندہ كے مفہوم ميں آتا ہے۔ ”اُمّي“ امت سے نہيں ”ام“ سے منسوب ہے اور پھر ”امت“ اس معاشرے كا نام ہے، جس ميں بہت سے گروہ مختلف طبقات كے امكان كے ساتھ باہم جي رہے ہوں۔ امت ہرگز عام لوگوں كے طبقے سے عبارت نہيں ہے۔ اس سے زيادہ مضحكہ خيز استدلال وہ ہے، جو سورہ قصص كي پچھترويں آيت سے شہيدوں كے بارے ميں كہا گيا ہے۔ آيت يہ ہے:
( ونزعنا من كل امة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم ) .
اس آيت كي تفسير (جو دراصل مسخ ہے) اس طرح كي گئي ہے:
”ہم ہر امت (ہر طبقے) سے ايك شہيد كو (اللہ كي راہ ميں قتل ہونے والے كو) اٹھاتے ہيں، يعني ان سے ايك انقلابي شخص كو ابھارتے ہيں اور پھر تمام امتوں سے كہتے ہيں كہ وہ اپنے اپنے برہانوں كو جو شہيد اور اللہ كي راہ ميں قتل ہونے والي انقلابي شخصيتيں ہي ہيں، كو اپنے ساتھ لائيں ۔“
اولاً: يہ آيت ايك دوسري آيت كا حصہ ہے اور ان دونوں كا تعلق قيامت سے ہے:
( ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ) .
”قيامت كا دن وہ ہوگا، جس ميں خدا مشركوں كو آواز سے گا كہ كہاں ہيں وہ شركاء جن كا تم مجھ پر گمان كيا كرتے تھے ۔“
ثانياً: ”نزعنا“ كا مطلب جدا كرنا ہے، ابھارنا اور اكسانا نہيں ہے ۔
ثالثاً: شہيد كے معني اس آيت ميں خدا كي راہ ميں قتل ہونے والا نہيں بلكہ اعمال پر ناظر اور گواہ ہے اور قرآن مجيد ہر پيغمبر كو امت كے اعمال پر گواہ گردانتا ہے۔ قرآن ميں كہيں بھي لفظ ”شہيد“ اللہ كي راہ ميں قتل ہونے والوں كے لئے نہيں آيا، لہٰذا جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم اور آئمہ طاہرين عليہم السلام نے اسے آج ہي كے رائج مفہوم ميں استعمال كيا ہے، ليكن قرآن ميں يہ لفظ اس مفہوم ميں نہيں آيا، پس يہ بات ہماري نظر سے گذر رہي ہے كہ كس طرح نامربوط ماركسي نظريہ كي توجيہ كے لئے قرآن كي آيتوں كو مسخ كيا جارہا ہے ۔
رابعاً: انبياء عليھم السلام كے ہدف كے بارے ميں وہ كيا ہے؟ كيا ان كا پہلا اور اصلي ہدف عدل و قسط قائم كرنا ہے يا بندے اور خدا كے درميان ايمان اور معرفت كے تعلق كي برقراري ہے يا پھر دونوں ہي باتيں ہيں، يعني انبياء عليھم السلام بااعتبار ہدف ”ثنوي“ ہيں يا كوئي اور بات بروئے كار ہے۔ ہم نے ”نبوت“ كي بحث ميں اس پر گفتگو كي تھى، جسے اب دہرانا نہيں چاہتے۔ (”وحي و نبوت“ اسي سلسلے كي تيسري كتاب) اس منزل پر ہم موضوع كو پيغمبروں كے كام كي ”روش“ اور Method كے اعتبار سے پركھنا چاہتے ہيں۔ جيسا كہ ہم عملي توحيد كے مباحث ميں بھي عرض كر چكے ہيں (”توحيدي تصور كائنات“ اسي سلسلے كي دوسري كتاب) انبياء عليھم السلام تو بعض متصوفين كے انداز فكر كے مطابق انسان كي اصلاح كے لئے اپني تمام كوششوں كو اس پر صرف كرتے تھے كہ اسے باطني طور پر آزاد بنائيں تاكہ وہ اشياء سے اپنا رشتہ توڑ لے اور نہ ہي بعض مادي مكاتب كي طرح باطني روابط كي اصلاح و تعديل كے لئے ظاہري يا بيروني اصلاح و تعديل كو كافي سمجھتے تھے۔ قرآن نے ايك جملے ميں اس مسئلے كو حل كر ديا ہے:
( تعالوا الي كلمة سوآء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شياء ولا يتخذ بعضنا بعضاً اربابا من دون الله ) (سورہ آل عمران، ۶۴)
”اے اہل كتاب ايك ايسي بات كي طرف آجاؤ، جو ہمارے اور تمہارے درميان يكساں ہے كہ ہم سوائے خدا كے كسي كي پرستش نہ كريں اور اس كا كسي كو شريك نہ بنائيں اور حقيقي خدا كو چھوڑ كر ہم ميں كوئي كسي كو پروردگار نہ بنائے ۔“
ليكن گفتگو اس باب ميں ہے كہ كيا انبياء عليہم السلام اپنے كام كا آغاز اندر سے كرتے ہيں يا باہر سے؟ كيا پہلے وہ عقيدے، ايمان اور معنوي جذبے كے ذريعے سے اندروني يا باطني انقلاب برپا كرتے ہيں اور ان لوگوں كو جو توحيدى، فكرى، احساسي اور عاطفي انقلاب سے بہرہ مند ہوجاتے ہيں، انہيں اجتماعي توحيد، اجتماعي اصلاح اور عدل و انصاف كي برقراري كے لئے ابھارتے ہيں؟ يا پہلے مادي پلڑے ميں اپنا وزن ڈال كر يعني محروميوں، دھوكہ بازيوں اور زيادتيوں پر لوگوں كي توجہ مركوز كر كے انہيں حركت ميں لاتے ہيں اور اجتماعي شرك اور بے جا امتيازات كا قلع قمع كرنے كے بعد وہ ايمان، عقيدے اور اخلاق كي جستجو ميں نكلتے ہيں؟
انبياء عليھم السلام اور اولياء الٰہي كي روش كا تھوڑا سا مطالعہ اور اس پر تھوڑي سي توجہ بھي ہميں يہ بتاتي ہے كہ وہ اپنا كام مصلحتوں اور انساني اصلاح كے مدعيوں كے برعكس فكر، عقيدے، ايمان، معنوي اضطرار، عشق الٰہى، مبداء اور معاد كے تذكرے سے شروع كرتے ہيں۔ سوروں كي ترتيب، قرآن مجيد كي نازل شدہ آيتوں كا مطالعہ كہ وہ كن مسائل سے شروع ہوئي ہيں اور اسي طرح جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كي سيرت كہ انہوں نے اپني تيرہ سالہ مكي زندگي اور دس سالہ مدني زندگي ميں كن مسائل پر توجہ دى، اس موضوع پر كافي روشني ڈالتي ہيں۔
خامساً: يہ ايك فطرى بات ہے كہ پيغمبر كے مخالفين رجعت پسندانہ منطق كے حامل تھے۔ ليكن اگر اس بات كو قرآن سے استنباط كيا جاتا اور وہاں ديكھا جاتا كہ انبياء عليھم السلام كے تمام مخالفين بلا استثناء اس منطق كے حامل تھے، تو يہ بات بھي سامنے آتي ہے كہ ان تمام مخالفين كا تعلق با حيثيت، خوشحال اور استحصال پسند طبقے سے تھا۔ قرآن سے جو بات سامنے آتي ہے، وہ يہ ہے كہ يہ منطق ان وڈيروں اور مخالفوں كي رہي ہے، جنہيں ملاء و مستكبر كہا جاتا ہے اور وہ لوگ جن كے ہاتھوں ميں بقول ماركس معاشرے كي مادي اجناس كي كنجي تھى، ان كي فكرى اجناس كو دوسروں تك پہنچاتے تھے اور يہ بات بھي فطرى ہے كہ پيغمبروں كي منطق، فكرى، تعقلي اور تقاليد و روايات سے پاك رہي ہے اور ايسا ہونا بھي چاہيے، ليكن اس كي وجہ ہرگز يہ نہيں ہے كہ طبقاتي محروميوں، مظلوميتوں اور استضعاف شدگيوں نے ان كے ضمير اور وجدان كو ايسا بنا ديا ہو اور يہ منطق ان كي محروميوں كا لازمي اور فطرى انعكاس ہو، بلكہ يہ اس لئے تھے كہ انہوں نے منطق، تعقل، عواطف اور انساني احساسات كي آغوش ميں پرورش پائي اور انسانيت نے انہيں رشد و كمال تك پہنچاديا۔ يہ بات ہم بعدميں بتائيں گے كہ انسان جس قدر انسانيت ميں رشد و كمال كي منزليں طے كرے گا اتنا ہي طبيعي اور اجتماعي ماحول سے اس كي وابستگي كم ہو جائے گي اور وہ وارستگي اور استقلال كي منزل كر لے گا۔ پيغمبروں كي مستقل منطق اسي بات كي متقاضي رہي ہے كہ وہ عادات و روايات و تقاليد كے پاپند نہ ہوں اور لوگوں كو بھي ان روايات اور اندھي تقاليد سے باز ركھيں ۔
سادساً: استضعاف كے بارے ميں بھي جو كچھ كہا گيا، وہ بھي قابل قبول نہيں، ليكن كيوں؟
اس لئے كہ اولاً قرآن نے اپني دوسري آيتوں ميں بڑي صراحت كے ساتھ تاريخ كي سرنوشت اور اس كے انجام كو كسي اور صورت ميں بيان كيا ہے، جب كہ ضمناً تاريخ كے تكامل كي جگہ كو بھي بيان كيا ہے اور وہ آيتيں اس آيت كے معني كي بالفرض كہ اس كا معني وہ ہو، جو بيان كيا جاتا ہے، شارح اور مفسر ہيں اور اسے مشروط بناتي ہيں۔
ثانياً: رائج و عام باتوں كے خلاف بنيادي طور پر استضعاف كي آيت نے كسي كلي اصول كو پيش نہيں كيا تاكہ اس ضمن ميں آنے والي آيتوں كے ساتھ موازنے كي منزل ميں كسي تفسير و توضيح كي يا آيت كو مشروط بنانے كي ضرورت ہو، يہ آيت اپني پہلي اور بعد كي آيت سے متصل ہے اور ان مربوط آيتوں پر توجہ سے يہ بات واضح ہوتي ہے كہ يہ آيت جس طرح كہ اس سے استدلال كياگيا ہے، كلي اصول كو بيان نہيں كر رہي۔ پس اس آيت كے بارے ميں ہماري بحث دو حصوں ميں منقسم ہوتي ہے۔ پہلے حصے ميں فرض كيا گيا ہے كہ ہم نے اس آيت كو اس كي پہلي اور بعد كي دس آيتوں سے جدا كر ديا ہے اور اسي سے ايك كلي تاريخي اصول اخذ كر ليا ہے، اس كے بعد اس كا دوسري آيتوں كے ساتھ موازنہ كرتے ہيں، جو اس آيت سے ماخوذ اصول كے برخلاف تاريخ كے ديگر اصولوں كي حامل ہيں، پھر ہم يہ ديكھتے ہيں كہ مجموعي طور پر ہميں اس سے كيا حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے حصے ميں گفتگو كا موضوع يہ ہوگا كہ يہ آيت بنيادي طور پر جس طرح كہ اس سے استدلال كيا گيا ہے، كلي تاريخ اصول بيان ہي نہيں كر رہي اور اور اب پہلے حصہ پر گفتگو ہوتي ہے۔ قرآن مجيد كي بعض آيتوں ميں تاريخ كي سرنوشت، اس كے سرانجام اور نيز تكامل تاريخ كے راستے اور مقام كے بارے ميں ضمناً گفتگو ہے اور يہ اسي وقت ميسر ہوگا، جب بے ايماني پر ايمان، فجور پر تقويٰ، بدعنواني پر اصلاح اور ناشائستہ عمل پر شائستہ عمل كي كاميابي ہوگي۔ سورہ نور كي ۵۵ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:
( وعدا لله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم امنا يعبد و نني لا يشركون بي شيئا )
اس آيت ميں جن لوگوں سے خلافت اور وراثت ارض كا وعدہ كيا گيا ہے اور انہيں حتمي كاميابي كي خوشخبري دي گئي ہے، شائستہ كار مومن ہيں۔ اس آيت ميں استضعاف كي آيت كے برخلاف جس ميں استضعاف شدگي اور محروميت و مظلوميت كا ذكر ہے، آئيڈيالوجيكل اور اخلاق و كردار جيسي صفات كا ذكر كيا گيا ہے اور درحقيقت ايك طرح كے عقيدے، ايك طرح كے ايمان اور ايك طرح كے كردار كي كاميابي اور آخري غلبے كا وعدہ كيا گيا ہے۔ بعبارت ديگر اس آيت ميں ايماندار، حقيقت پسندانہ اور راست كردار انسان كي كاميابي كا اعلان ہوا ہے۔ اس كاميابي ميں جس چيز كي نويد دي گئي ہے ۔
وہ ايك استخلاف يعني حصول حكومت اور پچھلي طاقتوں كا خاتمہ ہے اور دوسرے استقرار دين يعني عدل، عفاف، تقويٰ، شجاعت، ايثار، محبت، عبادت، اخلاص اور تزكيہ نفس وغيرہ پر مشتمل اسلام كي اجتماعي اور اخلاقي اقدار كي وجود پذيري ہے اور تيسرے عبادت يا اطاعت سے ہر طرح كے شرك كي نفي ہے۔ سورہ اعراف كي ايك سو اٹھائيسويں (۱۲۸) آيت ميں بھي يہي تذكرہ ہے:
( قال موسيٰ لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين )
”جناب موسيٰ نے اپني قوم سے كہا: وہ خدا سے استعانت طلب كرے اور صابر رہے، بيشك زمين، ملك الٰہي ہے اور وہ اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتاہے، اس كا وارث بناتا ہے (ليكن) عاقبت و انجام متقين كے لئے ہے، يعني سنت الٰہي يہ ہے كہ متقين ہي زمين كے وارث بنيں ۔“
سورہ انبياء عليھم السلام كي ايك سو پانچويں (۱۰۵) آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:
( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصلحون )
”ہم نے زبور ميں بعد اس كے كہ (كسي اور كتاب ميں) ايك دفعہ پہلے بھي ياد دہاني كرائي تھى، يہ لكھ ديا ہے كہ كہ زمين كي وراثت ميرے شائستہ كار بندوں كو ملے گي ۔“
اس ضمن ميں اور بھي آيتيں ہيں اب ہم كيا كريں؟ استضعاف كي آيت كو ليں يا استخلاف اور ان چند دوسري آيتوں كو؟ كيا ہم يہ بات كہہ سكتے ہيں كہ يہ دو طرح كي آيتيں اگرچہ ظاہراً دو مفہوم كي حامل ہيں، ليكن ايك حقيقت كو پيش كرتي ہيں اور وہ يہ كہ مستضعفين درحقيقت مومنين، صالحين اور متقين ہي ہيں، جن كا ذكر دوسري آيتوں ميں آيا ہے، كيا استضعاف ان كي طبقاتي اور اجتماعي عنوان ہے اور ايمان، عمل صالح اور تقويٰ مكتبي عنوان؟ ہرگز نہيں ۔
كيونكہ اولاً: ہم نے پہلے يہ بات ثابت كر دي ہے كہ عناوين كي مطابقت كا نظريہ اس معني ميں كہ بنياد استضعاف شدگى، استحصال زدہ ہونا محرومي ہے جبكہ ايمان، صالح اور تقويٰ ان بنيادوں پر كھڑي عمارت ہے، با اعتبار قرآن صحيح نہيں ہے۔ قرآن كي رو سے ممكن ہے، بعض گروہ مومن ہوں، مگر مستضعف نہ ہوں اور اسي طرح مستضعف ہوں، مگر مومن نہ ہوں اور قرآن نے دونوں گروہوں كي شناخت كروائي ہے، البتہ جيسا كہ ہم پہلے عرض كر چكے ہيں، ايك طبقاتي معاشرے ميں جب عدل، ايثار اور احسان وغيرہ سے متعلق الٰہي قدروں پر مبني توحيدي آئيڈيالوجي كا اعلان ہوتا ہے، تو روشن ہے كہ ا س پر ايمان لانے والوں كي اكثريت مستضعفين ميں سے ہوتي ہے كيونكہ ان كي راہ ان ركاوٹوں سے پاك ہوتي ہے، جو مخالف طبقے ميں پائي جاتي ہيں، ليكن كبھي بھي مومن طبقہ فقط مستضعف طبقے ميں سے نہيں ہوا ۔
ثانياً: ان دونوں آيتوں ميں سے ہر ايك آيت تاريخ سے متعلق دو مختلف ميكانزم پيش كرتي ہے۔ استضعاف كي آيت تاريخ كي راہ كو طبقاتي كشمكش سے عبارت جانتي ہے اور حركت سے متعلق ميكانزم كو استحصال كرنے والوں كي طرف سے پڑنے والا دباؤ اس طبقے كي بالذات رجعت پسندي اور استحصال كے سبب استحصال كے شكار افراد كا انقلابي جذبہ قرار ديتي ہے ۔
جس ميں كاميابي بالآخر استضعاف شدہ طبقے ہي كو حاصل ہوتي ہے، خواہ وہ ايمان اور عمل صالح سے بہرہ مندہ ہو يا نہ ہو اور اس ميں في المثل ويت نام اور كمبوڈيا وغيرہ كے استحصال شدہ عوام بھي آجاتے ہيں اور اگر ہم الٰہي رخ سے اس آيت كے معني كي توضيح كرنا چاہيں گے تو ہميں كہنا پڑے گا كہ يہ آيت چاہتي ہے كہ مظلوم كے لئے حق تعاليٰ كي حمايت جو كہ قرآن كي آيت:
”( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) “. (سورہ ابراہيم، آيت۴۲)
ميں آئي ہے، يعني عدل الٰہي كو بيان كرے۔ استضعاف كي آيت سے رونما ہونے والي وراثت و امامت ”عدل الٰہي“ كا مظہر ہے۔
ليكن استخلاف اور اس سے مشابہ آيتيں تاريخ سے كسي اور طرح كا ميكانزم پيش كرتي ہيں اور ايك ايسے اصول كا تذكرہ كرتي ہيں، جو عدل الٰہي سے زيادہ جامع اور مكمل ہے اور اس ميں عدل الٰہي بھي آجاتا ہے۔
وہ ميكانزم جو يہ آيت اور اس سے مشابہ آيتيں پيش كرتي ہيں، يہ ہے كہ دنيا ميں ہونے والي تمام جنگوں ميں مادي اور مفاداتي ماہيت ركھنے والي جدوجہد كے علاوہ اگر كوئي للہى، في اللہى، مقدس اور مادي مفادات سے پاك جدوجہد ہے، تو يہ وہ تحريك ہے، جس كي قيادت انبياء عليھم السلام اور پھر ان كي پيروي ميں اہل ايمان نے كي اور اس قسم كي جنگوں نے انساني تمدن اور بشريت كو آگے بڑھانے ميں مدد دي ہے۔ صرف يہي وہ تحريكيں ہيں، جن كو حق و باطل كا معركہ كہا جا سكتا ہے اور انہي معركوں نے تاريخ كو باعتبار انسانيت اور باعتبار معنويت آگے بڑھايا ہے، ان معركوں كا اصلي محرك كسي طبقے كا دباؤ نہيں ہے بلكہ حقيقت كي طرف فطرى ميلان، نظام وجود كي حقيقي شناخت اور عدالت خواہي يعني معاشرے كي حقيقي تعمير اس كے اصلي عامل ہيں۔
مظلوميتوں اور محروميوں كے احساس نے انسان كو آگے نہيں بڑھايا بلكہ حصول كمال كے فطرى احساس نے اسے يہ راستہ دكھايا ہے ۔
انسان كي حيواني صلاحيتيں انجام تاريخ ميں وہي ہيں، جو آغاز ميں تھيں اور تاريخ كے پورے سلسلے ميں كوئي نيا رشد و نمو اسے حاصل نہيں ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا، ليكن انسان كي انساني صلاحيتيں بتدريج آگے بڑھ رہي ہيں اور آگے چل كر وہ اور بھي اپنے آپ كو مادي اور اقتصادي قيود سے چھڑا كر عقيدے اور ايمان سے منسلك ہوگا۔ وہ سطح جس پر تاريخ نے ترقي كي اور كمال تك پہنچي مادى، مفاداتي اور طبقاتي جدوجہد نہيں ہے، بلكہ وہ نظرياتى، الٰہي اور ايماني جدوجہد ہے اور يہي وہ طبقاتي ميكانزم ہے جس ميں انسان نے ترقي كي اور نيك، پاكيزہ لوگوں اور راہ حق كے مجاہدوں نے كاميابي حاصل كي ۔
اب رہي بات اس كاميابي كے الٰہي پہلو كي تو الٰہي پہلو سے جو چيز سلسلہ تاريخ ميں ظہور پذير ہو كر تكامل كي منزلوں سے گزرتي ہے اور بالآخر تاريخ اپني انتہاء كو پہنچتي ہے، وہ ربوبيت اور رحمت الٰہي كا ظہور اور اس كي تجلي ہے، جو تكامل موجودات كا تقاضا كرتي ہے۔ صرف عدل الٰہي نہيں جو ”صلہ“ كي متقاضي ہے۔بعبارت ديگر جس بات كي خوشخبري دي گئي ہے، وہ خدا كي ربوبيت، رحيميت اور اس كي اكرميت كا ظہور ہے، صرف جباريت و منتقميت نہيں ۔
پس ہم ديكھتے ہيں كہ استضعاف كى، استخلاف كي اور اس سے مشابہ آيتوں ميں ہر آيت ايك خالص طريقہ كار كو پيش كرتي ہے۔ كامياب طبقے كے اعتبار سے، اس راہ كے اعتبار سے جسے تاريخ طے كر كے كاميابي تك پہنچتي ہے، ميكانزم يعني تاريخ كو حركت ميں لانے والے عوامل كے اعتبار سے ايك خاص طريقہ كار سامنے آتا ہے۔ ضمناً يہ بات بھي واضح ہوگئي كہ استخلاف كي آيت كے مقابل استضعاف كي آيت سے حاصل ہونے والي چيز جزوي بلكہ ايك معمولي جزو ہے، استضعاف كي آيت سے حاصل ہونے والے مطلب كا، يعني استضعاف كي آيت دفع ظلم يا مظلوم سے اللہ كي حمايت كے جس مفہوم كو پيش كرتي ہے، وہ استخلاف كي آيت كے مفاہيم كا ايك حصہ ہے ۔
اب ہم آيہ استضعاف كے بارے ميں بحث كے دوسرے حصے كي طرف آتے ہيں: حقيقت تو يہ ہے كہ استضعاف كي آيت نے ہرگز كسي كلي اصول كو پيش نہيں كيا، يہي وجہ ہے كہ اس نے نہ تو تاريخ كي راہ ميں كي وضاحت كي ہے اور نہ تاريخي ميكانزم كے بارے ميں كوئي اشارہ كيا ہے اور نہ ہي تاريخ كي كاميابي كو مستضعفوں كے حصے ميں اس اعتبار سے كہ وہ مستضعف ہيں، ديا ہے۔ يہ غلطي ہے كہ يہ آيت ايك كلي اصول كو پيش كرتي ہے، اس لئے ہوئي كہ اس آيت كو اپني پہلي اور بعد كي مرتبط آيت سے جدا كر كے ”الذين“ كو ”الذين استضعفوا“ كے مفہوم ميں مفيد عموم اور سب كے شامل حال بنا ديا گيا ہے اور پھر اس سے ايك ايسے اصول كا استنباط كيا گيا ہے، جو آيہ استخلاف كے حقيقي مفہوم كي ضد ہے، اب ہم ان تينوں آيتوں كو پيش كرتے ہيں:
( ان فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم و يستحيي نسائهم انه كان من المفسدين و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم آئمة و نجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض و نري فرعون وهامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) . (سورہ قصص، آيات۴ تا ۶)
يہ تينوں آيتيں ايك دوسرے سے مرتبط ہيں اور مجموعاً ايك ہي مفہوم كو پيش كرتي ہيں، ان تينوں مرتبط آيتوں كا مفہوم يہ ہے:
”فرعون نے زمين پر برتري حاصل كي اور زمين كے باسيوں كو گروہوں ميں بانٹ ديا۔ ان گروہوں ميں سے ايك گروہ كو وہ كمزور ركھتا تھا، ان كے بيٹوں كو ذبح كيا كرتا تھا اور (صرف) ان كي بيٹيوں كو باقي ركھتا تھا۔ وہ مفسدوں ميں سے تھا حالانكہ ہمارے ارادے ميں يہ بات تھي كہ ہم فرعون كي طرف سے كمزور بنائے جانے والے انہي لوگوں پر احسان كريں۔ ان كو پيشوا بنائيں، انہيں وارث قرار ديں اور اس سرزمين ميں ان كو تسلط عطا كريں اور فرعون، (اس كے وزير) ہامان اور ان دونوں كے لشكر كو وہ كچھ دكھا ديں، جس كا وہ خوف كيا كرتے تھے ۔“
ہم ديكھتے ہيں كہ ”( ونمكن لهم في الارض ) “ كا جملہ اور تيسري آيت كے ”( ونري فرعون و هامان ) ۔۔۔“ كا جملہ دونوں دوسري آيت كے ”ان نمن“ كے جملے پر عطف ہيں اور اس كے مفہوم كو مكمل كرتے ہيں، يہي وجہ ہے كہ ان دونوں آيتوں كو ايك دوسرے سے جدا نہيں كيا جا سكتا۔ دوسري طرف ہم ديكھتے ہيں كہ تيسري آيت كا دوسرا جملہ ”ونري فرعون و ہامان“ پہلي آيت كے مفہوم سے متصل ہے اور فرعون جس كي جباريت پہلي آيت ميں بيان ہو چكي ہے، كا انجام پيش كرتي ہے۔ پس تيسري آيت كو پہلي آيت سے جدا نہيں كيا جا سكتا اور چونكہ تيسري آيت پر عطف ہے اور اسے مكمل كرنے والي ہے، لہٰذا دوسري آيت بھي پہلي آيت سے جدا نہيں ہو سكتي ۔
اگر تيسري آيت نہ ہوتي يا اس ميں فرعون يا ہامان كے انجام كا تذكرہ نہ ہوتا، تو ممكن تھا كہ دوسري آيت كو پہلي آيت سے جدا كر ديا جاتا اور اس سے ايك كلي اصول كے طور پر استفادہ كيا جاتا، ليكن ان تينوں آيتوں كا ناقابل تفكيك جوڑ اسے كلي اصول بنانے ميں ركاوٹ ہے۔ جو بات سامنے آتي ہے، وہ يہ ہے كہ فرعون بڑائى، تفرقہ بازى، استحصال اور فرزند كشي كرتا تھا، حالانكہ اسي وقت ہمارا يہ ارادہ تھا كہ ہم انہي محقر، مظلوم اور محروم لوگوں پر احسان كريں اور انہيں پيشوا اور وارث قرار ديں۔ پس آيت ميں لفظ ”الذين“ كا موعود يعني مذكورہ لوگوں كي طرف اشارہ ہے، عمومي اور سب لوگوں پر محيط نہيں۔ علاوہ ازيں اس آيت ميں ايك نكتہ اور بھي ہے اور وہ يہ ہے كہ ”( ونجعلهم آئمه ) ۔۔۔“ كا جملہ ”ان نمن“ كے جملے پر عطف ہے، جس كا مطلب يہ ہے كہ ہم ان پر احسان كريں اور انہيں فلاں، فلاں بنا ديں يہ نہيں كہا: ”( بان نجعلهم ) ۔۔۔“ يعني جو احسان ہم نے ان پر كيا ہے، وہ امامت و وراثت ہي كا دينا تھا، جيسا كہ عام طور پر اسي طرح وضاحت كي جاتي ہے۔ آيت كا مطلب يہ ہے كہ ہمارا ارادہ يہ تھا كہ ہم ان مستضعفين پر ديني تعليم و تربيت، آسماني كتاب، ارسال رسول اور توحيدي اعتقادات كے ذريعے احسان كريں، انہيں اہل ايمان اور اہل صلاح و فلاح بنائيں اور آخر كار انہيں زمين (انسان كي اپني زمين) كا وارث اور امام قرار ديں۔ پس يہ آيت كہنا چاہتي ہے:
”( ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا) بموسي والكتاب الذي ننزله علي موسي ( و نجعلهم آئمه ) ۔۔۔ “
لہٰذا استضعاف كي آيت كا مفہوم ہرچند كے خاص ہے، ليكن استخلاف كي آيت كے مفہوم كے عين مطابق ہے، يعني اس آيت كے مصاديق ميں سے ايك مصداق كو بيان كرتي ہے۔ قطع نظر اس كے كہ ”ان نمن“ كے جملے پر ”( ونجعلهم آئمه ) ۔۔۔“ كے جملے كا عطف اس طرح كا حكم ديتا ہے، بنيادي طور پر يہ نہيں كہا جا سكتا كہ آيت يہ كہنا چاہتي ہے كہ بني اسرائيل مستضعف ہونے كے سبب وراثت اور امامت تك پہنچتے تھے۔ خواہ جناب موسيٰ عليہ السلام پيغمبر كي حيثيت سے ظہور كرتے يا نہ كرتے، خواہ موسيٰ عليہ السلام كي آسماني تعليمات آتيں يا نہ آتيں، خواہ وہ ان كي تعليمات كو مانتے يا نہ مانتے۔ ممكن ہے اسلام كے نقطہ نگاہ سے نظريہ ماديت تاريخ كے حامي افراد كسي اور بات كو پيش كريں اور كہيں كہ اسلامي كلچر باعتبار روح و معاني يا كمزور اور مستضعف طبقے كي ثقافت ہے يا پھر اس كا تعلق استحصالي طبقے سے ہے يا ايك جامع كلچر ہے، اگر اسلامي كلچر مستضعف طبقے كا كلچر ہے، تو پھر اس ميں بہرحال اپنے طبقے كا رنگ ہونا چاہيے۔ اس كے مخاطب اس كي ذمہ دارى، اس كي سمت كا تعين، سبھي كچھ استضعاف كے محور پر ہونا چاہيے اور اگر اسلامي كلچر كو ظالم يا استحصالي طبقے سے نسبت دي جائے، جيسا كہ مخالفين اسلام كا دعويٰ ہے، تو علاوہ بريں كہ اس ميں طبقاتي رنگ ہوگا ايك طبقہ كے محور پر اس كي گردش ہوگي۔ اس كا كلچر رجعت پسندانہ اور خلاف انسانيت ہوگا اور نتيجتاً الٰہيت سے اس كا واسطہ نہ ہوگا ۔
كوئي مسلمان اس نظريے كو ماننے كے لئے تيار نہ ہوگا۔ اس كے علاوہ اس كے كلچر كا سراپا خود اس كے خلاف گواہي دے گا۔ اب صرف يہ بات رہ جاتي ہے كہ كہا جائے كہ اسلامي ثقافت ايك جامع ثقافت ہے، جامع ثقافت يعني غير جانبدار ثقافت، بے پرواہ ثقافت، غير ذمہ دار ثقافت، بے مقصد، لا يعني ثقافت اور اعتزالي ثقافت، جو چاہتي ہے كہ اللہ كے كام كو اللہ اور قيصر كے كام كو قيصر كے حوالے كرے۔ ايك ايسي ثقافت جو آگ اور پانى، ظالم اور مظلوم اور استحصال گر اور استحصال كے شكارلوگوں كے درميان دوستي چاہتي ہے اور سب كو ايك مركز پر جمع كرنا چاہتي ہے۔ وہ ثقافت جس كا نعرہ يہ ہے كہ ”نہ سيخ جلے اور نہ كباب“ اس قسم كي ثقافت ايك قدامت پرستانہ ثقافت ہے، جو ظالم استضعاف گر اور استحصال پسند افراد كے حق ميں مفيد ثابت ہوتي ہے۔ جس طرح اگر ايك گروہ غير جانبدارنہ، بے توجہانہ، غير ذمہ دار اور ذلت پسندانہ روش اختيار كرے اور غارت گر اور غارت كے شكار افراد كے درميان اجتماعي يا معاشرتي جھگڑوں ميں حصہ نہ لے، تو گويا اس نے غارت گر كا ساتھ ديا ہے اور اس كے ہاتھ مضبوط كئے ہيں، اسي طرح اگر ايك ثقافت بے توجہ اور غير جانبدار بن جائے تو ہميں چاہيے كہ ہم اسے ظالم يا استحصالي طبقے كي ثقافت سمجھيں، پس چونكہ اسلامي ثقافت ايك بے پروہ، غير جانبدار يا استحصالي طبقے كي حامي نہيں ہے، لہٰذا ہميں چاہيے كہ ہم اسے مستضعف يا مظلوم طبقے كي ثقافت جانيں اور اس كے پيام، اس كے مخاطب اور اس كي معين راہ كو اسي طبقے كے محور اور دائرہ عمل ميں شمار كريں۔
يہ گفتگو انتہائي غلط گفتگو ہے۔ غالباً ماديت تاريخ سے بعض مسلمان روشن فكروں كے لگاؤ كا اصلي سبب دو باتيں ہيں، جن ميں سے ايك يہي سوچ ہے كہ اگر اسلامي ثقافت كو انقلابي ثقافت كہنا چاہتے ہيں يا اگر اسلام كو كسي انقلابي ثقافت سے جوڑنا چاہتے ہيں، تو ماديت تاريخ سے رشتہ جوڑے بغير يہ كام نہيں ہو سكتا۔ باقي يہ تمام باتيں كہ ہماري قرآني معرفت ہميں يہ سوچ ديتي ہے يا قرآن كے ہمارے مطالعات ہميں يہ بتاتے ہيں يا استضعاف كي آيت يہ كہتي ہے، سب ايك بہانہ اور پہلے سے سوچتي ہوئي بات كي توجيہ ہے اور اس بناء پر يہ لوگ اسلامي فكر و سوچ سے بہت دور نكل جاتے ہيں اور اسلام كي الٰہى، فطرى، انساني اور پاكيزہ منطق كو ختم كر كے مادي منطق تك لے آتے ہيں ۔
اس قسم كے روشن فكر حضرات سوچتے ہيں كہ كسي ثقافت كے انقلابي ہونے كي تنہا راہ يہ ہے كہ اس كا تعلق صرف محروم اور استحصال زدہ سے ہو، وہ اسي طبقے سے اٹھي ہو، اس كا رخ اسي طبقے كي طرف ہو، اسي طبقے كے مفادات كي طرف اس كي نگاہ ہو، اس كا مخاطب صرف يہي طبقہ، اس كے قائدين، اس كے رہنما اور اس كے تمام اجتماعي اور طبقاتي مراكز سب سے سب اسي طبقے سے ہوں اور باقي تمام گروہوں اور مراكز سے اس كا رابطہ صرف جھگڑے، دشمني اور جنگ كا ہو، اس كے علاوہ نہيں، ان روشن فكر حضرات كا خيال ہے كہ انقلابي ثقافت كي راہ لازماً ”پيٹ“ كے مسئلے پر آكر ختم ہوتي ہے اور تاريخ كے تمام عظيم انقلابات يہاں تك كہ انبياء الٰہي كي قيادت ميں برپا ہونے والے انقلابات كا تعلق بھي پيٹ كے مسئلے ہي سے تھا، لہٰذا انہوں نے عظيم المرتبت ابوذر، حكيم امت ابوذر اور پھر خداپرست ابوذر، مخلص ابوذر، امر بالمعروف كرنے والے اور نہي عن المنكر كرنے والے ابوذر اور مجاہد في سبيل اللہ ابوذر كو ايك بندہ شكم ابوذر اور نفسياتي الجھنوں كا شكار ابوذر بنا ديا اور كہا كہ وہ بھوك كو اچھي طرح محسوس كرتا ہے اور اسي بھوك كي خاطر وہ تلوار اٹھانے اور لوگوں كے قتل كرنے كو جائز بلكہ واجب و لازم سمجھتا ہے۔ اس كي سب سے بڑي صفت يہ تھي كہ چونكہ وہ خود بھوك كا مزہ چكھ چكا تھا، اس لئے جانتا تھا كہ اس كے طبقے سے وابستہ بھوكوں پر كيا گزر رہي ہے، مخلوق كي بھوك كا بھي اسے اچھي طرح احساس تھا اور اس لئے اس بھوك كے سبب فراہم كرنےوالے گروہ كے خلاف اس كے دل ميں نفرت بيٹھ گئي اور وہ اس گروہ كے خلاف مسلسل اپني جدوجہد ميں لگا رہا اور بس! اس لقمان امت، موحد، عارف اور اسلام كے پاك باز مجاہد مومن كي شخصيت بس اسي منزل پر تمام ہوتي ہے۔ يہ روشن فكر حضرات سمجھتے ہيں كہ ماركس كے نظريے كے مطابق:
”انقلاب، صرف ايك قہر آلودقيام اور عوامي تحريك ہي سے وجود ميں آسكتا ہے ۔“
ان كي سوچ ميں يہ بات نہيں آتي كہ ايك ثقافت، ايك مكتب، ايك آئيڈيالوجي الٰہي غرض يا غايت كي حامل ہو اور اس كا مخاطب انسان بلكہ درحقيقت فطرت انساني ہو اور اس كا پيغام آفاقي اور ہمہ گير ہو اور مقصد عدالت، مساوات، برابرى، پاكيزگى، معنويت، احسان، محبت اور ظلم كے خلاف جنگ ہو، تو وہ بھي ايك عظيم تحريك اور ايك عميق انقلاب برپا كر سكتي ہے۔ ليكن ايك الٰہي انساني انقلاب كہ جس ميں الٰہي ولولہ، معنوي مسرت، خدائي جذبہ اور انساني اقدار موجزن ہوں، اس كي ہميں تاريخ ميں بہت سي مثاليں ملتي ہيں، ايران كا اسلامي انقلاب اس كا ايك روشن نمونہ ہے۔ روشن فكر حضرات يہ بات نہيں سوچ سكتے كہ كسي ثقافت كے ٹھوس اور با مقصد ہونے اور غير جانبدار اور بے تعلق نہ ہونے كے لئے يہ ضروري نہيں كہ وہ محروم اور پسے ہوئے طبقے سے تعلق ركھتي ہو۔ ان كا خيال ہے كہ جامع ثقافت لازمي طور پر غير جانبدار اور لاتعلق ہوتي ہے۔ يہ سوچنے ميں ان كي فكر ان كا ساتھ نہيں ديتي كہ ايك جامع مكتب اور ايك جامع ثقافت اگر الٰہي جذبہ كي حامل ہو اور اس كا مخاطب انسان يعني انسان كي انسانيت فطرت ہو، تو محال ہے كہ وہ غير جانبدار، لا تعلق، بے مقصد اور غير ذمہ دار ہو، جو چيز مقصديت اور مسئوليت پيدا كر ليتي ہے، وہ محروم طبقہ سے نہيں، وہ محروم طبقہ سے نہيں، اللہ اور انساني وجدان سے وابستگي ہے ۔
يہ ان حضرات كي غلط فہمي كي ايك بنيادي وجہ ہے۔ اسلام اور انقلاب كے درميان رابطے كے تصور كے بارے ميں يہ لوگ اس غلط فہمي ميں مبتلا رہے ہيں، اس غلط فہمي كي دوسري بنيادي وجہ اسلام اور اس كے اجتماعي راہ عمل كے غلط تصور سے متعلق ہے۔ ان روشن فكروں نے انبياء عليھم السلام كي تحريكوں كے بارے ميں قرآن كي تاريخي تفسير ميں بڑي وضاحت سے مشاہدہ كيا ہے كہ ان كي طرف سے مستضعفين كے مفاد ميں ايك مضبوط راہ عمل متعين كي گئي ہے، دوسري طرف ”محور“ اور راہ عمل كے درميان مطابقت كے قانون يعني ”اجتماعي بنياد اور اعتقادي عملي بنياد كے درميان تطابق“ جو ايك ماركسي قانون ہے، كو يہ روشن فكر حضرات ناقابل تفكيك سمجھتے تھے اور اس كے علاوہ كچھ اور سوچ بھي نہيں سكتے، لہٰذا انہوں نے مجموعاً يہ نتيجہ اخذ كيا كہ چونكہ واضح طور پر قرآن پيش رفت كرنے والي اور مقدس تحريكوں كے راہ عمل كو مستضعفوں كے حقوق، ان كي آزادي ميں مفاد ميں جانتا ہے، لہٰذا قرآن كي رو سے تمام مقدس اور پيش رفت كرنے والي تحريكوں كا محور محروم، مستضعف اور تباہ حال طبقہ ہے۔ پس باعتبار قرآن تاريخ كي ہويت مادي اور اقتصادي ہے اور اقتصاد ہي اصل ۔۔۔۔ ہے۔
اب تك جو كچھ ہمارے معروضات رہے، ان سے يہ ثابت ہوا كہ چونكہ قرآن اصول فطرت كا قائل ہے اور انساني زندگي پر حاكم ايك ايسي منطق ركھتا ہے، جسے فطرى منطق كہنا چاہيے اور اس كے مد مقابل حصول منفعت كي منطق ہے، جسے حيوان صفت پست انساني منطق كہنا چاہيے، لہٰذا اسلام ”محور اور رائے عمل كے درميان مطابقت“ يا ”اجماعي بنياد اور اعتقادي بنياد كے تطابق“ كے قانون كو نہيں مانتا، اسے ايك غير انساني اصول قرار ديتا ہے، يعني اس تطابق كے مصداق وہ لوگ نہيں، جو تربيت يافتہ اور انسانيت كے درجے پر فائز ہيں اور جن كي منطق، منطق فطرت ہے، بلكہ وہ لوگ ہيں، جنہوں نے ابھي انسانيت تك رسائي حاصل نہيں كي اور جو انساني تربيت سے بے بہرہ ہيں اور جن كي منطق اصول مفاد پر مبني ہے ۔
ان باتوں سے ہٹ كر يہ جو ہم كہتے ہيں كہ اسلام كا عملي راستہ مستضعفين كے مفاد ميں ہے، ايك طرح كے مجاز اور سہل انديشي سے خالي نہيں ہے۔ اسلام عدالت، مساوات اور برابرى كي سمت اپنا راستہ معين كرتا ہے ظاہر ہے يہ راہ محروموں اور مستضعفوں كے لئے مفيد اور استحصال كرنے والے غارت گروں كے لئے مضر ثابت ہوتي ہے ۔
اسلام وہاں بھي جہاں كسي طبقے كے حقوق و منافع كا تحفظ چاہتا ہے، اس كا اصلي ہدف ايك انساني اصول كا قيام اور اس كي عظمت كا اظہار ہوتا ہے۔ يہ وہ منزل ہے، جہاں ايك بار پھر اس ”اصول فطرت“ كے غير معمولي منزل كا اندازہ ہوتا ہے جسے قرآن واضح طور پر بيان كرتا ہے اور جسے اسلامي ثقافت اور اسلامي تعليمات ميں ”ام المعارف“ كے عنوان سے پہچانا جانا چاہيے ۔
فطرت كے بارے ميں بہت كچھ كہا جاتا ہے، ليكن اس كي گہرائي اور اس كي مختلف جہتوں كي وسعت كي طرف بہت كم توجہ دي گئي ہے۔ ايسے لوگوں كي كمي نہيں، جو فطرت كے بارے ميں بہت دم مارتے ہيں، ليكن اس كي وسيع جہات پر پوري توجہ نہ ہونے كے سبب آخر كار جو نظريات اخذ كرتے ہيں، وہ اس اصول كے مخالف ہوتے ہيں ۔
اسي طرح كا اشتباہ بلكہ اس سے بھي زيادہ وحشت ناك اشتباہ خود مذاہب كے محور و مقصد كے بارے ميں رونما ہوا ہے۔ اب تك ہم نے جو گفتگو كي وہ مذہب (البتہ مذہب اسلام) كے نقطہ نظر سے تاريخي واقعات كي ہويت اور اس كے مراكز طلوع كے بارے ميں تھي۔ اب ہم تاريخ كے ايك معاشرتي مظہر كے عنوان سے خود مذہب پر گفتگو كريں گے، جو آغاز تاريخ سے اب تك موجود رہي ہے۔ پہلے اس معاشرتي حقيقت كي متعين راہ اور اس كے محور و مركز كو واضح كرنا چاہيے۔
ہم مكرر عرض كر چكے ہيں كہ ماركسي تاريخي ماديت اس اصول كو پيش كرتي ہے كہ جس كے مطابق وہ ہر ثقافتي حقيقت كے محور و مقصد اور اس كے متعين راہ كے درميان قانون تطابق كي قائل ہوتي ہے۔
درحقيقت عارفہ اور حكماء الٰہي نظام ہستي كے حالات و واقعات ميں جس اصولوں كے قائل ہيں، وہ ”النھايات ھي الرجوع الي البدايات“ ہے، يعني انجام دراصل آغاز كي سمت بازگشت ہے ۔
مولانا روم نے كہا:
جزئہا را رويہا سوي كل است
بلبلان را عشق با روي گل است
”اجزاء كا رخ كل كي طرف ہے، بلبلوں كو روئے گل سے عشق ہوتا ہے ۔“
آنچہ از دريا بہ دريا مي رود
از ہمانجا كامد آنجا مي رود
”جو كچھ سمندر سے آتا ہے، سمندر كي طرف چلا جاتا ہے، جہاں سے آتا ہے، وہيں چلا جاتا ہے ۔“
از سركہ سيلہائي تيز رو
و زتن ما جان عشق آميز رو
”كوہسار كي چوٹيوں سے تيز رفتار ندياں نكلتي ہيں اور ہمارے جسم سے عشق سے معمور روح نماياں ہوتي ہے ۔“
ماركسزم بھي فطرى، ذوقى، فلسفى، مذہبي اور حتمي ثقافت، اجتماعي امور ميں ايسي ہي بات كرتا ہے۔ يہ مكتب اس بات كا مدعي ہے كہ ہر فكر كي سمت اس طرف ہوتي ہے، جہاں سے وہ اٹھتي ہے، يعني ”النھايات ھي الرجوع الي البدايات“ نہ غير جانبدار اور بے طرف سوچ، فكر، مذہب اور ثقافت ايك ايسا وجود ہے اور نہ ايسي جانبدار سوچ، فكر، مذہب اور ثقافت موجود ہے، جو ايك ايسے اجتماعي نظريے كو آگے بڑھانے كي خواہش مند ہو، جس سے اس كا كوئي رشتہ اور تعلق نہ ہو، اس مكتب كي روح سے ہر طبقہ اپنے سے متعلق ايك خاص فكر وذُق كا حامل ہے۔
اس اعتبار سے طبقاتي اور منقسم معاشروں ميں حيات اقتصادي كي روح سے دو طرح كے احساسات، دو فلسفى طرز تفكر، دو اخلاقي نظام، دو طريقے كے آرٹ، دو نوعيت كے شعر و ادب، ہستي كے بارے ميں دو طرح كا ذوق اور احساس و نظر اور كبھي دو طرح كا علم پايا جاتا ہے اور جب اصل بنياد اور روابط مالكيت كي دو صورتيں ہو جاتيں ہيں، تو باقي تمام چيزيں بھي دو شكلوں اور دو سسٹمز ميں بٹ جاتي ہيں ۔
ماركس ذاتي طور پر ان دو نظاموں كے عمل ميں مذہب اور حكومت كے استثناء كا قائل ہے۔ ماركس كي نگاہ ميں يہ دونوں چيزيں استحصالي طبقے كي خاص ايجاد اور اس طبقے كي منفعت جوئي كا ايك خاص ذريعہ ہيں اور طبيعي طور پر ان دونوں كي پاليسي كي سمت اور جدوجہد كا رخ اسي طبقے كے فائدے ميں ہے۔ استحصال كا شكار طبقہ اپنے اجتماعي حالات كي بنياد پر نہ مذہب كو جنم ديتا ہے اور نہ حكومت كو۔مذہب اور حكومت دونوں مخالف طبقے سے اس كے سر تھوپے جاتے ہيں۔ پس نہ مذہب ميں دو سسٹمز ہيں اور نہ حكومت ميں۔بعض مسلمان روشن فكروں كا كہنا ہے كہ ماركس كے نظريے كے برخلاف مذہب پر بھي دو سسٹمز كا عمل حكم فرما ہے ۔
ان كے خيال ميں:
”جس طرح طبقاتي معاشروں ميں اخلاقى، فنى، ادبياتي اور تمام ثقافتي امور دو سسٹمز پر مشتمل ہيں اور ہر سسٹم كا محور اور مقصد اس كا مخصوص طبقہ ہے، ايك سسٹم كا تعلق حاكم اور دوسرے كا محكوم طبقہ سے ہے، اسي طرح مذہب بھي دو سسٹمز كے نظام پر مشتمل ہے اور ہميشہ ہر معاشرے ميں دو مذہبوں كا وجود رہا ہے، ايك حاكم طبقے كا مذہب اور دوسرے محكوم طبقے كا ۔“
”مذہب حاكم مذہب شرك اور مذہب محكوم مذہب توحيد ہے، مذہب حاكم بے جا امتيازات كا مذہب اور مذہب محكوم مساوات اور برابرى كا مذہب ہے، مذہب حاكم موجود صورتحال كي حمايت اور مذہب محكوم انقلاب اور موجود صورتحال كي مذمت كا مذہب ہے۔ مذہب حاكم جمود، سكون، سكوت اور مذہب محكوم قيام، حركت اور آواز بلند كرنے كا مذہب ہے۔ مذہب حاكم معاشرے كے لئے افيون اور مذہب محكوم معاشرے كي قوت ہے ۔“
”پس ماركس كا يہ نظريہ كہ ہميشہ مذہب كا رخ حاكم طبقے كے مفاد ميں اور محكوم طبقے كے خلاف ہوتا ہے اور مذہب معاشرے كے لئے افيون ہے، اس مذہب پر صادق آتا ہے، جس كا محور حاكم طبقہ ہے اور اس وقت صرف وہي مذہب تھا كہ جس كا عملاً وجود تھا اور جس كي حكمراني تھي۔ محكوم طبقہ كے مذہب يعني انبياء اكرامعليہ السلام كا مذہب كہ جس نے حاكم نظاموں كو ہرگز اپنے اوپر چھانے كي اجازت نہيں دى، سے متعلق نہيں ہے، ان روشن فكروں نے اس طرح حاكم طبقے كے فائدے ميں مذہب كي كاروائي سے متعلق ماركس كے نظريے كو رد كر كے يہ سمجھ ليا كہ انہوں نے ماركسزم كي ترديد كي ہے۔انہوں نے نہيں سوچا كہ خود ان كي گفتگو اگرچہ ماركس، اينجلز، مائو اور ماركسزم كے تمام قائدين كے نظريہ كے خلاف ہے، ليكن مذہب كے بارے ميں عيناً ايك ماركسي اور مادي توجيہ ہے، جو انتہائي خطرناك ہے اور ہرگز اس پر ان كي توجہ نہيں گئي كيونكہ انہوں نے بہرحال محكوم مذہب كے لئے طبقاتي عنصر كو فرض كر كے محور اور راہ عمل كے درميان مطابقت كے قانون كي تصديق كي ہے۔ دوسرے لفظوں ميں انہوں نے ماہيت مذہب اور ہر ثقافت سے وجود پذير ہونے والي حقيقت كے مادي ہونے اور ايك ثقافتي تخليق كے محور اور اس كے راہ عمل كے درميان مطابقت يقيني ہونے كے قانون كو غير شعوري طور پر تسليم كيا ہے اور اہم بات يہ ہے كہ وہ ماركس اور ماركسٹوں كے نظريے كے برخلاف ايسے مذہب كے وجود كے بھي قائل ہوئے ہيں، جس كا محور و مقصد محروم اور تباہ حال طبقہ ہے، انہوں نے محكوم مذہب كي راہ عمل كے اعتبار سے حقيقتاً ايك دلچسپ توجيہ كي ہے، ليكن محور و مقصد كي ماہيت كے اعتبار سے ايسي توجيہ نہيں كر سكے، جسے بہرحال مادي اور طبقاتي قبول كرنا پڑا ۔“
اس سے حاصل ہونے والا نتيجہ كيا ہے؟ يہ ہے كہ صرف حكمران طبقے سے تعلق ركھنے والا مذہب شرك اور مذہب حاكم ہي وہ عيني تاريخي مذہب ہے، جو زندگي پر اپنا اثر قائم كئے ہوئے ہے، اس لئے كہ ان كے پس پشت جبر تاريخ كا ہاتھ ہے۔ ان كے اختيار ميں اقتصادي اور سياسي طاقت رہي ہے اور اسي لئے ان كا مذہب بھي جو ان كے مفادات كا آئينہ دار تھا، چھپا رہتا تھا، ليكن مذہب توحيد ايك بيروني اور عيني وجود كي صورت ميں معاشرے ميں نہ اتر سكا۔ اس نے معاشرے ميں كوئي تاريخي كردار ادا نہيں كيا اور نہ كر سكتا تھا كيونكہ عمارت بنياد پر سبقت نہيں لے جا سكتي۔
”اس اعتبار سے انبياء كي توحيدي تحريكيں تاريخ كي محكوم اور شكست خوردہ تحريكيں ہيں اور اس كے علاوہ ہو بھي نہيں سكتي تھيں۔ توحيدي مذہب كے انبياء عليھم السلام نے برابرى كے مذہب كو پيش كيا ہے، ليكن اس كے بعد زيادہ عرصہ نہيں گزرا كہ شرك كے مذہب نے انبياء عليہم السلام كي تعليمات كے پس پردہ، نقاب توحيد تلے اپنا كام جاري ركھا اور ان تعليمات كي تحريف كے بعد اسي كو اپني غذاء بنا كر پہلے سے زيادہ طاقت ور ہوگيا اور محروم طبقے كي ايذا رساني ميں مزيد قوت حاصل كي ۔“
”درحقيقت سچے نبيوں نے اپني تمام تر كوششوں كے بعد لوگوں كے لئے كچھ سرو سامان كا انتظام كيا، ليكن وہي چيز لوگوں كے لئے بلائے جان بن گئي اور مخالف طبقے نے اسے اپنا آلہ كار بنا كر محروم اور بيكس و برباد لوگوں كے گلے كي رسي كو تنگ كر ديا۔انبياء عليھم السلام اپني تعليمات كے ذريعے جس چيز كو پائے تكميل تك پہنچانا چاہتے تھے، وہ نہ پہنچ سكي اور جو كچھ ہوا، وہ ان كا مقصد نہ تھا ۔“يہ تعبير فقہا:
ماقصد لم يقع وما وقع لم يقصد
”يعني جو قصد كيا گيا، واقع نہ ہوا اور جو واقع ہوا، مقصود نہ تھا ۔“
”يہ جو مادہ پرست اور مذہب دشمن عناصر كہتے ہيں، دين معاشرے كي منشيات كي طرح ہے، جمود اور ركاوٹ كا عمل ہے، مظالم اور بے جا امتيازات كي توجيہ كرنے والا ہے، جہل كا محافظ ہے اور عوام الناس كے لئے افيون ہے، بالكل درست ہے، ليكن اس مذہب كے لئے جو مسلط، مشرك اور بے جا امتيازات كا حامل ہے اور جو تاريخ پر چھايا رہا ہے ليكن يہ بات سچے مذہب كے لئے جھوٹ ہے، جو توحيدي اور محكوم اور مستضعف لوگوں كا مذہب ہے اور جسے ہميشہ اوراق حيات اور تاريخ كے صفحات سے دور ركھا گيا ہے ۔“
”وہ تنہا كردار جسے محكوم مذہب نے ادا كيا ہے، اعتراض اور عمل تنقيد ہے اور يہ بات ايسي ہے، جيسے كوئي پارٹي قانون ساز ادارے ميں اكثريت سے كامياب ہو اور حكومت بنائے اور اپنے پروگرام اور اپنے فيصلوں كو روبہ عمل لائے اور دوسرا گروہ ہرچند زيادہ قابل اور زيادہ ترقي يافتہ ہو، مگر ہميشہ اقليت ميں پڑا رہے، تو اس سے بجز اس كے اور كچھ نہ ہوگا كہ وہ اكثريت كے كاموں پر تنقيد اور اعتراض كرتا رہے ۔“
”اكثريت كي حامل پارٹي تنقيدوں پر كان نہيں دھرتي اور معاشرے كو جس نہج پر چلانا چاہتي ہے، چلاتي ہے اور كبھي كبھي اقليت كے اعتراضات اور انتقادات سے اپنے كام كو استحكام بخشنے كے لئے استفادہ كرتي ہے۔ اگر ان انتقادات كو وجود نہ ہوتا، تو ممكن تھا، وہ خود ايك دباؤ كے زير اثر ايك دن ختم ہوجاتى، ليكن اقليت كي تنقيديں اسے متنبہ كرتي رہتي ہيں اور وہ اپنے آپ كو سنبھالتي رہتي ہے اور اسي كے ذريعے اس كي پوزيشن مستحكم تر ہوتي چلي جاتي ہے ۔“
مذكورہ بيان كسي اعتبار سے درست نہيں ، نہ مذہب شرك كي ماہيت سے متعلق تجزيہ كے اعتبار سے اور نہ مذہب توحيد كي ماہيت سے متعلق تجزيہ كے اعتبار سے اور نہ ہي اس كردار كے اعتبار سے جسے تاريخ نے ان دونوں مذاہب كے بارے ميں پيش كيا ہے، بلاشبہ مذہب كا وجود دنيا ميں ہميشہ رہا ہے۔ اس سے صرف نظر كرتے ہوئے كہ وہ مذہب توحيد ہو يا مذہب شرك يا پھر دونوں طرح كے، ماہرين عمرانيات كي رائے اس بارے ميں مختلف ہے كہ كيا مذہب شرك كو مذہب توحيد پر زمانے كے اعتبار سے تقدم حاصل ہے يا اس كے برعكس مذہب توحيد مذہب شرك پر تقدم ہے، بيشتر افراد كي رائے يہ ہے كہ پہلے مذہب شرك وجود ميں آيا اور پھر اس نے بتدريج ترقي كي اور توحيد تك پہنچا اور بعض اس كے برعكس كہتے ہيں ۔
ديني روايات بلكہ بعض ديني اصول دوسرے نظريے كي تائيد كرتے ہيں، كيا واقعاً مذہب شرك بے جا امتيازات اور مظالم كي توجيہ كے لئے ظالم اور ستم گر افراد نے ايجاد كيا يا اس كا كوئي اور سبب ہے؟ محققين نے اس كے لئے دوسرے اسباب كا تذكرہ كيا ہے، يہ بات اتني آساني سے قابل قبول نہيں كہ شرك اجتماعي امتيازات كي پيداوار ہے اور مذہب توحيد كي يہ تحليل كہ يہ امتيازات كے مخالفين، يگانگت و بھائي چارے كے موافقين اور محروم طبقے كے مطالبات كے لئے ايك توجيہ ہے، يہ پہلي بات سے زيادہ غير عالمانہ بات ہے ۔
علاوہ ازيں يہ بات مباني اسلام سے بھي ہرگز ہم آہنگ نہيں، مذكورہ بيان، اللہ كے سچے پيغمبروں كو ”ناكام كامياب“ كے عنوان سے پيش كرتا ہے۔ ناكام اس اعتبار سے كہ انہوں نے باطل سے شكست كھائي اور تاريخ كے پورے سلسلے ميں مغلوب رہے۔ ان كا مذہب معاشرے پر اثر انداز نہ ہو سكا اور نہ ہي كم از كم حاكم اور باطل مذہب جيسا كوئي قابل توجہ كردار اپنے لئے متعين كر سكا۔ مذہب حاكم پر تنقيد و اعتراض كے علاوہ اس نے اور كوئي كردار ادا نہيں كيا اور كامياب اس اعتبار سے كہ ماديت كے حاميوں كے دعوے كے برخلاف ان كا تعلق استعماري اور استحصال پسند طبقے سے نہيں تھا اور يہ لوگ جمود اور ركاوٹوں كے عامل نہيں تھے۔ ان كي متعين راہ اس طبقے كے حق ميں نہيں تھي بلكہ اس كے برعكس مستضعف اور استحصال كاشكار ان كے پيش نظر تھے۔ ان لوگوں نے ان كے درد كو سہا تھا، انہي ميں سے اٹھے تھے اور انہي كے مفاد اور انہي كے كھوئے ہوئے حقوق كو واپس دلانے كے لئے كوشاں تھے ۔
سچے انبياء عليہم السلام اپني رسالت اور روح دعوت كے اعتبار سے كہ جو ان كے محور و مقصد اور طرزعمل سے عبارت ہے، كامياب ہيں، اپني ناكامي كے پہلو كے اعتبار سے بھي مكمل طور پر كامياب ہيں، يعني وہ خود اپني ناكامي كے ذمہ دار نہيں ہيں كيونكہ اختصاصي مالكيت كے نتيجے ميں ابھرنے والے ”جبر تاريخ“ كا ہاتھ حريف كو تھامے ہوئے ہے۔ اختصاصي مالكيت كے وجود نے جبراً اور قہراً معاشرے كو دو حصوں ميں بانٹ ديا ہے، ايك حصہ استحصال پسندوں كا تھا اور دوسرا استحصال كے شكار لوگوں كا۔ استحصال پسند جن كے ہاتھ ميں مادي پيداوار تھى، قہراً معنوي پيداوار كے مالك بھي تھے اور پھر اس جبر تاريخ سے كون پنجہ لڑا سكتا ہے، جو قضاء و قدر سے عبارت ہے، يہ وہ قضاء و قدر ہے، جس كا خدا مادي تعبير كے اعتبار سے آسمانوں ميں نہيں، زمين ميں ہے اور مجرد نہيں مادي ہے، گويا يہ وہي حاكميت كي طاقت ہے جسے معاشرے كي اقتصادي اساس كا نام ديا جاتا ہے اور جو پيداواري آلات كے گرد گھومتي ہے۔ پس انبيائے الٰہي اپني ناكامي كے ذمہ دار نہيں ہيں ۔
مذكورہ بيان جس كے مطابق انبياء عليھم السلام اپني ناكامي كے بارے ميں بري الذمہ ہيں، ہستي كا وہ حقيقي نظام جس كے بارے ميں كہا جاتا ہے كہ وہ ايك نظام خير اور نظام حق ہے اور خير، شر پر غلبہ پاتا ہے، كے مطابق غلط ثابت ہوتا ہے۔ توحيد كے پرستار جو نظام ہستي كو اچھي نگاہ سے ديكھتے ہيں، كہتے ہيں كہ نظام ہستي نظام حق ہے، نظام خير ہے، اس ميں سچائي ہي سچائي ہے۔ شر، باطل، نادرستى، ايك عرضى، طفيلي اور ناپائيدار وجود كي حامل ہے۔ انسان كے نظام ہستي يا نظام اجتماعي كا محور و مدار ”حق“ ہے۔ قرآن حكيم ميں ہے:
( فاما الزبد فيذهب جفاءاً و امّا ما ينفع الناس فيمكث في الارض ) . (سورہ رعد، آيت ۱۷)
”پس جو جھاگ ہے وہ كھڑي ہوجاتي ہے اور جو چيزلوگوں كے لئے كار آمد ہے وہ باقي رہتي ہے ۔“
اور كہا جاتا ہے كہ حق و باطل كي جنگ ميں حق كو كاميابي نصيب ہوتي ہے ۔
( بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. ) (سورہ انبياء، آيت ۱۸)
”بلكہ ہم حق كو باطل پر پھينك مارتے ہيں، پھر وہ اس باطل كا بھيجہ نكال ديتا ہے، (يعني اس كو مغلوب كر ديتا ہے) سو وہ مغلوب ہو كر دفعتہ جاتا رہتا ہے ۔“
يہ بھي اللہ كي تائيد سچے نبيوں كے ساتھ ہوتي ہے ۔
( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ) . (سورہ مومن، آيت ۵۱)
”ہم اپنے پيغمبروں كي اور ايمان والوں كي دنيوي زندگي ميں مدد ضرور كريں گے اور جس دن گواہ اٹھ كھڑے ہوں گے ۔“
( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ) (سورہ صافات، آيت۱۷۱ ۔۱۷۳)
”اور اپنے خاص بندوں پيغمبروں سے ہماري بات پكي ہو چكي ہے كہ ان لوگوں كي يقيني مدد كي جائے گي اور ہمارا لشكر تو يقينا غالب رہے گا ۔“
ليكن گذشتہ بيان سے اس اصول كي ترديد ہوتي ہے۔گذشتہ بيان كے اعتبار سے ہر چند كہ تاريخ ميں تمام انبياء، تمام رسول اور تمام مصلحين بري الذمہ ثابت ہوتے ہيں، ليكن ان پيغمبروں كے خدا پر الزام عائد ہوتا ہے ۔
سچ تو يہ ہے كہ مسئلہ بڑا ٹيڑھا ہے ۔ ايك طرف تو قرآن عالم كے كلي امور كے بارے ميں ايك اچھي نگاہ ركھتا ہے اور اس بات پر اصرار كرتا ہے كہ ”حق“ ہستي اور انسان كي اجتماعي زندگي كا محور ہے، پھر حكمت الٰہي بھي اپنے مخصوص اصول كي بنياد پر اس بات كي مدعي ہے كہ ہميشہ شر اور باطل پر خير اور حق كا غلبہ ہوتا ہے اور شر اور باطل كو وجود عرضى، غير اساسي اور طفيلي ہوا كرتا ہے ۔
دوسري طرف گذشتہ اور حال كي تاريخ كا مطالعہ اور مشاہدي موجودہ نظام كے بارے ميں ايك طرح كي بد بيني پيدا كرتا ہے اور اس تصور كو ابھارتا ہے كہ لوگوں كا يہ كہنا بے جا نہيں كہ پوري تاريخ درد ناك واقعات، مظالم، حق كشي اورا ستحصال كا مرقع ہے ۔
كيا كہا جائے؟ كيا ہم نظام ہستي اور انسان كے اجتماعي نظام كو سمجھنے ميں غلطي كر رہے ہيں؟ يا يہ كہ اس ميں غلطي نہيں كر رہے بلكہ قرآن فہمي ميں ہميں اشتباہ ہو رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہيں كہ ہستي اور تاريخ كے بارے ميں قرآن كا نظريہ خوش فہمي پر مبني ہے؟ يا پھر كسي ميں كوئي اشتباہ نہيں ہو رہا اور يہ تناقص حقيقت اور قرآن كے درميان پايا جاتا ہے اور اس كا كوئي حل نہيں ۔
ہم اس شبہ كو نظام ہستي تك اپني كتاب ”عدل الٰہي“ ميں خدا كے لطف و كرم سے حل كر چكے ہيں اور باقي جو تاريخ كے واقعات اور انسان كي اجتماعي زندگي سے متعلق ہے، آئندہ كي كسي بحث ميں”حق و باطل“ كا معركہ كے عنوان سے پيش كريں گے اور عنايت الٰہي سے اس شبہ كو دور كرنے كي كوشش كريں گے۔ہميں خوشي ہوگى، اگر اہل نظر اس مسئلے ميں اپنے مستدل نظريات پيش كرنے كي زحمت فرمائيں ۔
____________________
۵۹. مزيد معلومات كے لئے ملاحظہ فرمائيں: جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم پر ايمان لانے افراد كے بارے ميں سورہ كہف آيت ۔۲۸، جناب نوح عليہ السلام كي امت كے بارے ميں سورہ ہود آيت ۔۱۱۱، جناب موسيٰ عليہ السلام كے پيروكاروں كے بارے ميں سورہ يونس آيت ۔۸۳، جناب شعيب عليہ السلام پر ايمان لانے والوں كے بارے ميں سورہ اعراف آيت ۔۸۸ ۔۹۰، جناب صالح عليہ السلام كا ساتھ دينے والوں كے بارے ميں سورہ اعراف آيت ۔۷۵۔۷۶ ، طوالت سے بچنے كے لئے انہي آيتوں كا اشارہ كافي ہے۔
۶۰. فٹ نوٹ ميں سورہ جمعہ كي دوسري آيت: ”هو الذي بعث في الاميين رسولا “ اور سورہ بقرہ كي ۱۲۹ويں آيت كا ذكر ہے، جو اس بات كو ظاہر كرتي ہے كہ انبياء عليھم السلام كا تعلق ”امتوں“ سے ہے اور امتوں سے مراد محروم طبقے ہيں، ہم بعد ميں اس استدلال كا جائزہ ليں گے۔
۶۱. فٹ نوٹ ميں سورہ قصص كي آيت: ”ونزعنا من كل امة شهيدا “ كي طرف اشارہ كيا گيا ہے اور يہ فرض كيا گيا ہے كہ آيت اس مفہوم كو پيش كرتي ہے كہ اللہ كي راہ ميں شہيد ہونے والے ہميشہ ”امتوں“ اور چھوٹے طبقوں ميں سے ابھرتے ہيں، اس آيت كے بارے ميں بھي ہم اپنے مقام پر گفتگو كريں گے۔
۶۲. يہ لوگ اس بات كے اظہار كے بغير كہ ماركس كي تاريخي ماديت كا سانچہ بنا رہے ہيں، اپنے اول خول كو ”معرفت قرآني“ كے انعكاس كا غلاف چڑھا كر پيش كر رہے ہيں ۔
۶۳. سورہ نساء آيت۹۷، سورہ ابراہيم آيت۲۱، سورہ نساء آيات۱۳ تا ۳۷، سورہ مومن آيات۴۷ تا۵۰.
معيار اور پيمانے
ہويت تاريخ كے بارے ميں كسي مكتب كے نقطہ نگاہ كو جانچنے كے لئے كچھ معيار اور پيمانوں سے استفادہ كيا جا سكتا ہے اور ان پيمانوں كو سامنے ركھ كر اچھي طرح اس بات كا علم ہو سكتا ہے كہ وہ مكتب تاريخي انقلابات اور تاريخي واقعات كو كس نظر سے ديكھتا ہے۔ اس سلسلے ميں جو معيار اور جو پيمانے ہماري نظر تك پہنچے ہيں، انہيں ہم يہاں پيش كرنا چاہيں گے۔ البتہ ممكن ہے اس كے علاوہ اور پيمانے بھي ہوں، جو ہماري نظر سے پوشيدہ رہ گئے ہوں ۔
اس سے پہلے كہ ہم ان معياروں كو پيش كريں اور ان كے ذريعے اسلام كا نظريہ حاصل كرنا چاہيں، اس بات كا تذكرہ ضروري ہے كہ ہماري نظر ميں قرآن ميں بعض اصولوں كي نشاندہي ہوئي ہے جو واضح طور پر مادي بنياد پر معاشرے كي معنوي بنياد كي بالادستي كو ظاہر كرتے ہيں، قرآن واضح طور پر ايك قانون كي صورت ميں كہتا ہے:
( ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم ) . (سورہ رعد، آيت۱۱)
”خدا كسي قوم كي حالت اس وقت تك نہيں بدلتا، جب تك كہ وہ خود اپنے ارادے سے اس چيز كو نہ بدل دے، جس كا تعلق اس كي رفتار و كردار سے ہے ۔“
بعبارت ديگرلوگوں كي تقدير اس وقت تك نہيں بدلتى، جب تك كہ وہ خود اپني ان باتوں كو نہ بدل ديں، جو ان كے نفوس اور احساسات سے متعلق ہيں۔ يہ آيت تاريخ كے اقتصادي جبر كي صريحاً نفي كرتي ہے۔ بہرحال ہم نے جن پيمانوں كي تشخيص كي ہے، اسے پيش كر كے اسلام كو ان پيمانوں سے پركھنے كي كوشش كريں گے ۔
۱۔ دعوت سے متعلق حكمت عملى
ہر وہ مكتب جو معاشرے كے لئے كسي پيام كا حامل ہے اور لوگوں كو اس پيام كو قبول كرنے كي طرف بلاتا ہے، لازمي طور پر ايسي خاص روش اور ايسے طريقہ كار سے استفادہ كرتا ہے، جو ايك طرف تو اپنے اصلي اغراض و مقاصد سے متصل ہوتا ہے اور دوسري طرف اپنے اس نقطہ نظر سے متعلق ہوتا ہے، جو وہ تاريخ كے انقلابات اور تحريكوں كي ماہيت كے بارے ميں ركھتا ہے ۔
كسي مكتب كي دعوت كا مطلب لوگوں كو بيدار كرنا اور ان حساس مسائل كو اٹھانا ہے، جن سے لوگوں ميں حركت پيدا ہو مثلا ”اگسٹ كانٹ“ كا مكتب انسانيت جسے وہ ايك طرح كا سائنسي مذہب سمجھتا ہے اور انسان كے جوہر تكامل كو اس كي ذہنيت ميں ديو مالائي فلسفي صورتوں پر مبني دو مرحلوں ميں طے كرتا ہے اور كہتا ہے كہ انسان نے اپني ذہنيت ميں ديومالائي اور فلسفي صورتوں پر مبني دو مرحلوں كو طے كر كے سائنسي مرحلہ تك رسائي حاصل كر لي ہے۔ اب جو بيداري وہ لوگوں ميں پيدا كرنا چاہتا ہے، وہ گويا سائنسي بيداري ہے اور لوگوں كو حركت ميں لانے كے لئے جن حساس مسائل سے كام لينا چاہتا ہے، وہ بھي سائنسي مسائل ہي ہيں ۔
يا ماركسزم جو محنت كش طبقے كي انقلابي تھيوري ہے، جو بيداري ديتي ہے، وہ محنت كشوں كے شعور كو طبقاتى تضاد سے عبارت مسائل كو اٹھاتي ہے، ان كا تعلق رنجشوں، محروميوں اور حق تلفيوں سے ہوتا ہے۔ معاشرے اور تاريخ كے بارے ميں كسي مكتب كا كيا نظريہ ہے؟ اس سے ہٹ كر كہ مكاتب جو بيداري ديتے ہيں اور جن مسائل كو اٹھاتے ہيں، وہ مختلف ہوتے ہيں۔ تاريخ، تكامل تاريخ اور انسان كے بارے ميں جس مكتب فكر كا جو نظريہ ہوگا، اس كي دعوت بھي اسي انداز كي ہوگي اور دعوت كي تاثير، دباؤ اور دعوت كے درميان رابطے اور دباؤ كے اخلاقي يا غير اخلاقي ہونے كي نظريات ميں يہ مكاتب اس اعتبار سے مختلف ہوجاتے ہيں۔
بعض مكاتب جن ميں مسيحيت كا بطور مثال ذكر كرتے ہيں، انسانوں كے رابطے ميں جس چيز كو اخلاقي سمجھتے ہيں، وہ صرف دعوتوں كي پرامن نوعيت ہے، يہ لوگ زور اور دباؤ كو ہر صورت ميں، ہر حالت اور ہر شرط پر غير اخلاقي گردانتے ہيں، لہٰذا اس مذہب كا مقدس كلمہ يہ ہے كہ اگر كوئي تمہارے داہنے گال پر تھپڑ رسيد كرے، تو تم باياں گال بھي اس كے آگے كر دو اور اگر كوئي تمہارا جبہ تم سے چھين لے، تو تم اپني ٹوپي بھي اس كے حوالے كر دو۔ اس كے مقابلے پر ”نطشے“ كي طرح بعض مكاتب جس واحد چيز كو اخلاقي سمجھتے ہيں، وہ دباؤ اور طاقت ہے۔ اس لئے كہ انسان كا كمال اس كي طاقت ميں ہے۔ ايك طاقت ور شخص مقدر ترين شخص كے برابر ہے۔ ”نطشے“ كي نظر ميں عيسائيت كا اخلاق غلامى، ضعف اور ذلالت سے عبارت ہے، نيز انساني جمود كا بنيادي عامل ہے۔
بعض دوسرے انداز فكر كے لوگ بھي اخلاق كو دباؤ اور طاقت سے وابستہ جانتے ہيں، ليكن ہر دباؤ ان كي نظر ميں اخلاق نہيں ہوتا۔ ماركسزم كے نقطہ نظر سے وہ طاقت جو استحصال كرنے والا استحصال ہونے والے كے خلاف استعمال كرتا ہے، غير اخلاقي ہے، چونكہ اس كا عمل موجودہ حالات كو اپني جگہ برقرار ركھتا ہے اور عامل توقف ہے، ليكن وہ زور جسے استحصال ہونے والاكام ميں لاتا ہے، اخلاق ہے كيونكہ وہ اس كے ذريعے، معاشرے ميں تبديلي لا كر اسے اگلي منزل تك پہنچانا چاہتا ہے ۔
بعبارت ديگر معاشرے پر حكم فرما دائمي جنگ جس ميں دو گروہ ايك دوسرے سے نبرد آزما ہيں، ايك ”تھيسز“ كا كردار ادا كر رہا ہے اور دوسرا ”اينٹي تھيسز“ كا، وہ طاقت جو ”تھيسز“ كا كردار ادا كر رہي ہے كيونكہ رجعت پسندہے، لہٰذا غير اخلاقي ہے، جبكہ وہ طاقت جو ”اينٹي تھيسز“ كا كام كرتي ہے كيونكہ انقلابي اور ترقي دينے والي ہے، لہٰذا اخلاقي ہے، البتہ يہي طاقت جو ابھي اخلاقي ہے، بعد ميں جب دوسري طاقت سے جو اسے نابود كرنے والا كردار ادا كرے گى، نبرد آزما ہوگى، تو اس وقت اس كا كردار رجعت پسندانہ ہو جائے گا اور اس كے تازہ رقيب كا كردار اخلاقي ہو جائے گا، لہٰذا اخلاقي نسبي ہے، يعني جو ايك مرحلے ميں اخلاق ہے، اس سے كامل تر اور بلند تر مرحلے ميں خلاف اخلاق ہے۔
پس عيسائيت كے نقطہ نگاہ سے مخالف گروہ جو اس مكتب كي نظر ميں تكامل كي راہ ميں ركاوٹ ہے، سے مكتب كا تعلق صرف ايك رابطہ ہے، رابطہ بھي نرمي اور ملائمت كے ساتھ دعوت كا راستہ ہے اور رابطے كا يہي انداز اخلاقي ہے ۔
نطشے كے مطابق اخلاقي رابطہ صرف وہ رابطہ ہے، جو ايك طاقتور، ضعيف كے ساتھ ركھتا ہے اور طاقت سے زيادہ اخلاق كوئي چيز نہيں اور كمزور ہونا سب سے بڑا غير اخلاقي امر ہے، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ كمزوري ہے، ماركسزم كي رو سے اقتصادي نقطہ نظر سے دو مخالف گروہوں كا ايك دوسرے سے رابطہ سوائے زور اور طاقت كے اور كچھ نہيں ہو سكتا۔ طاقت كے اس رابطہ سے استحصال كرنے والے طبقے كي طاقت تكاملي عمل ميں ركاوٹ بننے كي وجہ سے غير اخلاقي اور استحصال شدہ طبقے كي طاقت اخلاقي ہے۔ يہاں يہ بحث ہي نہيں كہ تازہ دم طاقت كا ”ويراني طاقت“ سے رابطہ ايك معركہ بھي ہے اور اخلاقي بھي ہے ۔
اسلام كے نقطہ نظر سے مذكورہ تمام نظريات مذموم ہيں، عيسائيت كے خيال كي طرح اخلاق كو صرف باہمي توافق، دعوت كي نرمى، صلح وصفا اور محبت ميں سميٹا نہيں جا سكتا، بعض اوقات زور اور طاقت بھي اخلاق بن جاتے ہيں، لہٰذا اسلام زور اور ظلم كے خلاف جنگ كو مقدس كام اور فريضہ قرار ديتا ہے اور اسلحے سے جہاد كو خاص حالات اور خاص موقع پر تجويز كرتا ہے ۔
صاف ظاہر ہے كہ نطشے كا نظريہ ايك مہمل، عبث، نغير انساني اور كمال دشمن نظريہ ہے ۔
ماركسزم كا نظريہ اسي ميكانزم پر مبني ہے، جس ميكانزم كو وہ تكامل تاريخ كے بارے ميں ضروري سمجھتا تھا۔ اسلام كي رو سے كمال دشمن گروہ سے طاقت كے ذريعے نمٹنا ماركسزم كے نظريے كے برخلاف پہلا نہيں دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ حكمت اور موعظہ حسنہ كا ہے۔
( ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنه ) . (سورہ نحل، آيت۱۲۵)
كمال دشمن گروہ كے خلاف طاقت كے استعمال كا مرحلہ اس دم اخلاقي ہے، جب فكري اقناع (حكمت و برہان) اور روحي اقناع نصيحت اور موعظہ كے مرحلے طے ہوگئے ہوں اور كوئي نتيجہ برآمد نہ ہوا ہو۔
يہي وجہ ہے كہ جو انبياء عليھم السلام جنگوں سے گذرے ہيں، انہوں نے اپني دعوت كے پہلے مرحلے كو حكمت، موعظہ حسنہ اور كبھي كبھار كلامي مجادلہ سے گذارا ہے اور جب اس راہ سے كسي نتيجے پر نہيں پہنچے يا نتيجہ سامنے نہيں آيا، بلكہ ايك نسبي نتيجہ تك رسائي ہوگئى، تو پھر انہوں نے جنگ، جہاد اور طاقت كے استعمال كو اخلاقي جانا۔ بنيادي طور پر چونكہ اسلام مادي نہيں بلكہ معنوي بنيادوں پر سوچتا ہے، اس لئے وہ برہان، استدلال، موعظہ اور نصيحت كے لئے ايك عجيب طاقت كا قائل ہے ۔
جس طرح (بہ تعبير ماركس) اسلحہ كے ذريعے تنقيد ايك طاقت ور چيز ہے، اسي طرح تنقيد كا اسلحہ بھي اپني جگہ ايك طاقت ہے اور اس سے استفادہ كيا جانا چاہيے۔ البتہ اسے واحد ايسي طاقت نہيں سمجھتا جو ہر جگہ استعمال كي جا سكتي ہو، يہ بات كہ اسلام رشد و تكامل سے دشمني كرنے والے گروہ كے ساتھ جنگ كو دوسرا مرحلہ سمجھتا ہے، پہلا نہيں اور برہان، موعظہ اور جدال حسن كو ايك طاقت گردانتا ہے۔ اسلام كي وہ خاص معنوي نگاہ ہے، جو وہ انسان اور اس كے تحت معاشرے اور تاريخ كے بارے ميں ركھتا ہے ۔
پس يہ بات معلوم ہوئي كہ كسي مكتب كا اپنے مخالف محاذ سے رابطہ محض دعوت كي بنياد پر ہو يا محض جنگ كي بنياد پر يا پہلے دعوت اور اس كے بعد جنگ و جدال كي بنياد پر ہو، منطقي اور بياني طاقت كي تاثير اور اس كي حدود كے بارے ميں اس مكتب كي سوچ كو ظاہر كرتا ہے اور اسي طرح تاريخي واقعات اور ان ميں جنگ كے كردار كے بارے ميں اس كے نظريات كو واضح كرتا ہے ۔
اب ہم بحث كے دوسرے حصے ميں آتے ہيں اور ديكھتے ہيں كہ اسلامي بيداري كي نوعيت كيا ہے اور وہ كون سے مسائل ہيں، جن پر زور دے كر اسلام اپني دعوت پيش كرتا ہے ۔
اسلامي بيداري پہلے درجہ ميں مبداء و معاد كے بارے ميں نصيحت كرنے جيسے امور ہيں اور وہ حكمت عملى، جس سے قرآن بھي كام ليتا ہے اور انبياء عليھم السلام ماسبق نے بھي كام ليا ہے۔ انبياء عليھم السلام اس امر ميں انسان كو متوجہ كرنا چاہتے تھے كہ وہ كہاں سے، كہاں پر اور كہاں كے لئے آيا ہے اور كہاں ہے اور كہاں جانے والا ہے؟ يہ دنيا كہاں سے نمودار ہوئي ہے اور كس مرحلے كو طے كر رہي ہے اور اسے كہاں جانا ہے؟ سب سے پہلے انبياء عليھم السلام نے جو ذمہ داري سامنے ركھى، وہ تمام مخلوقات اور كل ہستي كے بارے ميں ذمہ داري تھي اور معاشرتي ذمہ داري اسي كا ايك حصہ ہے۔ ہم پہلے اس بات كي طرف اشارہ كر چكے ہيں كہ ان تمام مكي سورتوں ميں جو جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كي بعثت كے ابتدائي ۱۳ سالوں ميں نازل ہوئيں، كم ہي ايسي گفتگو ہوئي ہے، جو مبداء اور معاد كے تذكرہ سے خالي ہو۔(۶۴)
جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم نے اپني دعوت كا آغاز ”قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا“ يعني ايك اعتقادي انقلاب اور ايك فكري تطہير سے كہا، يہ ٹھيك ہے كہ توحيد وسيع پہلوؤں كي حامل ہے اور اگر تمام اسلامي تعليمات كا تجزيہ عمل ميں آئے، تو وہ توحيد كي طرف پلٹيں گي اور اگر توحيد كي تركيب كي جائے، تو اسلامي تعليمات پر منتہي ہوگى، (تفسير الميزان سورہ آل عمران كي آخري آيتوں كے ذيل ميں) ليكن ہمين معلوم ہے كہ آغاز كار ميں اس جملے ”قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا“ مقصود نہ فقط شرك آميز عبادات كو چھوڑ كر فكري اور عملي طور پر توحيد سے وابستہ ہونا تھا اور نہ بالفرض اتنا وسيع مقصد پيش نظر تھا كہ لوگوں كا دھيان اس طرف جاتا ۔
يہ مضبوط اور محكم آگاہي جس كي جڑيں انساني فطرت كي گہرائي ميں موجود ہيں، انسانوں ميں عقيدہ سے متعلق ايك طرح كي غيرت اور پختگي پيدا كرتي ہے اور اپنے عقيدے كو پھيلانے اور رواج دينے كا وہ جذبہ بيدار كرتي ہے كہ وہ اس راستے ميں جان و مال اور منصب و اولاد قربان كرنے سے بھي دريغ نہيں كرتا۔ انبياء عليھم السلام اس منزل سے اپنے كام كا آغاز كرتے تھے، جو ہمارے اس دور ميں عمارت كہلاتي ہے، اس ذريعے سے بنياد تك پہنچتے تھے۔ انبياء عليھم السلام كے مذاہب ميں انسان اپنے مفادات سے زيادہ اپنے عقيدے، مسلك اور ايمان سے وابستہ ہوتا ہے۔ در حقيقت اس مكتب ميں فكر اور عقيدہ بنياد اور كام يعني طبيعت اور مظاہر طبيعت يا معاشرے كے ساتھ رابطہ عمارت ہے۔ ہر ديني دعوت كو پيغمبرانہ ہونا چاہيے، يعني اسے دائمي طور پر مبداء اور معاد كے ساتھ ملاہونا چاہيے۔ انبياء عليھم السلام احساس كولوگوں ميں جگا كر ان كے شعور ميں باليدگي پيدا كر كے، ان كے وجدان سے غبار كو ہٹا كر ان ميں ايسي آگاہي پيدا كر كے رضائے حق، فرمان حق اور سزا و جزاء كے ذكر كے ساتھ معاشرے كو حركت ميں لاتے تھے۔ قرآن ميں ۱۳ مقامات پر اللہ كے ”رضوان“ كا ذكر آيا ہے، يعني انبياء عليھم السلام نے اس معنوي مسئلے پر ہاتھ ركھ كر اہل ايمان كو حركت دي۔ اس بيداري كو الٰہي يا عالمي بيداري بھي كہا جا سكتا ہے ۔
دوسرے مرحلے ميں اسلامي تعليمات ميں انسان كے بارے ميں آگاہي كو سامنے ركھا گيا ہے، يعني انسان كو اس كي كرامت ذات، اس كي شرافت ذات اور اس كي عزت و بزرگي ياد دلائي گئي ہے، مكتب اسلام ميں انسان ايك ايسا حيوان نہيں، جس كے وجود كي دليل يہ ہو كہ اس نے كروڑوں سال پہلے جب وہ دوسرے جانداروں كے ہمدوش اور ہمركاب تھا اور اس نے تنازع للبقاء كے دائرہ عمل ميں اس قدر خيانت كي كہ آج اس درجہ تك پہنچا بلكہ ايك ايسي ہستي ہے، جس ميں الٰہي جلوہ موجزن ہے۔ فرشتوں نے اس كے آگے سر جھكايا ہے، اس ہستي كے پيكر وجود ميں باوجود شہوت، شر اور فساد جيسے حيواني ميلانات كے، پاكيزگي كا جوہر موجود ہے، جو بدى، خونريزى، جھوٹ، فساد، پستى، حقارت اور ظلم كے ساتھ ساجھا نہيں كھاتا۔ وہ كبريائي عزت كا مظہر ہے ۔
( ولله العزة و لرسوله و للمومنين ) . (سورہ منافقون، آيت۸)
”عزت اللہ، اس كے رسول صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم اور مومنين كے لئے ہي ہے ۔“
جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كا ارشاد ہے:
شرف المومن قيامه بالليل و عزة استغناؤه عن الناس .(۶۵)
”مرد كي شرافت اس كي شب بيداري اور اس كي عزت لوگوں سے بے نيازي ميں ہے ۔“
حضرت علي عليہ السلام نے صفين ميں اپنے ساتھيوں سے ارشاد فرمايا:
الحيوة في موتكم قاهرين و الموت في حيوتكم مقهورين
”زندگي يہ ہے كہ مر جاؤ مگر كاميابي كے ساتھ اور موت يہ ہے كہ زندہ رہو، مگر ذات كے ساتھ ۔“(۶۶)
امام حسين عليہ السلام ابن علي نے فرمايا:
لا اري الموت الا سعادة والحيوة مع الظالمين الا برما (۶۷)
”ميرے نزديك موت بجز سعادت اور ظالموں كے ساتھ زندگي كو بجز رنج كچھ نہيں ۔“
اور پھر يہ ارشاد فرمايا:
هيات منا الذلة .(۶۸)
”ذلت ہم سے بہت دور ہے ۔“
يہ سب عبارات انسان كي ذاتي شرافت اور حسن كرامت كو ظاہر كرتي ہيں اور يہ جو ہر فطرتاً ہر انسان ميں موجود ہے ۔
تيسرے مرحلے ميں حقوق اور معاشرتي ذمہ داريوں سے آگاہي ہے، قرآن ميں ايسے مقامات ہمارے سامنے آتے ہيں، جہاں دوسروں كے غصب شدہ حقوق يا پھر اپنے كھوئے ہوئے حقوق كے حصول كے لئے قرآن ہميں حركت ميں لانا چاہتا ہے۔
( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال و النساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ) . (سورہ نساء، آيت۷۵)
”تمہيں كيا ہوگيا ہے، آخر كيوں تم اللہ كي راہ ميں ان ستم رسيدہ مردوں، عورتوں اور بچوں كے لئے قتال نہيں كرتے، جو كہتے ہيں، اے ہمارے پالنے والے!تو ہميں ان ظالموں كے شر سے باہر اور اپنے لطف و كرم سے ہمارے لئے سرپرست اور ياور كا انتظام فرما دے ۔“
درج ذيل آيہ كريمہ ميں جہاد كي طرف رغبت كے لئے دو معنوي باتوں كا ذكر كيا گيا ہے۔ ايك يہ كہ يہ راستہ اللہ كا راستہ ہے اور دوسرے يہ كہ بے بس، بيچارے اور بے كس لوگ ظالموں كے چنگل ميںپھنس كر رہ گئے ہيں ۔
سورہ حج ميں ارشاد ہوتا ہے:
( اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله علي نصرهم لقدير؛ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز؛ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة واتو الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ) (سورہ حج، آيات۳۹ تا ۴۱)
”مومنوں كو بموجب اس كے كہ وہ مظلوم گردانے گئے ہيں، يہ اجازت دي گئي ہے كہ اپنے جنگي دشمن سے برسر پيكار ہيں، خدا مومنوں كي نصرت پر قادر ہے اور يہ مظلوم لوگ وہي ہيں، جنہيں اپنے گھروں سے باہر نكال ديا گيا ہے، جبكہ ان كا كوئي جرم نہيں، سوائے اس كے كہ انہوں نے كہا، اللہ ہمارا رب ہے اور اگر يہ بات نہ ہوتي كہ خدا بعض لوگوں كے شركو بعض ديگر لوگوں كے ذريعے دفع كرتا ہے، تو يہ تمام صومعے، دير، كنشت اور مسجديں منہدم ہو جاتيں، جن ميں كثرت سے اللہ كا ذكر كيا جاتا ہے۔ خدا ان لوگوں كي مدد كرتا ہے، جو اسے ياد كرتے ہيں۔ بے شك خدا غالب توانا ہے اور يہ وہ لوگ ہيں كہ اگر ہم انہيں زمين ميں اقتدار عطا كريں تو يہ نماز كو قائم كريں گے، زكوٰۃ ديں گے، بھلائي كا حكم ديں گے، برائي سے باز رہيں گے اور تمام كاموں كو اختتام تك پہنچانا اللہ ہي كا كام ہے ۔“
اس آيت ميں ہم ديكھتے ہيں كہ قرآن مجاہدين كے غصب شدہ حقوق كي طرف اشارہ كركے جہاد اور دفاع كي اجازت ديتا ہے، ليكن اس كے ساتھ وہ دفاع كے اصلي فلسفے كو بعض افراد كے غصب شدہ حقوق سے برتر، بہتر اور اصولي تر قرار ديتا ہے اور وہ يہ كہ اگر دفاع اور جہاد كا عمل نہ ہو اور اگر اہل ايمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بيٹھے رہيں، تو معابد و مساجد جو معاشرے كي معنوي حيات كا دھڑكتا ہوا دل ہيں، كو نقصان پہنچے گا اور وہ ويران ہوجائيں گي۔ سورہ نساء ميں ارشاد ہوتا ہے:
( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم ) . (سورہ نساء، آيت۱۴۸)
”خداوند عالم بري بات كے اظہار كو پسند نہيں كرتا، مگر مظلوم سے ۔“
ظاہر ہے يہ مظلوم كے قيام كي ايك طرح سے تشويق، سورہ شعراء ميں شعراء اور ان كے تصوراتي احساسات كي مذمت كے بعد ارشاد ہوتا ہے:
( الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ) (سورہ شعراء، آيت۲۲۷)
”مگر وہ لوگ جو ايمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال انجام ديئے اور اللہ كا ذكر كثرت سے كيا اور بعد اس كے كہ مظلوم واقع ہوئے، ظالم سے انتقام ليں ۔“
ليكن قرآن اور سنت رسول صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم ميں باوجود اس كے كہ ظالم كے بوجھ تلے دبنا بدترين گناہ اور احقاق حق ايك فريضہ ہے، پھر بھي انساني پہلو اور انساني قدروں كو اس سے الگ نہيں كيا گيا، قرآن كبھي كبھي نفسياتي قدروں، عداتوں اور نفساني خواہشوں كو وزن نہيں ديتا، مثلاً ہر گز يہ نہيں كہتا كہ فلاں گروہ نے اس طرح كھايا پيا ، بانٹ كر لے گئے، جي بھر كر عيش كيا، پھر تم كيوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بيٹھتے ہو ۔
اگر كسي كا سرمايہ اس سے زبردستي چھيننے كي كوشش كي جائے، تو اسلام اس كي اجازت نہيں ديتا كہ اس بہانے كي بنياد پر كہ ماديت كي كوئي اہميت نہيں، صاحب مال سكوت كر جائے، بالكل اسي طرح جس طرح اس بات كي اجازت نہيں كہ اگر كسي كي عزت پر حملہ ہو، تو متعلقہ شخص يہ كہہ كر خاموش ہوجائے يہ تو شہوت كي بات ہے، بلكہ اس امر ميں دفاع كو ضروري گردانتا ہے اور ”المقتول دون اھل و مالہ“ (يعني جو اپنے مال يا ناموس كي حفاظت كرتے ہوئے مارا جائے، اسے شہيد جانا ہے، ليكن اسلام نے جو اپنے مال كے بارے ميں دفاع سے متعلق امر كي حوصلہ افزائي كي ہے، اس ميں كسي حرص كو بنياد نہيں بنايا، بلكہ حق كے دفاع كي بات ہے، جو اپنے جگہ وزن ركھتي ہے، اسي طرح وہاں بھي جہاں اپني عزت و ناموس كا دفاع واجب گردانتا ہے، اس لئے نہيں كہ شہوت كو اہميت دي گئي ہے، بلكہ يہاں بھي معاشرے كي عظيم ترين آبرو يعني عفت كو پيش نظر ركھا گيا ہے اور مرد كو اس كا محافظ قرار ديا گيا ہے۔
۲۔ عنوان مكتب
ہر مكتب اپنے پيروكاروں كو ايك خاص عنوان ديتا ہے، وہ نظريہ جو مثلاً ايك نسلي نظريہ ہے ، اپنے پيروكاروں كو ايك نام ديتا ہے، جس كے اعتبار سے وہ ايك خاص”ہم“بن جاتے ہيں۔ بطور مثال گورے ہيں، اس وقت جب اس مكتب كے پيروكار لفظ ”ہم“ استعمال كرتے ہيں، تو مراد گوروں كا گروہ ہوتا ہے يا مثلاً ماركسي نظريہ جو مزدوروں سے متعلق ہے، اپنے پيروكاروں كو ”مزدور“ كا عنوان ديتا ہے۔ ان كي ہويت اور ان كو مشخص كرنے والي چيز ”مزدوري“ ہے، ان كا ”ہم“ مزدور كا ”ہم“ ہے۔ محنت كشوں اور مزدوروں كا ہم، عيسائي مذہب اپنے پيروكاروں كي ہويت كو ايك فرد كي پيروي ميں مشخص كرتا ہے۔ گويا پيروكاروں كا مقصد يا راستے سے كوئي سروكار نہيں، ان كي اجتماعي ہويت يہ ہے كہ جہاں عيسي عليہ السلام ہيں وہاں وہ ہيں۔ اسلام كي ايك خصوصيت ہے كہ اس نے نسلى، طبقاتى، مشاغلاتى، مقامى، علاقائي اور شخصي عناوين ميں سے كسي كو اپنے مكتب اور اس كے پيروكاروں كي شناخت كے لئے قبول نہيں كيا۔ اس مكتب كے پيروكار، اعراب، سامى، فقراء، اغنياء، مستضعف، گورے، كالے، ايشيائى، مشرقى، مغربى، محمدى، قرآن اور اہل قبلہ جيسے عناوين سے نہيں پہچانے جاتے۔ ان عناوين ميں كوئي بھي ”ہم“ اور وحدت كا معيار نہيں بنتا۔ يہ سب چيزيں اس مكتب كے پيروكار كي حقيقي ہويت ميں شمار نہيں ہوتيں۔ جب اس مكتب كي ہويت كي بات آتي ہے، تو پھر يہ تمام عناوين محو ہوجاتے ہيں۔ بس ايك چيز باقي رہ جاتي ہے، بھلا وہ كيا ہے؟ صرف ايك ”رابطہ“ خدا اور انسان كے درميان رابطہ، يعني اسلام جو منزل تسليم ہے۔ مسلمان قوم كون سي قوم ہے؟ وہ قوم ہے، جو خدا كے آگے تسليم ہے، حقيقت كے سامنے تسليم ہے، وحي و الہام كے سامنے تسليم ہے، وہ وحي جو افق حقيقت سے انسان كي رہنمائي كے لئے لائق ترين افراد كے قلب سے طلوع ہوئي ہے، تو پھر مسلمانوں كا ”ہم“ اور ان كي حقيقي ہويت كيا ہے؟ يہ دين ان كو كس قسم كي وحدت دينا چاہتا ہے۔ ان پر كون سي مہر لگانا چاہتا ہے اور كس پرچم تلے اكٹھا كرنا چاہتا ہے؟ اس كا جواب يہ مختصر سا جملہ ہے:اسلام، يعني حقيقت كے حضور سر تسليم خم كرنا ۔
ہر مكتب اپنے پيروكاروں كے لئے وحدت كے جس معيار كو پيش كرتا ہے، بس وہي اس مكتب كے اہداف اور انسان، معاشرے اور تاريخ كے بارے ميں اس كے نكتہ نظر كو سمجھنے كا بہترين ذريعہ ہے۔
۳۔ شرائط و موانع قبوليت
ہم پہلے عرض كر چكے ہيں كہ حركت تاريخ كا ميكانزم مختلف مكاتب كي نظر ميں مختلف رہا ہے۔ كوئي حركت كے طبيعي ميكانزم كو ايك طبقہ كے دوسرے طبقہ پر دباؤ، ايك طبقہ كے بالذات رجعت پسندہونے اور دوسرے طبقے كے بالذات انقلابي ہونے كو سمجھتا ہے، كوئي اصلي ميكانزم كو ايك انسان كي ترقي خواہانہ اور كمال جو يا نہ پاكيزہ فطرت ميں ديكھتا ہے اور اسي طرح كوئي كچھ اور كوئي كچھ اور۔ظاہر ہے كہ حركت سے متعلق ميكانزم جو مكتب جس انداز كا ميكانزم سمجھتا ہے، اسي انداز سے وہ ان شرائط، موجبات يا موانع اور ركاوٹوں كي وضاحت كرتا ہے، جو اس كي تعليمات ميں موجود ہوتي ہيں۔ وہ مكتب جس كے نزديك حركت سے متعلق ميكانزم ايك طبقہ كا دوسرے طبقہ پر دباؤ ہے، معاشرے كو حركت ميں لانے اور اس كے جمود كو توڑنے كے لئے اگر دباؤ ميں كمي محسوس كرتا ہے، تو اسے بڑھانے كي كوشش كرتا ہے۔ ماركس نے اپني بعض كتب ميں اس امر كي طرف توجہ دلائي ہے كہ”آزادي سے ہمكنار طبقہ كے لئے غلام طبقہ كا وجود ضروري ہے“۔ اس جائزے كے اختتام پر وہ لكھتا ہے:
”پس جرمن قوم كي آزادي كا امكان كہاں؟ “ جواب ميں ہم عرض كريں گے كہ ايك ايسے طبقے كي تشكيل كي جائے، جو مكمل طور پر زنجيروں ميں جكڑا ہوا ہو۔ اس انداز فكر كا حامل مكتب ”اصلاحات“ كو مانع قرار ديتا ہے، چونكہ اصلاحات دباؤ ميں كمي پيدا كرتي ہيں اور دباؤ ميں كمي انقلاب كو روكتي ہے يا كم سے كم اس ميں تاخير پيدا كرتي ہے۔ اس مكتب كے برخلاف جو معاشرے كي ذاتي اور فطري حركت كا قائل ہے، يہ مكتب ہرگز كسي طبقہ كے لئے بيڑياں بنوانے كا فتويٰ صادر نہيں كرتا۔ اس لئے كہ وہ دباؤ كو رشد و تكامل كي لازم شرائط نہيں سمجھتا۔ اسي طرح تدريجي اصلاحات اس كي نظر ميں پيش رفت كي مانع نہيں، اسلام ميں شرائط اور موانع بيشتر يا پھر ہميشہ فطرت كے گرد چكر لگاتے ہيں۔ قرآن كبھي اصلي اور قديمي پاكيزگي پر باقي رہنے كو بعنوان شرط پيش كرتا ہے: ”( هدي للمتقين ) “ (سورہ بقرہ، آيت۲) اور كبھي نظام ہستي كے مقابل ذمہ داري اور مسئوليت كے تصور سے پيدا ہونے والے خوف اور دغدغہ كو ”يخشون ربھم بالغيب“ يا ”من خشي الرحمن بالغيب“ كہہ كر عنوان شرط بناتا ہے (سورہ طہٰ، آيت۳) اور كبھي فطرت كے زندہ ہونے اور زندہ رہنے كو بعنوان شرط گنواتا ہے: ”لتنذر من كان حيا “(۶۹)
اسلام دعوت كي قبوليت كي شرط كو پاكيزگي خلقت سے متعلق احساس ذمہ داري اور فطري حيات كے ساتھ جينے كو قرار ديتا ہے۔ اس كے مقابلے پر موانع ميں وہ اخلاقي اور نفسياتي برائيوں، اثم قلب،(۷۰) چشم بصيرت كے نابينا ہوجانے(۷۱) ، بڑے لوگوں كي پيروي(۷۲) كتاب نفس ميں تحريف ہونے(۷۳) باپ دادا كي عادتوں كي پيروي(۷۴) بڑے لوگوں كي پيروي(۷۵) ظن كي پيروي(۷۶) اور ان جيسے امور كا نام ليتا ہے۔ اسراف اور حرص و آذر كو بھي اس اعتبار سے مانع جانتا ہے كہ يہ چيزيں حيواني صفات كو انسان ميں تقويت دے كر اسے وحشي اور درندہ بنا ديتي ہيں۔ يہ تمام امور قرآن كي نظر ميں خير و صلاح اور تكامل كے لئے معاشرے و انقلاب كي راہ ميں ركاوٹ ڈالتے ہيں ۔
اسلامي تعليمات كي رو سے نوجوان، بوڑھوں سے اور فقراء، امراء كي نسبت تسليم كے حوالے سے زيادہ آمادگي ركھتے ہيں۔ اس كي وجہ پہلے گروہ ميں عمر كي كمي ہے، جس كے سبب ان كي فطرت نفساني آلودگيوں سے ابھي دور ہوتي ہے اور دوسرے گروہ ميں مال اور آسائشوں كا فقدان ہوتا ہے ۔
اس طرح كي شرائط اور اس انداز كے موانع اس بات كي تائيد كرتے ہيں كہ قرآن معاشرتي اور تاريخي انقلابات كے ميكانزم كو مادي اور معاشي ہونے سے زيادہ باطني اور روحاني سمجھتا ہے ۔
۴۔ معاشروں كا عروج اور انحطاط
ہر اجتماعي مكتب علي القاعدہ معاشروں كي ترقي اور بلندي نيز ان كے انحطاط و تنزل كے بارے ميں اپنا ايك نظريہ ركھتا ہے۔ رہي يہ بات كہ وہ كن چيزوں كو اس سلسلے ميں ترقي يا پھر انحطاط كا اصلي اور بنيادي عامل سمجھتا ہے، تو اس كا تعلق اس رخ سے ہے كہ جس رخ سے وہ معاشرے، تاريخ، تكاملي تحريكات اور انحطاطي خطوط كو ديكھتا ہے ۔
قرآن ميں بطور خاص قصص و حكايات بيان كرتے ہوئے، اس موضوع پر توجہ دي گئي ہے، اب ہم ديكھتے ہيں كہ قرآن آج كي اصطلاح ميں بنياد كے حق ميں نظريہ پيش كرتا ہے يا عمارت كے حق ميں؟ زيادہ صحيح اور زيادہ بہتر تعبير ميں يوں كہہ ليجئے كہ قرآن كن كن چيزوں كو اساس اور كن كن چيزوں كو اس پر قائم عمارت جانتا ہے؟ وہ اقتصادي اور مادہ مسائل كو بنيادي عامل گردانتا ہے يا اعتقادي اور اخلاقي مسائل كو؟ يا پھر كسي كو افضليت نہيں ديتا اور دونوں اس كي نظر ميں برابر ہيں؟
الف) انصاف اور بے انصافى
قرآن نے بہت سے آيتوں ميں اس كا تذكرہ كيا ہے، ان ميں سورہ قصص كي وہ چوتھي آيت بھي ہے، جس كا پہلے ہم ”استضعاف كي آيت“ ميں ذكر كر چكے ہيں:
( ان فرعون علافي الارض وجعل اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم انه كان من المفسدين )
اس آيہ كريمہ ميں فرعون كي اس برتري كے گھمنڈ كا تذكرہ كرنے كے بعد جس ميں وہ ربوبيت اعليٰ كا دعويدار تھا اور دوسروں كو اپنا زر خريد غلام سمجھتا تھا، ذكر ہوتا ہے كہ وہ مختلف حيلوں بہانوں سے لوگوں ميں تفرقہ ڈال كر ان كے درميان بے جا امتيازات پيدا كر ديتا تھا، اس طرح انہيں ايك دوسرے كے مقابل لا كھڑا كرتا تھا، اپنے ملك كے باشندوں كے ايك خاص گروہ كو ذليل كرنے ميں كوئي كسر اٹھا نہيں ركھتا تھا۔ ان كے لڑكوں كو قتل كروا ديتا تھا اور ان كي لڑكيوں كو اپني اور اپنے حاميوں كي خدمت كے لئے چھوڑ ديا كرتا تھا۔ قرآن اسے ايك مفسد اور تباہ گر كے عنوان سے ياد كرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے كہ ”( انه كان من المفسدين ) “ كا جملہ اس بات كي طرف اشارہ ہے كہ اس طرح كے اجتماعي مظالم معاشرے كو اُلٹ پلٹ كر ركھ ديتے ہيں ۔
ب) اتحاد اور تفرقہ
سورہ آل عمران كي آيت۱۰۳ ميں بڑي وضاحت سے يہ حكم موجود ہے كہ سب اہل ايمان، ايمان كي بنياد پر اللہ كي رسي كو متحد اور متفق ہو كر تھاميں اور تفرقہ پيدا نہ كريں۔ پھر ايك آيت چھوڑ كر ارشاد ہوتا ہے:
”اپنے پچھلوں كي طرح نہ ہوجانا، جنہوں نے اختلاف اور تفرقہ ميں زندگي بسر كي ۔“
سورہ انعام كي آيت۱۵۳ بھي اسي سے ملتي جلتي ہے ۔
سورہ انعام آيت ۴۵ميں ارشاد ہوتا ہے:
( قل هو القادر علي ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعاً و يذيق بعضكم باس بعض) .
”كہہ دو (اے رسول صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم) ! خدا اس بات پر قادر ہے كہ وہ تمہارے اوپر يا پيروں تلے سے عذاب جاري كر دے يا تمہيں تفريق و افتراق كا جامہ پہنائے اور بعض لوگوں كي بد رفتاري كا مزہ بعض دوسرے لوگوں كو چكھائے ۔“
سورہ انفال كي۴۶ ويں آيت ميں ارشاد ہوتا ہے:
( ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم. )
”ايك دوسرے كے ساتھ نہ جھگڑو كہ آپس كے اندروني جھگڑے كمزوري پيدا كرتے ہيں اور يہ كمزوري تمہيں برباد كر دے گي ۔“
ج) امر بالمعروف اور نہي عن المنكر كا اجراء ياانصراف
قرآن نے امر بالمعروف اور نہي عن المنكر كي ضرورت كے بارے ميں جو كچھ كہا ہے، اس ميں سے ايك آيت سے صريحاً يہ استنباط ہوتا ہے كہ اس عظيم فريضہ سے انصراف قوموں كو ہلاكت اور ان كے انہدام ميں موثر ثابت ہوتا ہے، يہ سورہ مائدہ كي(۷۹) ويں آيت ہے، جس ميں وہ بني اسرائيل كے كافروں كي رحمت خدا سے دوري كا ايك سبب يہ بھي ذكر كرتا ہے كہ انہوں نے ايك دوسرے كو منكرات سے نہيں روكا يعني نہي عن المنكر سے بے توجہي برتى:
( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانو يفعلون )
”يہ لوگ ايك دوسرے كو منكرات كے ارتكاب سے نہيں روكتے تھے اور يہ كتنا غلط كام تھا، جو وہ كرتے تھے ۔“
معتبر اسلامي روايات ميں امر بالمعروف اور نہي عن المنكر كے مثبت اور منفي كردار كے بارے ميں بہت كچھ كہا گيا ہے، ان سب كو يہاں نقل كرنا ہمارے بس كي بات نہيں ۔
د) فسق وفجور اور اخلاقي برائياں
اس سلسلے ميں بھي بہت سي آيات ہيں۔ كچھ آيتيں تو وہي ہيں، جو ”ترف“ اور ”مترف“ ہونے كو ہلاكت كا سبب گردانتي ہيں(۷۷) اور بہت سي آيات ہيں جن ميں لفظ ”ظلم“ استعمال ہوا ہے۔ قرآن كي اصطلاح ميں ظلم صرف كسي فرد يا گروہ كا دوسرے فرد يا گروہ كے كسي حق پر جارحيت كا نام نہيں ہے بلكہ كوئي شخص خود اپنے اوپر بھي ظلم كر سكتا ہے، كوئي قوم خود اپنے نفس پر ظالم ہو سكتي ہے، ہر فسق و فجور اور ہر بے راہ روي ظلم ہے۔ قرآن ميں ظلم كا تذكرہ عام مفہوم ميں ہے، جس ميں دوسروں پر ظلم كي بات بھي آجاتي ہے اور فسق و فجور اور غير اخلاقي امور بھي آتے ہيں۔ تاہم زيادہ تر اس كا استعمال دوسرے مفہوم ميں ہوا ہے۔ وہ آيتيں جن ميں ظلم اپنے عام مفہوم ميں قوموں كي ہلاكت كا باعث قرار ديا گيا ہے، بہت زيادہ ہيں اور ہماري مختصر كتاب ان كے بيان سے قاصر ہے ۔
ان تمام معياروں كو سامنے ركھ كر معاشرے اور تاريخ كي بنيادوں كے بارے ميں قرآن كے نقطہ نظر كو سمجھا جاسكتا ہے۔ قرآن بہت سے امور كے بارے ميں جنہيں آج كي اصطلاح ميں عمارت كہا جاتا ہے، كے حتمى، قطعي اور تقدير ساز كردار كا قائل ہے ۔
____________________
۶۴. بعض نام نہاد معاصر روشن فكر مسلمانوں نے قرآن كي اكثر سورتوں پر لكھي ہوئي اپني تفسيروں ميں سرے سے اس بات كا انكار كر ديا ہے كہ قرآن نے معاد كے بارے ميں كہيں ايك آيت بھي نازل كي ہو، جہاں كہيں بھي قرآن ميں ”دنيا“ كا نام آيا ہے، اس سے مراد ”زندگي كا پست ترين نظام“ يعني بے جا امتيازات اور استحصال ہے اور جہاں آخرت كا تذكرہ ہوا ہے، اس سے مراد ”برتر نظام“ ليا گيا ہے، جہاں بے جا امتيازات، استحصال اور ناانصافي كا نام و نشان نہيں اور جہاں اختصاصي مالكيت كي جڑيں كاٹي گئي ہيں، اگر يہي آخرت كا مفہوم ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے كہ قرآن نے مادي مكتب فكر سے ہزار سال پہلے مذہب كي فاتحہ پڑھ دي ۔
۶۵.الكافى، جلد۲، ص۱۴۸.
۶۶.نہج البلاغہ، خطبہ۵۱.
۶۷.بحار الانوار، ج۴۴، ص۳۸۱.
۶۸.اللہوف علي قتلي الطفوف، ص۴۱.
۶۹.سورہ انبياء، آيت۴۹، سورہ فاطر۱۸ اور سورہ يسين۱۱ كي آيات كي طرف رجوع فرمائيں.
۷۰.سورہ يسين،(۷۰)، سورہ بقرہ.
۷۱.سورہ حج،(۴۶).
۷۲.سورہ حم سجدہ، ۴۴.
۷۳.سورہ شمس، ۱۰.
۷۴.سورہ زخرف، ۲۳.
۷۵.سورہ احزاب، ۲۷.
۷۶.انعام، ۱۱۶.
۷۷.ملاحظہ فرمائيں: سورہ ہود آيت۱۱۶، انبياء آيت۱۳ اور سورہ مومنون آيت۳۳اور ۶۴.
تاريخ كا تغير و تبدل
اب تك تاريخ كے دو اہم مسئلوں ميں سے ايك مسئلے پر گفتگو ہوئي ہے، يعني تاريخ كي ماہيت كے بارے ميں بات ہوئي ہے كہ آيا وہ مادي ہے يا غير مادى؟ دوسرا اہم مسئلہ انساني تاريخ كا تحول و تطور ہے ۔
ہم جانتے ہيں كہ انسان تنہا زندگي بسر نہيں كر سكتا، وہ ايك اجتماعى وجود ہے۔ انسان كے علاوہ بھي كچھ ايسے جاندار ہيں، جن كي زندگي كم و بيش اجتماعى ہے اور ايك دوسرے كے ساتھ مل جل كر زندگي بسر كرتے ہيں۔ ان كي زندگي آپس ميں تعاون و ہمكاري اور ذمہ داريوں كي تقسيم كے ذريعے كچھ منظم قواعد و ضوابط اور قوانين كے تحت بسر ہوتي ہے۔ سب جانتے ہيں كہ شہد كي مكھي اسي قسم كي جانداروں ميں سے ہے، ليكن انسان اور اس قسم كے جانداروں كي اجتماعى موجوديت ميں ايك بنيادي فرق پايا جاتا ہے اور وہ يہ كہ ان جانداروں كي اجتماعى زندگي ميں جمود يكسانيت پائي جاتي ہے، ان كے نظام حيات ميں كوئي تبديلي اور كوئي رد و بدل نہيں پايا جاتا، اگر موريس ميٹرلينگ كي تعبير كو صحيح سمجھا جائے تو كہا جائے گا كہ ان كے تمدن ميں كوئي جدت پسندي نہيں ۔
اس كے برخلاف انسان كي اجتماعى زندگي ميں تغير و تبدل رونما ہوتا رہتا ہے، بلكہ يہ زندگي شباب كي حامل ہے، يعني تدريجاً اس كي سرعت ميں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لہٰذا انسان كي اجتماعى زندگي كي تاريخ ادوار ميں بٹي ہوئي ہے اور يہ ادوار مختلف نقطہ ہائے نظر ميں ايك دوسرے سے مختلف ہيں۔ مثلاً لوازم معيشت كے نقطہ نظر سے، صيد و شكار كا دور، كھيتي باڑي كا دور، صنعت كا دور، اقتصادي نظام كے نقطہ نظر سے: دور اشتراكى، دور غلامى، دور جاگيردارى، دور سرمايہ داري اور دور سوشلزم، سياسى نظام كے نقطہ نظر سے طوائف الملوكي كا دور، استبدادي دور، اريسٹو كريسي كا دور اور ڈيموكريسي كا دور، جنس كے نقطہ نظر سے عورت كي حاكميت كا دور، مرد كي حاكميت كا دور وغيرہ ۔
يہ تغير اور يہ انقلابي تبديلي باقي تمام اجتماعى جانوروں كي زندگي ميں كيوں نہيں پائي جاتى؟ اس تبديلي كا بنيادي عامل اور اس كا راز كيا ہے جس كے سبب انسان ايك معاشرتي دور سے دوسرے معاشرتي دور ميں جاتا ہے؟ بعبارت ديگر انسان كو آگے بڑھانے اور ترقي كي منزلوں پر گامزن كرنے والي وہ كون سي چيز ہے، جو حيوان ميں نہيں؟اور يہ ترقي اور پيشرفت كس صورت سے، كن قوانين كے تحت اور مروجہ اصطلاح ميں كس انداز كے ميكانزم سے رونما ہوتي ہے؟
البتہ يہاں تاريخ كے فلسفىوں كي طرف سے عام طور پر ايك سوال پيش ہوتا ہے اور وہ يہ كہ كيا پيش رفت اور تكامل كي واقعي كوئي حقيقت ہے؟ يعني كيا واقعي انسان كي معاشرتي زندگي ميں واقع ہونے والي تبديليوں كا تاريخي سلسلہ اپني غرض و غايت ميں پيش رفت اور تكامل كو لئے ہوئے ہے؟ تكامل كا معيار كيا ہے؟
بعض افراد ان تبديليوں كو پيش رفت اور تكامل نہيں سمجھتے اور اس كا تذكرہ انہوں نے اپني متعلقہ كتاب ميں بھي كيا ہے۔(۷۸)
بعض تاريخ كے سفر اور اس كي حركت كو ايك ضروري حركت سمجھتے ہيں، ان كا كہنا ہے كہ تاريخ ايك نقطے سے حركت كرتي ہے اور اپنے مخصوص مراحل كو طے كرنے كے بعد پھر، واپس اسي نقطے پر آجاتي ہے، جہاں سے وہ چلي تھى، يہي تاريخ كي ريت ہے كہ وہ اپنے آپ كو دہراتي ہے۔ مثلاً ايك تشدد پسندانہ قبائلي نظام شجاع اور صاحب ارادہ صحرائي لوگوں كے ذريعے وجود ميں آتا ہے۔ يہ حكومت اپني طبيعت كي بناء پر استكباريت اور ارسٹوكريسي ميں بدل جاتي ہے۔ استكباري حكومت ميں آمريت ايك عمومي انقلاب كو جنم ديتي ہے اور جمہوري نظام حكومت قائم ہوتا ہے ۔
جمہوري نظام ميں بے ضابطگى، بے سرپرستي اور آزادي ميں افراط ايك بار پھر قبائلي احساسات كے ساتھ ايك تشدد پسند استبدادي حكومت كے برسركار آنے كا سبب بنتا ہے ۔
ہم في الحال اس بحث ميں جانا نہيں چاہتے اور اسے كسي اور وقت كے لئے اٹھا ركھتے ہيں، ”اصل موضوع“ كي صورت كے بارے ميں اسي پر بنا ركھيں گے كہ مجموعي طور پر حركت اور سير تاريخ ميں پيش رفت ہے، البتہ يہ بتانا ضروري ہے كہ وہ تمام افراد جو تاريخ كے بارے ميں پيش رفت كے قائل ہيں، اس بات كا اعتراف كرتے ہيں كہ ايسا نہيں ہے كہ تمام معاشرے اپنے تمام حالات ميں اپنے ماضي سے بہتر ہوتے ہيں اور معاشرے ہميشہ بغير كسي وقفے كے ترقي كي طرف بڑھتے رہتے ہيں اور ان ميں انحطاط نہيں ہوتا۔
بلاشبہ معاشروں ميں توقف، انحطاط، پستى، دائيں يا بائيں جانب جھكاؤ اور بالآخر سقوط و زوال كا عمل ہوتا ہے، ليكن ہماري مراد يہ ہے كہ انساني معاشرے مجموعي طور پر بلندي كي راہوں كو طے كرتے ہيں۔
فلسفہ تاريخ كي كتابوں ميں اس مسئلہ كو كہ محرك تاريخ كيا ہے؟ اور وہ كون سي چيز ہے، جو تاريخ كو آگے بڑھاتي اور اجتماعى تبديلي كا باعث بنتي ہے؟ عام طور پر اس طرح پيش كيا گيا ہے كہ كس قدر غور و خوض كے بعد اس كي نادرستي سامنے آتي ہے، عام طور پر اس مسئلے كے بارے ميں جو نظريات پيش ہوئے ہيں، وہ يہ ہيں:
۱۔ نسلي نظريہ
اس نظريہ كے مطابق بعض نسليں تاريخ كو آگے بڑھانے ميں بنيادي كردار كي حامل ہيں، بعض نسلوں ميں تمدن آفريني اور ثقافت آفريني كي صلاحيت ہوتي ہے اور بعض ميں نہيں ہوتى، بعض سائنس، فلسفہ، صفت، اخلاق اور فن وغيرہ كو جنم دينے كي صلاحيت ركھتي ہيں اور بعض فقط استعمال كرنے والي ہيں، تخليق كرنے والي نہيں۔ اس سے يہ نتيجہ حاصل ہوتا ہے كہ نسلوں ميں تقسيم كار كي ايك صورت ہوني چاہيے، وہ نسليں جو سياست، تعليم و تربيت، ثقافت، ہنر، فن اور صنعت ميں صاحب استعداد ہيں، انہيں چاہيے كہ وہ اسي طرح كے اعليٰ اور ظريف انساني امور كے ذمہ دار ہوں اور جن نسلوں ميں اس طرح كي صلاحيت موجود نہيں انہيں اس طرح كے كاموں سے باز ركھ كر ان كے ذمہ محنت اور مشقت والے جانوروں جيسے جسماني كام لگائے جانے چاہئيں، جن ميں فكر، ذوق اور نظريے كي ظرافت ضروري نہيں ہوتي۔ ارسطو كا نسلوں كے اختلاف كے بارے ميں يہي نظريہ تھا، اسي لئے وہ بعض نسلوں كو غلام بنانے اور بعض كو غلام بننے كا مستحق سمجھتا تھا۔
بعض لوگوں كا عقيدہ ہے كہ تاريخ كو آگے بڑھانے كا عمل خاص نسلوں سے انجام پاتا ہے، مثلاً جنوبي نسل پر شمالي نسل كو برتري حاصل ہے، يہ نسل اور نژزاد ہي تھى، جس نے تمدنوں كو آگے بڑھايا ہے، فرانس كا مشہور فلسفى كانٹ گوبينو جو آج سے تقريباً ايك صدي پہلے تين سال تك ايران ميں فرانس كے نائب سفير كي حيثيت سے رہا تھا، اسي نظريے كا حامي تھا۔
۲۔ جغرافيائي نظريہ
اس نظريے كے مطابق طبيعي ماحول نے تمدن، ثقافت اور صنعت كو ايجاد كيا ہے، معتدل علاقوں ميں معتدل مزاج اور طاقت ور ذہن وجود ميں آتے ہيں۔ بو علي سينا نے كتاب قانون كي ابتداء ميں انسانوں كي احساسى، ذوقى اور فكرى شخصيت پر طبيعي ماحول كي تاثير كے بارے ميں بہت كچھ كہا ہے ۔
اس نظريے كي بنياد پر وہ چيز جو انسانوں كو تاريخ كي پيش رفت كے سلسلے ميں آمادہ كرتي ہے وہ نسل اور خون يعني عامل وراثت نہيں كہ ايك خاص نسل جس ماحول اور جس علاقے ميں بھي ہو تاريخ كو آگے بڑھانے والي ہو اور دوسري نسل اس كے برخلاف جس ماحول ميں ہو، اس طرح كي صلاحيت سے عاري ہو، بلكہ نسلوں كا اختلاف ماحول كے اختلاف كا نتيجہ ہے، نسلوں كي جگہ كي تبديلي سے ان كي صلاحيتيں بھي تبديل ہوجاتي ہيں۔ پس درحقيقت يہ خاص زمينيں اور خاص علاقے ہي ميں جو آگے بڑھانے والے اور جدت طراز ہوتے ہيں۔ سترھويں صدي كے فرانسيسي ماہر عمرانيات مانٹيسكو مشہور كتاب ”روح القوانين“ ميں اس نظريے كي حمايت كرتے ہيں ۔
۳۔ بلند پايہ شخصيتوں سے متعلق نظريہ
اس نظريے كے مطابق تاريخ كو يعني تاريخي تبديليوں كو وہ سائنسي ہوں يا سياسى، فنى ہوں يا اخلاقى، اقتصادي ہوں يا كچھ اور، نابغہ افراد وجود ميں لاتے ہيں، انسانوں اور دوسرے جانداروں كے درميان فرق اس بات كا ہے كہ دوسرے جاندار علم حياتيات كي رو سے يعني طبيعي استعداد كي رو سے ايك درجہ ميں ہيں، ان انواع كے درميان كسي قسم كا كوئي فرق (كم از كم قابل اعتنا فرق) ديكھنے ميں نہيں آتا۔
اس كے برعكس انسانوں ميں استعداد كي يكسانيت نہيں اور ان ميں زمين سے آسمان تك كا فرق پايا جاتا ہے۔ نابغہ لوگ ہر معاشرے كے استثنائي افراد ہوتے ہيں۔ استثنائي افراد ہي عقل يا ذوق يا ارادے اور تخليقي صلاحيت كے اعتبار سے غير معمولي طاقت كے حامل ہوتے ہيں۔ ايسے افراد جس معاشرے ميں نمودار ہوتے ہيں، اسے علمى، فنى، اخلاقى، سياسى اور فوجي اعتبار سے بلندي عطا كرتے ہيں۔ اس نظريے كے اعتبار سے لوگوں كي اكثريت تقليدي ہوتي ہے، جو تخليقي صلاحيت سے عاري اور دوسروں كے افكار اور صنعتوں سے استفادہ كرنے والي ہوتي ہے ۔
ليكن ہميشہ كم و بيش ہر معاشرے ميں موجد، مخترع، پيش رو، خالق افكار اورخالق صنعت افراد كا ايك مختصر سا گروہ موجود ہوتا ہے، يہي وہ لوگ ہيں، جو تاريخ كو آگے بڑھا كر نئے مرحلے ميں داخل كرتے ہيں ۔
مشہور انگريزي فلسفى كارلائل جس نے مشہور كتاب ”بلند پايہ ہستياں“ (الابطال) لكھي اور جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم سے اس كا آغاز كيا، اسي نظريے كا قائل ہے۔ كار لائل كے نظريے كے مطابق ہر قوم ميں ايك يا كئي شخصيتيں اس قوم كي پوري تاريخ كي غمازي كرتي ہيں اور زيادہ بہتر عبارت ميں ہر قوم كي تاريخ ايك يا كئي مايہ ناز ہستيوں كي شخصيت اور ذہانت كي تجلي گاہ ہوتي ہے، مثلاً تاريخ اسلام جناب رسالت مآب صلي اللہ عليہ وآلہ وسلم كي شخصيت كي تجلي گاہ ہے، فرانس كي جديد تاريخ نپولين اور چند ديگر افراد كي اور روس كي حاليہ ساٹھ سالہ تاريخ لينن كي تجلي گاہ ہے۔
۴۔ اقتصادي نظريے
اس نظريے كے مطابق تاريخ كا محرك اقتصاد ہے، ہر قوم كا تاريخي اور اجتماعى پہلو جو ثقافتي جہت سے ہو چاہے مذہبي و سياسى جہت سے، فوجي ہو يا پھر اجتماعى، اس معاشرے كے پيداواري طريقہ كار اور پيداواري روابط كي عكاسي كرتا ہے۔ معاشرے يا قوم كي اقتصادي بنياد ميں تبديلي دراصل اس قوم يا اس معاشرے كو حركت ديتي ہے اور اسے آگے لے جاتي ہے۔ يہ مايہ ناز لوگ جن كا تذكرہ اس سے قبل كے نظريہ ميں ہو چكا ہے، معاشرے كي اجتماعى، سياسى اور اقتصادي ضرورتوں كے مظاہر كے علاوہ كچھ نہيں ہيں۔ يہ ضروريںپيداواري آلات ميں تبديلي كے باعث پيدا ہوتي ہيں۔ كارل ماركس بلكہ مجموعي طور پر تمام كاركسٹ اور كہيں كہيں غير ماركسٹ بھي اس نظريے كے حامي ہيں۔ ميرے خيال ميں دور حاضر كا يہ سب سے مقبول نظريہ ہے ۔
۵۔ الٰہي نظريہ
اس نظريے كے مطابق جو كچھ بھي زمين پر رونما ہوتا ہے، ايك آسماني امر ہے، جو حكمت بالغہ كے مطابق عمل ميں آتا ہے۔ تاريخ كے تحولات و تغيرات اللہ كي حكمت بالغہ اور اس كي حكيمانہ مشيت كي جلوہ گاہ ہيں ۔
پس جو چيز تاريخ كو آگے بڑھاتي ہے اور اس ميں تبديلي لاتي ہے، وہ ارادہ الٰہي ہے۔ تاريخ اللہ كے مقدس ارادے كا پلے گراؤنڈ ہے۔ مشہور پادري اور مورخ ”بوسوئہ“ جو ”لوئي پانزوہم“ كامعلم بھي تھا، اس نظريے كا حامي ہے ۔
يہ وہ نظريات ہيں، جنہيں عام طور پر فلسفہ تاريخ كي كتابوں نے حركت تاريخ كے عوامل كے عنوان سے پيش كيا ہے ۔
ہمارے خيال ميں يہ گفتگو كس طرح بھي درست نہيں، اس ميں ايك طرح كا ”خلط مبحث“ ہوا ہے۔ ان ميں سے بيش تر نظريات تاريخ كي اس علت محرك سے تعلق نہيں ركھتے، جس كي تلاش ميں ہم سرگرداں ہيں۔ مثلاً نسل سے متعلق نظريہ ايك عمرانياتي نظريہ ہے اور اس پر اس رخ سے بحث ہو سكتي ہے كہ كيا انساني نسليں موروثي عوامل كے اعتبار سے ايك انداز كي صلاحيت ركھتي ہيں اور ہم سطح ہيں كہ نہيں، اگر ہم سطح ہيں تو پھر تمام نسليں ايك ہي انداز سے تاريخ كي حركت ميں شريك ہيں يا كم ازكم شريك ہوسكتي ہيں اور اگر ہم سطح نہيں ہيں، تو پھر كچھ ہي نسليں تاريخ كو آگے بڑھانے ميں حصہ دار ہيں يا ہو سكتي ہيں۔ اس اعتبار سے يہ مسئلہ صحيح ہے، ليكن فلسفہ تاريخ كا راز پھر بھي مجہول رہ جاتا ہے۔ بالفرض ہم يہ مان ليں كہ صرف ايك ہي نسل كے ہاتھوں تاريخي تحول و تغير ہوتا ہے، تو پھر بھي مشكل كے حل ہونے كے لحاظ سے كوئي فرق نہيں پڑتا اور مشكل جوں كي توں رہتي ہے جبكہ ہم اس كے بھي قائل ہوجاتے ہيں كہ تاريخ كے تحول و تغير ميں تمام انسانوں كا عمل دخل ہے كيونكہ يہ معلوم نہيں ہوتا كہ آخر كس بناء پر انسان يا انسان كي كسي نسل كي زندگي تبديل ہوتي رہتي ہے اور حيوان كي زندگي ميں ہر تغير و تحول نہيں ہے۔ وہ راز كہاں چھپا ہوا ہے؟ يہ بات تحرك تاريخ كے راز سے پردہ نہيں اٹھاتي كہ تاريخ كو ايك نسل نے انقلاب سے ہمكنار كيا يا تمام نسلوں نے؟
اسي طرح جغرافيائي نظريہ بھي اپني جگہ عمرانياتي علوم كے ايك سفيد مسئلے سے مربوط ہے اور وہ يہ كہ يہ ماحول انسان كي عقلى، فكرى، ذوقى اور جسماني ترقي ميں موثر ہے۔ كوئي ماحول انسان كو حيوان كي حد ميں يا اس كے قريب ركھتا ہے، ليكن كوئي اور ماحول حيوان سے انسان كے فاصلے كو زيادہ ركھتا ہے۔ اس نظريے كے مطابق تاريخ صرف بعض ممالك اور بعض مناطق ميں تحرك ركھتي ہے اور دوسرے مناطق اور دوسرے ماحول ميں ثابت، يكساں اور حيوانات كي سرگزشت كي طرح رہي ہے، ليكن اصلي سوال اپني جگہ باقي ہے كہ مثلاً شہد كي مكھي يا باقي تمام اجتماعى زندگي بسر كرنے والے جاندار نيز انہي مناطق اور انہي ممالك ميں فاقد تحرك تاريخ ہيں۔ پس وہ اصلي عامل جو دو قسم كے ان جانداروں ميں اختلاف كا اصلي سبب بنتا ہے اور ان ميں سے ايك ثابت اور دوسرا ہميشہ ايك مرحلے سے دوسرے ميں منتقل ہوتا رہتا ہے، كيا ہے؟ان سب سے زيادہ بے ربط، الٰہي نظريہ ہے، مگر كيا صرف تاريخ ہي وہ واحد چيز ہے، جو جلوہ گاہ مشيت الٰہي ہے؟ تمام دنيا آغاز سے انجام تك اپنے تمام اسباب، علل، موجبات اور موانع كے ساتھ جلوہ گاہ مشيت ايزدي ہے۔ مشيت الٰہي دنيا كے تمام اسباب و علل كے ساتھ مساوي رشتے كي حامل ہے، جس طرح انسان كي انقلابات بھري زندگي جلوہ گاہ مشيت الٰہي ہے، اسي طرح شہد كي مكھي كي ثابت اور يكساں زندگي بھي جلوہ گاہ مشيت الٰہي ہے۔ پس گفتگو اس امر ميں ہے كہ مشيت الٰہي نے انسان كي زندگي كو كس نظام كے ساتھ خلق كيا ہے؟
انسان ميں كيا راز ركھ ديا ہے كہ اس كي زندگي متحول و متغير ہے جبكہ ديگر جانداروں كي زندگي اس راز سے خالي ہے۔
تاريخ كا اقتصادي نظريہ بھي فنى اور اصولي پہلو سے خالي ہے، يعني اصولي صورت ميں اسے پيش نہيں كيا گيا، تاريخ كے اقتصادي نظريہ كو جس صورت ميں پيش كيا گيا ہے، اس سے فقط تاريخ كي ماہيت اور ہويت واضح ہوتي ہے كہ وہ مادي اور معاشي ہے اور باقي تمام پہلو اس تاريخي جوہر كے عوارض كي حيثيت ركھتے ہيں، يہ نظريہ واضح كرتا ہے كہ اگر معاشرے كي اقتصادي بنياد ميں تبديلي رونما ہو تو لازمي طور پر معاشرے كے باقي تمام امور تبديلي سے دوچار ہوں گے، ليكن يہ سب باتيں ”اگر“ ہيں، اصلي بات پھر بھي اپني جگہ رہ جاتي ہے اور وہ يہ كہ ہم يہ فرض كرتے ہيں كہ اقتصاد معاشرے كي اصل بنياد ہے اور ”اگر“ اس اصل بنياد ميں تبديلي رونما ہو، تو تمام معاشرہ بدل جائے گا ليكن كيوں اور كس عامل كي كن عوامل كے تحت بنياد ميں تبديلي آئے گى؟ اور اس سے بنياد پر قائم عمارت متغير ہوگي ۔ بعبارت ديگر اقتصاد كا بنياد ہونا اس كے متحرك ہونے اور حركت ركھنے كے لئے كافي نہيں ہے ۔
ہاں، اگر اس نظريے كے حامل افراد اس عقيدے كے بجائے اقتصاد كو جو (بقول ان كے) معاشروں كي اصل بنياد اور اس پر قائم عمارت كے مسئلے كو پيش كريں اور كہيں كہ عامل محرك تاريخ اصل بنياد كي دوسمتوں (پيداواري آلات اور پيداواري روابط) كا تضاد ہے، تو پھر مسئلہ صحيح صورت ميں پيش ہوتا ہے، اس ميں كوئي شك نہيں كہ ”اقتصاد محرك تاريخ ہے“ كے مسئلے كو پيش كرنے والے كا اصلي مقصد يہي ہے كہ تمام تحريكات كا اصلي سبب اندروني تضادات ہيں اور پيداواري آلات اور پيداواري روابط كے درميان داخلي تضاد محرك تاريخ ہے، ليكن ہماري گفتگو پيش كرنے والے كي مراد ما في الضمير سے متعلق نہيں بلكہ صحيح طور پر پيش كرنے سے متعلق ہے ۔
نابغہ شخصيتوں سے متعلق نظريہ درست ہو يا نادرست براہ راست فلسفہ تاريخ سے يعني عامل محرك تاريخ سے مربوط ہے۔ تاہم تاريخ كو حركت ميں لانے والي طاقت كے بارے ميں يہاں تك ہميں دو نظريے حاصل ہوئے، ايك نابغہ شخصيتوں سے متعلق نظريہ جو تاريخ كومخلوق افراد جانتا ہے اور يہ نظريہ درحقيقت اس بات كا مدعي ہے كہ معاشرے كي اكثريت خلاقيت اور ترقي كي صلاحيتوں سے عاري ہے اور اگر پورا معاشرہ ايسا ہو، تو انقلاب اور پيش رفت كا سوال ہي باقي نہيں رہتا، ليكن معاشرے ميں خداداد صلاحيتوں كي مالك ايك اقليت ہوتي ہے، جو تخليق كرتي ہے، منصوبے بناتي ہے، عزم اور ہمت سے كام ليتي ہے، سخت جدوجہد كرتي ہے، عام لوگوں كو اپنے پيچھے ساتھ لاتي ہے اور اس طرح تبديلياں واقع ہوتي ہيں۔ يہ بلند پايہ لوگ صرف طبيعي اور موروثي استثنائي واقعات كا معلول ہوتے ہيں۔اجتماعي حالات اور معاشرے كي مادي ضرورتيں ان كي تخليق ميں كوئي كردار ادا نہيں كرتيں ۔
دوسرا معاشرے كي اصل بنياد اور اس پر قائم عمارت ميں تضاد كا نظريہ ہي ہے، جو محركيت اقتصاد كي ايك صحيح تعبير ہے اور جس كے بارے ميں ہم پہلے اشارہ كر چكے ہيں ۔
تيسرا نظريہ فطرت
انسان كے كچھ خصائص ہيں، جن كي وجہ سے وہ ايك كمال پذير اجتماعى زندگي ركھتا ہے۔ ان ميں سے ايك خصوصيت اور ايك صلاحيت تجربات حاصل كرنا اور ان كي حفاظت كرنا ہے۔وہ جو كچھ اپنے تجربات سے حاصل كرتا ہے، اسے محفوظ كرتا ہے اور آئندہ تجربات كي بنياد بناتا ہے ۔
اس كي دوسري صلاحيت يا دوسري استعداد قلم اور بيان سے علم كا حصو ل ہے۔ وہ دوسرے كے تجربات اور اكتسابات كو زبان اور اسے زيادہ بہتر مرحلے ميں تحرير سے اپنے آپ ميں منتقل كرتا ہے، نسلوں كے تجربات، مكالمات اور تحريروں كے ذريعے دوسري نسلوں تك پہنچتے اور جمع ہوتے رہتے ہيں، يہي وجہ ہے كہ قرآن نے نعمت بيان، نعمت قلم اور لكھنے كو بڑي اہميت دي ہے۔
( الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ) . (سورہ رحمن، آيات۔۱ تا۴)
”انتہائي مہربان خدا نے قرآن كي تعليم دى، انسان كو خلق كيا اور اسے بيان كرنا سكھايا ۔“
( اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق اقراء و ربك الاكرم الذي علم بالقلم. ) (سورہ علق، آيات،(۱) تا ۴)
”پڑھو اپنے رب كے نام سے جس نے پيدا كيا، جمے ہوئے خون سے انسان كو خلق كيا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار ہي سب سے زيادہ كريم ہے، جس نے قلم كے ذريعے تعليم دي ۔“
انسان كي تيسري خصوصيت اس كي عقل و خلاقيت ہے۔ انسان اپني اس مرموز قوت سے تخليق و اختراع كرتا ہے، وہ مظہر خلاقيت الٰہي ہے۔ اس كي چوتھي خصوصيت جدت پسندي كي سمت اس كا فطري اور ذاتي لگاؤ ہے، يعني انسان ميں خلاقيت اور اختراع، صرف استعداد كي صورت ميں نہيں ہے كہ وہ چاہے اور ضرورت محسوس كرے، تو تخليق و ايجاد پر توجہ دے بلكہ خلاقيت اور نئي چيز كي ايجاد كا رجحان اس ميں بالذات ركھ ديا گيا ہے ۔
تجربوں كا تحفظ اور ان كي نگہداشت علاوہ از ايں ايك دوسرے كو تجربات منتقل كرنے كي صلاحيت نيز تخليق و ايجادات اور ان كي طرف انسان كا ذاتي لگاؤ، وہ طاقتيں ہيں، جو اسے ہميشہ آگے كي سمت بڑھاتي رہي ہيں۔ حيوانات ميں نہ تو تجربوں كے تحفظ كي صلاحيت ہے اور نہ ہي وہ اپنے اكتسابات يا ادراكات كو ايك دوسرے تك پہنچا سكتے ہيں۔(۷۹)
نہ ان ميں تخليق و ابتكار كي صلاحيت ہے جو قوہ عقليہ كي خاصيت ہے اور نہ جدت پسندي كا شديد رجحان ہے، يہي وجہ ہے كہ حيوان جہاں تھا وہيں رہتا ہے اور انسان آگے نكل جاتا ہے۔ اب ہم ان نظريات كو تنقيدي نگاہ سے ديكھنا چاہيں گے۔
تاريخ ميں شخصيت كا كردار
بعض لوگوں كا دعويٰ ہے كہ ”تاريخ نابغہ اور عام حد كے درميان جنگ سے عبارت ہے، يعني ہميشہ عام اور متوسط آدمي اس حالت كے حامي ہوتے ہيں، جس سے ان كو انسيت ہوتي ہے اور نابغہ يا اعليٰ صلاحيتوں كے مالك افراد موجود حالت كو بہتر ميں بدلنے كے خواہاں ہوتے ہيں ۔“
كارلائل كہتا ہے كہ تاريخ اعليٰ صلاحيتوں كے مالك اور ممتاز افراد سے شروع ہوتي ہے۔ يہ نظريہ دراصل دو مفروضوں پر مبني ہے۔
ايك يہ كہ معاشرہ طبيعت اور حيثيت سے عاري ہے۔ افراد سے معاشرے كي تركيب حقيقي تركيب نہيں ہے۔ افراد سب ايك دوسرے سے الگ ہيں۔ ايك دوسرے سے تاثير و تاثر حاصل كرنے سے ايك ايسا حقيقي مركب اور ايك ايسي اجتماعى روح وجود ميں نہيں آسكتى، جو اپني كوئي حيثيت، طبيعت اور خصوصي قوانين ركھتي ہو، پس افراد ہيں اور ان كي انفرادي نفسيات اور بس۔ كسي معاشرے ميں افراد كا ايك دوسرے سے جداگانہ بنيادوں پر رابطہ بالكل جنگل كے درختوں كا سا رابطہ ہے، معاشرتي واقعات انفرادي اور جزوي واقعات كا مجموعہ ہوتے ہيں، اس كے علاوہ كچھ نہيں۔ اس اعتبار سے معاشرے ميں رونما ہونے والے ”اتفاقات“ اور ”واقعات“ زيادہ تر جزوي اسباب كے حامل ہوتے ہيں، كلي اور عمومي اسباب كے نہيں ۔
دوسرا مفروضہ يہ ہے كہ انسان مختلف اور متفاوت صورتوں ميں پيدا ہوئے ہيں اور باوجود اس كے كہ وہ عام طورپر ثقافتي وجود اور باصلاح فلاسفہ حيوان ناطق ہيں، پھر بھي زيادہ تر انسان خلاقيت، نو آوري اور تخليق سے عاري ہوتے ہيں۔ ان كي اكثريت ثقافت اور تمدن كو برتنے والي ہوتي ہے، پيدا كرنے والي نہيں۔ حيوانات كے ساتھ ان كا فرق يہ ہے كہ حيوانات برتنے والے بھي نہيں بن سكتے ۔ اس اكثريت كا مزاج تقليدى، روايتي اور شخصيت پرستي پر مبني ہوتا ہے ۔
انسانوں كي بہت كم تعداد بلند پايہ ، نابغہ، عام اور متوسط حد سے بالاتر مستقل الفكر، مخترع، موجد اور مضبوط ارادے كي مالك ہوتي ہے، يہ لوگ معاشرے كي اكثريت سے جدا ہوتے ہيں، گويا يہ”كسي اور آداب اور آب و خاك اور كسي اور شہر و دريا كے لوگ ہيں۔“ اگر اس طرح كے سائنسى، فلسفى، ذوقى، سياسى، اجتماعى، اخلاقى، ہنري اور فنى ماہرين كا وجود نہ ہو، تو انسانيت اسي منزل پر رہتي جہاں پر پہلے تھي اور اس سے ايك قدم بھي آگے نہ بڑھتي ۔
ہماري نظرميں يہ دونوں مفروضے مہمل ہيں، پہلا مفروضہ اس اعتبار سے بے معني ہے كہ ہم ”معاشرے“ كي بحث ميں پہلے يہ ثابت كر چكے ہيں كہ معاشرے كي اپني ايك حيثيت، طبيعت، قانون اور روايت ہے اور وہ انہي كلي روايات پر قائم ہے اور يہ روايات خود اپني ذات ميں اسے آگے بڑھانے اور تكامل بخشنے والي ہيں۔ پس اس مفروضے كو الگ كر كے ہميں يہ ديكھنا ہوگا كہ باوجود اس كے كہ معاشرہ حيثيت، طبيعت اور روايت سے ہمكنار ہے اور اپني روش كے مطابق اپنا عمل جاري ركھتا ہے۔ فرد كي شخصيت اس ميں كوئي كردار ادا كر سكتي ہے يا نہيں؟ اس موضوع پر ہم پھر كبھي گفتگو كريں گے، اب ہم دوسرے مفروضے كي طرف آتے ہيں۔ اس ميں كوئي شك نہيں كہ انسان كو مختلف صلاحيتوں كے ساتھ خلق كيا گيا ہے، ليكن يہ بات بھي درست نہيں كہ صرف بلند پايہ اور نابغہ لوگ ہي تخليقي صلاحيت كے حامل ہوتے ہيں اور تقريباً باقي تمام لوگ تہذيب و تمدن كے محض صارفين ہوتے ہيں۔ دنيا كے تمام افراد ميں كم و بيش خلاقيت اور نو آوري كي صلاحيت پائي جاتي ہے اور اسي لئے اگر تمام افراد نہيں، تو كم از كم ان كي اكثريت تخليق، توليدي اور نو آوري ميں حصہ لے سكتي ہے، اب يہ اور بات ہے كہ ان كي كوششيں نابغہ افراد كے مقابل ميں بہت كم اور ناچيز ہوں ۔
”تاريخ كو نابغہ شخصيتيں بناتي ہيں“ والے نظريہ كے بالكل برعكس ايك اور نظريہ ہے، جو يہ كہتا ہے كہ تاريخ شخصيتوں كو وجود ميں لاتي ہے، شخصيتيں تاريخ كو نہيں۔ يعني عيني اجتماعى ضرورتيں ہيں، جو شخصيتوں كو پيدا كرتي ہيں ۔
مونٹيسكو كہتا ہے: ”بڑي شخصيتيں اور عظيم واقعات زيادہ وسيع اور زيادہ طويل واقعات كے نتائج اور ان كي نشانياں ہيں ۔“
ہيگل كہتا ہے: ”عظيم ہستياں تاريخ كي خالق نہيں دايہ ہوتي ہيں۔ عظيم لوگ ”عامل“ نہيں ”علامت“ ہوتے ہيں۔ بعض لوگ جو ”ڈوركم“ كي طرح ”اصالۃ الجمعي“ كے قائل ہيں اور اس بات پر اعتقاد ركھتے ہيں كہ تمام افراد بطور مطلق اپني كوئي شخصيت نہيں ركھتے بلكہ وہ اپني تمام شخصيت كو معاشرے سے ليتے ہيں۔ افراد اور شخصيتيں سوائے اجتماعى روح كے مظہر يا بقول محمود شبستري سوائے اجتماعى روح كے روشن دان كي جاليوں كے كچھ بھي نہيں ۔“
وہ لوگ جو ماركس كي طرح علاوہ بر ايں كہ انسان كي عمرانيات پر مبني علوم كو اس كے اجتماعى كاموں سے قرار ديتے ہيں، اسے اجتماعى شعور پر مقدم بھي جانتے ہيں، يعني افراد كے شعور كو اجتماعى و مادي ضرورتوں كے مظاہر ميں سے شمار كرتے ہيں، ان كي نظر ميں شخصيتيں، معاشرے كي مادي اور اقتصادي ضرورتوں كے مظاہر ہيں۔ مادي ضرورتيں ۔۔۔ (انتہائي افسوس ہے كہ استاد مطہري شہيد رحمۃ اللہ عليہ كا مسودہ يہيں پر آكر ختم ہوجاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے كہ ابھي وہ اس كے بارے ميں اور بھي كچھ لكھنا چاہتے تھے، ليكن وقت نے انہيں مہلت نہ دي ۔)
____________________
۷۸.ملاحظہ فرمائى: ”تاريخ كيا ہے؟ “، ترجمہ فارسى: حسن كامشاد، اسي طرح ويل ڈيورنٹ كي تاليف ”تاريخ كے دروس“ اور ”لذات فلسفہ“ ، ص۲، ۳۱۲.
۷۹. بعض حيوانات ميں سائنسي تجربات كي بنياد پر نہيں بلكہ روز مرہ كے واقعات كي سطح پر ادراك كي منتقلي پائي جاتي ہے، جيسا كہ چيونٹي كے بارے ميں كہا جاتا ہے اور قرآن ميں ارشاد ملتا ہے: ”قالت نملة يا يها النمل ادخلوا امساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون “ .سورہ نمل:۱۸.
فہرست
پيش لفظ ۴
معاشرہ كيا ہے؟ ۶
كيا انسان مدني الطبع ہے؟ ۷
كيا معاشرے كا وجود اصيل اور عيني ہے؟ ۹
معاشرہ اور اس كے قوانين و سنن ۱۶
جبر يا اختيار؟ ۱۹
معاشرتي تقسيم اور طبقہ بندى ۲۲
معاشروں كي يگانگت يا ان كا تنوع بہ اعتبار ماہيت ۲۵
معاشروں كا مستقبل ۲۸
تاريخ كيا ہے؟ ۳۵
سائنسي تاريخ ۴۰
۱۔ نقلي تاريخ كا معتبر يا بے اعتبار ہونا ۴۱
۲۔ تاريخ ميں قانون علت و معلول ۴۲
۳۔ كيا تاريخ كي فطرت مادي ہے؟ ۴۶
ماديت تاريخ كے نظريہ كي بنياد ۴۸
۱۔ روح پر مادہ كا تقدم ۴۸
۲۔ معنوي ضرورتوں پر مادي ضرورتوں كا تقدم ۵۰
۳۔ فكر پر كام كے تقدم كا اصول ۵۱
۴۔ انسان كے انفرادي وجود پر اس كے اجتماعى وجود كا تقدم ۵۳
۵۔ معاشرے كے معنوي پہلوؤں پر مادي پہلوؤں كا تقدم ۵۶
نتائج ۶۳
انتقادات ۷۶
۱۔ بے دليل ہونا ۷۸
۲۔ بانيان مكتب كي تجديد نظر ۷۸
۳۔ بنياد اور عمارت كے جبري تطابق كا بطلان ۸۴
۴۔ آئيڈيالوجى كي اپنے دور سے عدم مطابقت ۸۶
۵۔ ثقافتي ترقي كا استقلال ۸۶
۶۔ تاريخي ميٹريالزم خود اپني تنسيخ كرتا ہے ۸۸
اسلام اور تاريخي ماديت ۹۳
اعتراض ۱۰۱
معيار اور پيمانے ۱۲۲
۱۔ دعوت سے متعلق حكمت عملى ۱۲۲
۲۔ عنوان مكتب ۱۲۸
۳۔ شرائط و موانع قبوليت ۱۲۹
۴۔ معاشروں كا عروج اور انحطاط ۱۳۱
الف) انصاف اور بے انصافى ۱۳۱
ب) اتحاد اور تفرقہ ۱۳۱
ج) امر بالمعروف اور نہي عن المنكر كا اجراء ياانصراف ۱۳۲
د) فسق وفجور اور اخلاقي برائياں ۱۳۲
تاريخ كا تغير و تبدل ۱۳۵
۱۔ نسلي نظريہ ۱۳۶
۲۔ جغرافيائي نظريہ ۱۳۷
۳۔ بلند پايہ شخصيتوں سے متعلق نظريہ ۱۳۷
۴۔ اقتصادي نظريے ۱۳۸
۵۔ الٰہي نظريہ ۱۳۸
تيسرا نظريہ فطرت ۱۴۱
تاريخ ميں شخصيت كا كردار ۱۴۲