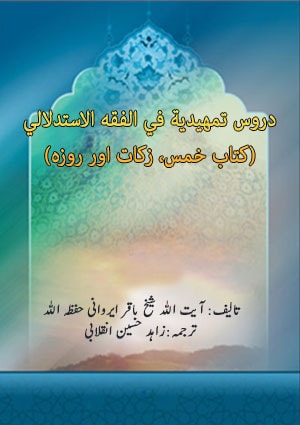یہ کتاب برقی شکل میں نشرہوئی ہے اور شبکہ الامامین الحسنین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں اس کی فنی طورپرتصحیح اور تنظیم ہوئی ہے
دروستمهيدية في الفقه الاستدلالي
(کتاب خمس، زکات اور روزہ)
تالیف: آیت اللہ شیخ باقر ایروانی حفظہ اللہ
ترجمہ:زاہد حسین انقلابی
تصحیح: مولانا سید ظفر علی شاہ نقوی
انتساب!
میری یہ ناچیز کوشش
اپنے مولا وآقا
حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
کے نام!
جن کا دیدار نہ سہی ؛ پھر بھی اپنی زندگی انہی کے لطف و کرم کی گھنی چھاؤں میں
گزر رہی ہے۔
مقدمہ
کتاب کا تعارف:
کتاب“دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی ”آیت اللہ شیخ باقرایروانی حفظہ اللہ کی علمی کوشش کا نتیجہ ہےجس میں احکام کو ذکر دلیل کے ذریعے استدلال کے ساتھ پیش کرنے کی ایک نئی روش اپنائی گئی ہے۔معاصر فقہ میں یہ کتاب ایک نیا اضافہ ہے جو اس شعبے کے طلبہ کے لئے روش استنباط سکھانے اور اپنے دعویٰ کے لئے استدلال پیش کرنے کا طریقہ سکھانے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب ، قدیم درسی کتب کی جگہ لینے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی ہے اور بعض مراکز علمی میں نصاب درسی کے طور پر رائج بھی ہو گئی ہے ۔
مؤلف کا تعارف:
آیت اللہ شیخ محمد باقر ایروانی حفظہ اللہ تقریبا ۱۹۴۹ ء میں عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔آپ نے فقہ و اصول اور عربی ادب میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسی شہر میں درس خارج تک کی تعلیم بھی حاصل کی۔آپ کے اساتذہ میںآیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم الخوئی اور شہید محمد باقر الصدرؒ جیسی شخصیات کا نام آتا ہے۔
۱۹۸۴ ء میں ایران عراق کی جنگ کے دورانآپ نے قم کی طرف ہجرت کی اور کئی سال تک حوزہ علمیہ قم میں درس خارج کے استا د رہے۔درس خارج کے ساتھ ساتھ تالیفات کا سلسلہ بھی جاری رکھا ۔آپ کی مشہور کتب میں “الامام المهدی بین التواتر و حساب الاحتمال ” ،“الاسلوب الثانی للحلقة الثالثة ” ،“دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة ” اور کتاب حاضر “دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی ” شامل ہیں۔
ظالم بعثی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعدآیت اللہ ایروانی حفظہ اللہ نجف اشرف واپس چلے گئے اورآج بھی وہاں پر درس خارج میں مشغول ہیں۔اللہ ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے ! آمین۔
ضرورت ترجمہ:
کسی بھی کتاب کی اہمیت کے پیش نظر دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جانا تمام معاشروں میں رائج اور متداول روش ہے۔ اردو زبان میں بھی عربی اور فارسی سمیت دوسری زبانوں سے مختلف کتب کے ترجمے کئے جا رہے ہیں۔ دینی اور مذہبی کتب کے حوالے سے عقائد، اخلاقیات اور دوسرے معارف دینی پر مشتمل کتب کی کثیر تعداد کا ترجمہ ہوچکا ہے؛ لیکن احکام کے حوالے سے سوائے مراجع کی توضیح المسائل کے کسی دوسری کتاب کا ترجمہ ہماری نظر سے نہیں گزرا؛ لہذا اردو دان طبقے کے لئے احکام کے ساتھ ان کی ادلہ سےآشنائی کی غرض سے فقہ استدلالی کے تمہیدی دروس کے عنوان سے اس ترجمے پر توجہ دی گئی ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے گا۔
کتاب کے مشتملات:
راقم نے کتاب صوم، کتاب زکات اور کتاب خمس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعی کی ہے۔ اس میں روزہ کے احکام، مبطلات روزہ، اعتکاف کے جملہ مسائل، زکات کے احکام، نصاب، مصارف، خمس کے احکام، مصارف اور دیگر بہت سارے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ ان احکام کوثابت کرنے کے لئے زیادہ ترمعصومین ؑ سے مروی روایات سے استناد کیا گیا ہے۔ البتہ گاہے گاہے اصولی قواعد جیسے “اصالہ برائت”، “ استصحاب” اور “قاعدہ فراغ” وغیرہ سے بھی مدد لی گئی ہے۔
وما توفیقی الا باللہ
کتاب صوم
روزہ کو باطل کرنے والی چیزیں
روزہ یعنی قربتا الی اللہ کی نیت سے مندرجہ ذیل چیزوں سے بچنا :
۱ ۔کھانا اور پینا :چاہے وہ چیز عام طور پرکھائی پی جاتی ہوں یا نہ ہوںاور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عادی طریقے سے کھائی یا پی جائے یا غیر عادی طریقے سے ،مقدار کم ہو یا زیادہ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے سر اور سینہ کا بلغم اگر منہ میں آ جائے تو نگلناجائز نہیں ہے. انجکشن لگانا یا کان وغیرہ اور اس جیسےاعضاءمیں قطرے ڈالنا اور اسی طرح تھوک (لعاب دہن) کے نگلنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔
۲ ۔جماع کرنا چاہےآگے میں ہو یا پیچھےمیں، چاہے فاعل ہو یا مفعول اور اگر کوئی شخص جماع کا اردہ کرئےلیکن دخول میں شک کرے یاسپاری کی مقدارمیں دخول کا شک ہو تو صرف قضاء واجب ہے کفارہ نہیں.
۳ ۔منی کے نکلنےکے لیے اگر ایسے مقدمات فراہم کرنے کے بعد منی نکالنا جن سے عام طور پر منی نکل جاتی ہے لیکن اگر بغیر ارادہ کے منی نکل جائے تو نہ اس پر کفارہ ہےاور نہ قضاء ۔
۴ ۔طلوع فجر تک جان بوجھ کرجنابت پر باقی رہنا ۔
۵ ۔اکثر فقہاء کے نزدیک خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنایا اسی طرح کسی ایک معصوم(ع) پر جھوٹ باندھنا ۔
۶ ۔ گاڑھا غبار کا حلق تک پہنچانا ایک نظریے کے مطابق ۔
۷ ۔سر کا پانی میں ڈبونا۔
۸ ۔ سیال چیز سےحقنہ کرنا ۔
۹ ۔جان بوجھ کرقے کرنا ۔
مذکورہ احکام کے دلائل :
۱ ۔روزہ کی نیت میں قصد قربت شرعی لحاظ سے معتبر( ضروری) ہے ۔ لغت کے بر خلاف چونکہ لغوی لحاظ سے قصد قربت معتبر نہیں ہے ۔اور یہ(قصد قربت کا اعتبار) اہل شریعت کے نزدیک ثابت ہونے کی بنا پر ہے کہ جس میں شریعت اسلام کے علاوہ کااحتمال نہیں ہے
اور فضیل بن یسار کی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا :
"الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَة (۱)
ترجمہ :''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے : نماز ، زکات ،حج ، روزہ اور اہلبیت کی ولایت۔"
اوراسلام کی بنیاد کسی ایسی چیزپر نہیں رکھی جا سکتی جس میں قصد قربت نہ ہو ۔
۲ ̵ قصد قربت کا نہ ہونا بالخصوص روزے کو باطل کر دینے کی دلیل اہل شریعت کا اس کے پابندہونا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ایسی دلیلیں ہیں جوعدم قصد قربت کے روزہ باطل ہونے پر دلالت کرتی ہیں لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ مذکورہ بالا موارد کے علاوہ میں ب روزہاطل نہیں ہوتا ہے
۳. کھانے پینے والی چیزو ں پر جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہےاس پر ادلہ :
۱.خداوند متعال فرماتے ہیں :
( وَ كلُواْ وَ اشْرَبُواْ حَتىَ يَتَبَينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخْيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلىَ الَّيْلِ )
ترجمہ:"اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہوجب تک فجر کا سیاہ ڈورا ،سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے"
اور جس پر محمد بن مسلم کی حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ "(۲)
ترجمہ: "{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ }محمد بن مسل.م سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ روزہ دار جب تک ان تین چیزوں سے پرہیز کرئےتو اس کے روزئے کو کوئی چیزنقصان نہیں پہنچاسکتی ہے ۱ ۔ کھانے پینے سے ۔ عورتوں (مباشرت سے)سے۔اور پانی میں پورے سرکےڈبونے سے "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس طلب کی تائید کرتی ہیں ۔
۴.کھانے، پینے والی چیزیں چاہے لوگوں میں رائج ہو ں یا نہ ہو ںاسی طرح چاہے عام طورپرکھائی جانے والی ہوں یا نہ ہوں اور عادی طریقے سے کھائی یا پی جائےیا غیر عادی ۔جس پر دلیل حذف متعلق کی وجہ ہے جوکہ عموم دلالت کرتی ہے یا دلیل اطلاق کی وجہ سے ہے۔
لیکن عام ہونا دو طرف سے عادی طریقے سے کھائی یا پی جائے یا غیر عادی سے اور چاہے کم ہو یا زیادہ یہ اطلاق کی دلیل سے ثابت ہوتی ہے ۔
۵۔اگر سر وسینہ کا بلغم منہ میں آجائےاور روزہ دار اس کو نگل لے تو روزہ باطل ہو جائے گا کیونکہ اس پر کھانا پینا صدق کرتا ہےلیکن اگر منہ کی فضا تک نہیں پہنچا اور خود بخود اندر چلا جائے تو روزہ باطل نہیں ہو گا اور اگر شک کر ئے کہ روزہ صحیح ہےیا نہیں تو قاعدہ برائت جاری ہوگا ۔
۶۔انجکشن اورقطرے اور انکھ و کان میں دوائی ڈالنا جائز ہے کیونکہ ان پر کھانا پینا صدق نہیں کر تا اور اگر اس کی حرمت میں شک کریں تو قاعدہ برائت جاری ہو گا ۔
۷۔لعاب دھن کے نگلنے کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو" نہی "آئی ہے اس کا انصراف کھانے اور پینے پر ہے جوکہ لعاب دھن کے نگلنے پر صدق نہیں کرتی ہے اور اس بات کی تاکید متشرعین کی سیرت سے بھی ہوتی ہے بلکہ ایک اور دلیل جو یہاں ذکر کی جاسکتی ہے وہ یہ کہ اگر لعاب دھن کا نگلنا جائز نہ ہوتا تو روزہ دار کے لیے شدید مشقت کا باعث ہو تا جس سے اللہ تعالی نےاس ایت کی رو سے شریعت میں منع کیا گیا ہے
( مَا جَعَلَ عَلَيْكمُ فىِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (۳)
ترجمہ:" کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے"
۸۔روز ےکی حالت میں ہمبستری کرنا روزے کو باطل کر دیتی ہے کہ رات کو ہمبستری کرنا جائز ہے اور دن کوحرام ہے جس پر دلیل قران کی یہ آیت ہےکہ خداوندعالم ارشاد فرماتے ہیں :
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلىَ نِسَائكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تخَتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنكُمْ فَالَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كلُواْ وَ اشْرَبُواْ حَتىَ يَتَبَينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخْيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (۴)
ترجمہ: " تمہارے لئے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دےا گےا ہے۔ہو تمہارے لئے پردہ پوش ہیں اور تم انکے لئے ۔خدا کو معلام ہے کہ تم اپنے ہی نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کرکے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم با اطمینان مباشرت کرو اور جو خدا نے تمہارے لئے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو اوراس وقت تک کھا پی سکتے ہوجب تک فجر کا سیاہ ڈورا ،سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے" اس سے مراد ہمبستری سے اجتناب کرنا ہے ۔
اور اسی طرح محمد بن مسلم کی صحیح روایت ہے جو کہ پہلے ذکر ہو چکی ہے اور دوسری روایات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے ۔
۹۔ہمبستری کرنا چاہےآگےسےہو یا پیچھےسے ،چاہے فاعل ہو یا مفعول روزہ کو باطل کر دیتی ہے کیونکہ یہ عام ہے جس پر دلیل آیت کا اطلاق ہے جو کہ پہلے گذر چکی ہے ۔
۱۰۔اگر کوئی شخص شک کرئے کہ مباشرت ہوئی ہے یا نہیں ، یا یہ جانتا ہے کہ مباشرت ہوئی ہے لیکن سپاری کے مقدار کے داخل ہونے میں شک کرئے کہ داخل ہوئی ہےیا نہیں تو اس صورت میں قضاء واجب ہے کیونکہ اس شخص نے قصد کیا تھا کہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کسی کو انجام دے گا اور یہ قصد روزے کے قضاء ہونے کا موجب بنتا ہے جس کا ذکر آیندہ عموی احکام میں آئے گا اور یہ کہ اس صورت میں کفارہ دینا واجب نہیں ہے کیونکہ اس پر دلیل استصحاب دلالت کرتی ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوا ہے کیونکہ اسباب کفارہ صادر نہیں ہوئے ہیں ۔
۱۱۔ منی کے نکلنے سے روزہ باطل ہوجاتا ہےجس پر دلیل عبد الرحمن بن حجاج کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِع "(۵)
ترجمہ:"{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ }عبدالرحمن بن حجاج سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سےپوچھا کہ ایک شخص ماہ رمضان میں اپنی اہلیہ سے اس قدربوس وکنار کرتا ہے کہ اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو ؟فرمایا : اس طرح کفارہ واجب ہے جس طرح مجامعت کرنے والے پر واجب ہوتا ہے "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی ا س بات پر دلالت کرتی ہیں کہ منی کا نکلنا مبطلات روزہ میں سے ہیں اور قضاء بھی واجب ہے اگرچہ یہ روایت استمناء کے طلب کے بارے میں ہے لیکن ممکن ہے کہ اس روایت کو بطریق اولی دوسرے مبطلات میں بھی جاری کریں ۔
۱۲۔ اگر منی بغیر قصد کےنکل جائےتو روزہ دار کے اوپر کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں جو مبطل ہیں وہ انسان کے اختیاری افعال ہیں چونکہ یہاں موجب مبطل کی دلیل قاصر ہے جس کی بنا پر براءت سے تمسک کیا جائے گا پس اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ احتلام مبطلات روزہ میں سے نہیں ہے اور روایت میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے جس پر دلیل عبداللہ بن میمون کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَة "(۶)
ترجمہ :"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ} عبداللہ بن میمون سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : تین چیزیں ایسی ہیں جو روزہ کو باطل نہیں کرتیں : ۱ ۔قئی ۲ ۔ احتلام ۳ ۔ اور پچھنے لگوانا "
تین چیزوں سے روزہ دار کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے ۱احتلام سے۲الٹی سے ۳حجامت سے ۔۔۔۔ اور اسی طرح واضح ہے کہ روایت میں بھی روزہ احتلام سے باطل نہیں ہوتا ہےاور اسی طرح روزہ دار کے لیے ممکن ہے کہ دن کو استبراء کرئے اگر چہ روزہ دار جانتا ہوکہ آلہ تناسل میں منی باقی ہے کیونکہ اس سے منی نکلی تھی تو باقی ماندہ منی احتلام سابق کے ساتھ ہے جو اختیاری نہیں تو مبطل روزہ میں سے نہیں ہے ۔
۱۳۔اگر کوئی مجنب روزہ کی حالت میں صبح تک جنابت پر باقی رہے تو اس کا روزہ باطل ہے جسں پر دلیل ابو بصیر کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی موثق روایت ہے :
"مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِيقٌ أَنْ لَا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَدا "(۷)
ترجمہ :"{ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ} ابوبصیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں جس نے ماہ رمضان کی کسی رات اپنے آپ کو جنب کیا اور پھرصبح صادق جان بوجھ کرغسل نہیں کیا ۔ فرمایا ( کفارہ میں )ایک غلام آزاد کرے ،یا دو ماہ مسلسل روزہ رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے (اور اس روز کا روزہ بھی رکھے اور اس کی قضاء بھی کرے )۔ پھر فرمایا : وہ اس لائق ہے کہ میرے خیال کے مطابق وہ کبھی اس روز کے روزہ کی فضیلت کو نہیں پا سکے گا "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں پس اس بنا پر کفارہ کے واجب ہونے اور قضاء کے واجب ہونے پر یہ عمل دلالت کرتی ہے کہ مبطلات روزہ میں سے ایک جان بوجھ کرجنابت پر صبح تک باقی رہنا ہے ۔
اور اس روایت کے مقابلے میں حبیب خثعمی کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْر "(۸)
ترجمہ :"حبیب خثعمی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نےفرمایا :حضرت رسوا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں نماز تہجد پڑھ کر اپنے آپ کو جنب کرتے تھے اور پھرطلوع فجر تک جان بوجھ کرغسل کو مؤخر کرتے تھے "
اور اسی طرح روایت عیص بن قاسم کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْه "(۹)
ترجمہ:"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ} عیص بن قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں رات کے پہلے حصہ میں اپنے آپ کو جنب کیا اور طلوع فجر تک غسل کو مؤخر کیا تو ؟ فرمایا : اس روزہ کو مکمل کرے اوراس پر قضاء نہیں ہے"
اور اس جیسی دوسری روایات ۔
پہلی روایت کا رد۔ اس روایت کے مضمون کی تصدیق نہیں کر سکتے خصوصا روایت میں لفظ (کان) کی شانیت کے مصادیق زیادہ ہیں تو ہم بے بس ہیں کہ لفظ ( کان) کو بعض مصادیق پر حمل کریں ۔
دوسری روایت کا رد۔دوسری روایت مطلق ہے اور ہم بے بس ہیں کہ اس کو غیر عمدی حالت پر حمل کریں کیونکہ روایت ابو بصیر عمدی حالت پر صراحت سےدلالت کرتی ہے ۔
یہاں پر ایک تفصیل ہے جس کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو جنابت کی حالت میں صبح تک باقی رہتاہے کہ پہلی بار سونا صبح کی اذان تک ، اور یہ کہ نیند سے بیدار ہو جائے اور دوبارہ سوجائے جس کے بارے میں روزہ کے عمومی احکام میں اشارہ کیا جائےگا
۱۴۔ ان لوگوں کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اکثر فقہاء کے قول کی بنا پر مبطلات روزہ میں سے ہے
جس پر دلیل ابی بصیر کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع- يُفَطِّرُ الصَّائِمَ "(۱۰)
ترجمہ:"{حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ} ابو بصیر سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا :خدا اور رسول ص اور ائمہ علیھم السلام پر جھوٹ بولنا روزہ دار کے روزے کو توڑ دیتا ہے "
اس روایت کے علاوہ دوسری روایات میں بھی اس ( مبطلات روزہ )کا ذکرکیا گیا ہے ۔
۱۵۔مبطلات روزہ میں سے ایک غبار(گھاڑا) ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے قضاء و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے صرف قضاء واجب ہوتی ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے
جس پر دلیل سلیمان بن حفص مروزی کی حضرت امام کاظم علیہ السلام سے مروی روایت ہے :
"سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَو كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ: الْأَكْلِ، وَ الشُّرْبِ، وَ النِّكَاح "(۱۱)
ترجمہ:"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ }سلیمان بن جعفر (حفص)مروزی سے روایت کرتے ہیں ہے کہ میں نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ: جب روزہ دار ماہ رمضان میں جان بوجھ کر کلی کرئےیا ناک میں پانی ڈالے اور حلق تک پہنچائے یا غلیظ بو سونگھے یا گھر میں جھاڑو دے اور اس کے ناک اور حلق میں غبار داخل ہو جائے تو اس پر مسلسل دو ماہ کا روزہ واجب ہے کیونکہ یہ چیزیں کھانا ، پینا اور جماع کی طرح ہیں جوروزہ کو توڑ دیتی ہیں"
اس موضوع میں مناسب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ کفارہ کو دینا ترجیح رکھتا ہے ۔ اگر ترجیح کی قابلیت ہو ۔ اس دلیل کے ساتھ کہ الفاظ میں جملے کی سیاق کلی کرنےاورناک میں پانی ڈالنے اورعطر کےخوشبو کرنے کو شامل ہے جو کہ یہ موارد یقینا مبطلات روزہ میں سے نہیں ہیں ۔
یہ حکم(قول مناسب) سند روایت سے قطع نظر کہ اس میں مروزی جو کہ ضعیف ہے کیونکہ اس کاموثق ہونا ثابت نہیں ہے اور اس راوی کا مضمر ہونا اوربزرگان راویوں سے نہ ہونابھی ثابت ہے وگرنہ مسئلے کا حکم واضح و روشن ہے( یعنی اگر راوی کا مضمر ہونا دور ہو جائے تو غبار مبطل روزہ میں سے ہے) ۔
پس اس بنا پر مناسب قول یہ ہے کہ اس کے قائل ہو جائے کہ گھاڑا غبارمبطل روزہ میں سے نہیں ہے
۱۶۔پورےسر کو پانی میں ڈبونا قول مشہور کے مطابق مبطل روزہ میں سےہے اور بعض کہتے ہیں کہ فقط حرمت تکلیفی ہےاور ان کی دلیل روایت محمد بن مسلم ہے جوکہ پہلے گذر چکی ہے مگریہ کہ اس کے مقابلے میں روایت اسحاق بن عمار کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی موثق روایت ہے :
"إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ لَا يَعُودَن "(۱۲)
ترجمہ:"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ }اسحاق بن عمار سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روزہ دار شخص جان بوجھ کر پانی میں ڈبکی لیتا ہے ۔ آیا اس پر اس دن کی قضاء واجب ہے ؟ فرمایا : اس پر قضاء واجب نہیں ہے مگردوبارہ تکرار نہ کرے "
اور بعض اوقات ممکن ہے کہ روایات کو اس طرح جمع کرئےکہ روایت اول کوروایت دوم کے قرینہ کے ذریعے سے جوکہ روزے کی قضاء کے واجب ہونے کونفی کرتی ہے تو اس کو حرمت تکلیفی پر حمل کرتے ہیں ۔
مگریہ کہ ضروری ہو جائے کہ مضر سے مراد روزہ دار کے لیے مضر ہونے پر حمل کریں ۔ نہ کہ روزے کی صحت کےلیے مضر ہونے پر حمل کریں ۔ پس اس بنا پر روزہ دار مکلف ہے اور اس طرح کا حمل بعید ہے ۔
اور بعض اس کے قائل ہیں کہ ان دو روایات کے درمیان تعارض(اختلاف ) برقرارہے یعنی ان دونوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں پس دوسری روایت اسحاق بن عمار کو تقیہ پر حمل کرتے ہیں کیونکہ ان کے نتیجہ کا حکم روزہ کے باطل ہونے پر ہے ۔
۱۷-مائع چیزوں کے ساتھ حقنہ کرنا:سیال چیزوں سے حقنہ کرنے کی "تکلیفی حرمت(حقنہ کے حرام ہونے میں )" میں کسی قسم کوئی اشکال نہیں پایاجاتاہے جس پردلیل احمدبن محمدبن ابی نصر کی امام رضا علیہ السلام سے مروی یہ صحیح روایت ہے :
"أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ "(۱۳)
ترجمہ :"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ} احمد بن محمد بن نصر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ ماہ رمضان میں آدمی کو کچھ تکلیف ہوتی ہے ۔کیا وہ حقنہ کرسکتا ہے ؟ فرمایا : روزہ دار کے لیے (مائع چیز سے)حقنہ کرنا جائز نہیں ہے "
اگرحقنہ کرنے سے اُس کے مایع ہونے کا حکم نہیں سمجھ میں آتاہے تو پھر ضروری ہے کہ اس حقنہ کرنے کے ساتھ مائع چیزکے ساتھ حقنہ کرنے کی قید لگائی جائے ۔اور اس پردلیل حسن بن فضال کی امام موسی کاظم علیہ السلام سے مروی یہ موثق روایت ہے :
"كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِد "(۱۴)
ترجمہ :"میں نے امام موسی کاظم علیہ السلام کو خط لکھا کہ اگر ایک روزےکی حالت میں ایک بتی کو اپنے اندر داخل کرے تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ؟امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جامد چیزکے ساتھ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے"
اور کیا حقنہ کرنے پر روزہ کے باطل ہونے کا حکم بھی لگایاجا سکتا ہے ؟ یہ حکم لگانا بعید نہیں کیونکہ عرف میں اُن اعمال کے بارے میں جو مختلف اجزاء سے مرکب ہیں (جیسے نمازاور روزہ وغیرہ میں )نہی کا ظہور اس کے مانع ہونے اور اس کی مخالفت سے اُس عمل کے فاسد(باطل)ہونے میں ہے۔
اورجس بات سے ہمارے موقف کی تاکیدہوتی ہے وہ سائل کا حقنہ کی ضرورت کے متعلق سوال کرنا ہے۔جس کے ساتھ اس کی "تکلیفی حرمت "(حرام ہونا)کا کوئی معنی نہیں بنتا۔لہذا ضروری ہے کہ یہ کہاجائے اس کا مقصد بطلان کے بارے میں راہنمائی حاصل کرنا تھا۔
۱۸۔ جان بوجھ کرقئ کرنے سے روزے کا بطلان :مشہورقول یہی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتاہے۔اوراس پر دلیل حلبی کی امام صادق علیہ السلام سے منقول یہ صحیح روایت ہے :
"حَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ "(۱۵)
ترجمہ :"{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ }حلبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا :جب کوئی روزہ دار جان بوجھ کرقئی کرئے تو اس نے روزہ توڑ دیا ۔ اور اگر بے اختیار آ جائے تو پھر اپنے روزہ کو مکمل کرے "
مگر صحیح مذکور کے مقابلے میں عبداللہ بن میمون کی امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے:
"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَة "(۱۶)
ترجمہ :"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ } عبداللہ بن میمون سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : تین چیزیں ایسی ہیں جو روزہ کو باطل نہیں کرتیں : ۱ ۔قئی ۲ ۔ احتلام ۳ ۔ اور پچھنے لگوانا "
پس اس روایت میں قئی کو غیر عمدی پر حمل کرئے گے
روزہ کےصحیح ہونے کی شرائط:
روزہ کے صحیح ہونے کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں:
۱۔اسلام
۲۔عقل
۳۔حیض اور نفاس سے پاک ہونا
۴۔وہ سفر جس سے نمازقصرہوجاتی ہے۔سوائے اُس مسافر کے کہ جو یاتو حکم سے جاہل ہےیااپنے وطن سے یا اُس جگہ سے جو اس کے وطن کے حکم میں ہے زوال کے بعد نکلا ہےیاپھر زوال سے پہلے اپنے وطن یااُس جگہ پہنچ جائے ،جہاں اس نے (دس دن یا اس سے زیادہ دن )ٹھرنے کا ارادہ کر رکھاہے ۔
۵۔اور نقصان دہ مرض ہو تو ان موارد میں روزہ دار کا روزہ صحیح ہے ۔
یہ بات ثابت ہونے کے لیے بیماری کے نقصان دہ ہونے کا ڈر کافی ہے ۔ اور ماہر اور قابل اعتماد ذاکٹر کی بات بھی (اس سلسلے میں ) حجت ہے
مذکورہ احکام کےدلائل :
۱۔اسلام
روزہ کے صحیح ہونے کی شرط میں سے ایک اسلام ہے اور اس پر دلیل اجماع ہےاور بعض اوقات اس پر قرآن کی اس آیت کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے ۔
( وَ مَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنهْمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَ بِرَسُوله ) (۱۷)
ترجمہ: اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی قبولیت کی راہ میں بس یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔
اس آیت کے ساتھ دلیل اولویت کو ملانے کے بعد اس سےعموم کا استفادہ کیا جاسکتاہے۔(۱۸)
اور اوپر والی دلیل کے علاوہ ممکن ہے کہ ان روایات سے بھی یہ حکم ثابت کیا جو ولایت (امیر المئومنین اور اولاد امیر المئومنین ) کو روزہ کے صحیح ہونےکے لیےشرط جانتی ہیں کیونکہ کافر ولایت کو نہیں مانتا ہے جس پر دلیل عبدالحمید بن ابی العلاءکی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
" عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ كَذَلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَاصِيَةُ الْمَفْتُونَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا ص وَ بَعْدَ تَرْكِهِمُ الْإِمَامَ الَّذِي نَصَبَهُ نَبِيُّهُمْ ص لَهُمْ فَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَمَلًا وَ لَنْ يَرْفَعَ لَهُمْ حَسَنَةً حَتَّى يَأْتُوا اللَّهَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ وَ يَتَوَلَّوُا الْإِمَامَ الَّذِي أُمِرُوا بِوَلَايَتِهِ وَ يَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الَّذِي فَتَحَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ "(۱۹)
"ترجمہ: ابی علاء حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں ۔۔۔۔ایسا ہے کہ یہ گناہ گار لوگ پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ کے بعد امتحان میں واقع ہو گئے اور اس کے بعد امام علیہ اسلام کو پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے منصوب کیا تھا لوگوں نے چھوڑ دیا ۔خدا وند عالم ان کے اعمال کو قبول نہیں کرئے گا اور کوئی نیکی ان کے لیے نہیں لکھے گا جب تک وہ راستہ جس پر خدا نے خکم دیا ہے اے کی طرف آ جائیں اور اس کی امام علیہ السلام کی طرف جس کا حکم کیا ہے اور وہ باب سے داخل ہوں جس کو خدا وند عالم نے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے کھولا ہے
اوراس روایت سے روزہ کی صحت کے لیے اسلام کی شرط کے ساتھ ایمان کی شرط بھی ثابت ہوتی ہے ۔
اگر اشکال ہو کہ آیت اور روایات کی دلالت قبول اعمال پرہے نہ کہ شرط صحت اعمال پر ـ جبکہ یہ دلالت محل کلام سے خارج ہے کیونکہ ہمارامحل کلام صحت عمل ہے اور اس عمل کو انجام دینے کے بعد مکلف بری الذمہ ہو جاتا ہے جیساکہ خدا وندمتعال ارشاد فرماتے ہیں کہ
( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين ) (۲۰)
ترجمہ: خدا صرف صاحبان تقوٰی کے اعمال کو قبول کرتا ہے ۔
اس کے بعد اس شرط ہونے پر "قطعی اجماع" کے علاوہ کوئی دلیل باقی نہیں رہتی ۔ اور مستزادیہ کہ بعض کافروں سے قربت کی نیت ٹھیک نہیں ہے حالانکہ عبادات میں قصد قربت شرط ہے اور یہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کا قرب حاصل کرنا بے معنی ہے ۔
۲۔ عقل کا روزہ صحیح ہونے کی شرط ہونا:
اس کی دلیل یہ ہےکہ عقل کےعلاوہ نیت ہی نہیں کی جاسکتی ہےکیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے مجنون (پاگل)مکلف ہی نہیں ہے۔پس جب اللہ کی طرف احکام اس کو شامل ہی نہیں ہیں تو اس کے بعد عقل کے روزہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہونے پر مزیدکسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
۳۔ حیض اورنفاس سے پاک ہونا:
عیص بن قاسم کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے:
عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَث (۲۱)
ترجمہ :''عیص بن قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک عورت کو ماہ رمضان میں غروب آفتاب سے کچھ پہلے خون حیض آ جائے تو ؟ فرمایا : جیسےہی حیض آئے اسی وقت روزہ افطار کر دے''
اور اسی طرح عبدالرحمن بن حجاج کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
سالت أبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ قَالَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ (۲۲)
ترجمہ:''{ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ } عبدالرحمن بن الحجاج سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک روزہ دار عورت نے عصر کے بعد بچے کو جنم دیا آیا وہ اس دن کا روزہ تمام کرے یا کھول دے ؟ فرمایا:کھول دے اور اس کی قضاء کرے ''
یہ حکم اوپر والی روایت کے مطابق ہے لیکن اس کے مقابلےمیں ابی بصیر کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی یہ صحیح روایت ہے:
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةٍ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ وَ تَشْرَبْ (۲۳)
ترجمہ :''ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : اگر کوئی عورت ماہ رمضان میں زوال آفتاب سے پہلے حائض ہو جائے تو وہ (روزہ افطار کرکے) کھا پی سکتی ہے اور اگر زوال کے بعد یہ صورت پیش آئے تو غسل کرکے اس روزہ کو شمار کرے جب تک کچھ کھایا پیا نہ ہو ''
مگر یہ روایت اصحاب امامیہ کے نزدیک متروکہ (یعنی اصحاب نے اس روایت سے دوری اختیار کی ہے ) ہےاور کسی نے اس پر عمل نہیں کیا ہے پس اس روایت کا اعتبار باقی نہیں رہتاہے۔
۴۔سفر نہ کرنے کی شرط صحت روزہ ہونا:
اس پر دلیل خدا وند متعال کا یہ ارشاد گرامی ہے :
( و مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر ) (۲۴)
ترجمہ :''اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانہ میں رکھے''
دوسری دلیل روایت موثقۃ سماعہ ( اعتماد کرنا)بھی موجود ہے جو کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں ۔
سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ فَلَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحَجِّ (۲۵)
ترجمہ :''{ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ } سماعہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان (حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ) سے پوچھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے ؟ فرمایا : سفر میں روزہ نہیں ہے کچھ لوگوں نے عہد رسالت میں سفر میں روزہ رکھا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نےان کا نام گنہگار رکھا تھا ۔ پس سفر میں روزہ نہیں ہے ماسوا حج کے ان تین روزوں کے جن کا خدا نے (تمتع میں قربانی نہ دےسکنے کی وجہ سے ) حکم دیا ہے (اور سات واپس گھر پہنچ کر کل دس روزے)''
اور اے کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں
روایت سماعہ مضمر ہے تو پھر مضمر پر استدلال کس طرح کرتے ہیں ؟
یہ اضمار نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اضمار بزگان اصحاب کی جانب سے ہے اور روایت بیان کرنا غیر امام سے ان کے لائق نہیں ہے
۵۔ شرط صحت روزہ میں سےایک یہ ہے کہ مکلف کاسفر نمازکےقصرہونےکاموجب بنے ۔اس پر دلیل روایت معاویہ بن وھب کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی یہ صحیح روایت ہے :
''مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: هَذَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَرْتَ'' (۲۶)
ترجمہ :''{ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ }معاویہ بن وھب سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیا السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا : سلسلہ ایک ہے ۔ جب نماز قصر کرو تو روزہ افطار کرو اور جب روزہ افطار کرو تو نماز قصر کرو ''
۶۔اگر کوئی مسافر سفر کے دوران افطارکے حکم سے جاہل ہے یعنی نہیں جانتا کہ مسافر کا روزہ سفر میں درست نہیں ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے جس پر دلیل عیص بن قاسم کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
عن صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِه (۲۷)
ترجمہ:''صفوان بن یحیی نےعیص بن قاسم سے روایت کی ہے جوکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہیں فرمایا :جب کوئی شخص ماہ رمضان میں سفر کرے تو روزہ افطار کرے گا اور اگر جہالت ولاعلمی کی وجہ سے رکھے تو اس کی قضاء نہیں کرے گا ''
اس کے علاوہ دوسری روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
مذکورہ بالا روایت مطلق ہے (کسی قسم کی قید نہیں لگائی گئی ہے )اس لیے کہ یہ اس شخص کو بھی شامل ہوتی ہے جس کو سرے سے ہی حکم معلوم نہیں ہے اور اس کو بھی جس کو اصل حکم تو معلوم ہے لیکن بعض خصوصیات کا علم نہیں ہے ۔مثلا اس کو یہ علم نہیں ہے کہ زوال سے پہلے سفر کرے اور زوال کے بعد واپس لوٹے اس کا روزہ نہیں ہوتا ۔
۷۔اگر مسافر بعد از زوال اپنے وطن سے حرکت کرے تو اس کا روزہ صحیح ہےاس کے لیے روزہ توڑنا حرام ہے ۔ لیکن جو شخص زوال سےپہلےسفرکرئے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور یہ مشہور فقہاء کا نظریہ ہےجس پر دلیل عبید بن زرارہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی یہ صحیح روایت ہے :
''عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلُ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَصُومُ أَوْ يُفْطِرُ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيَصُمْ فَقَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ ع أَصُومُ وَ أُفْطِرُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عُزِمَ عَلَيَّ يَعْنِي الصِّيَام ''(۲۸)
ترجمہ : عبید بن زرارہ سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں سفر کرئے تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا روزہ توڑ دے گا ؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا : اگر زوال سے پہلے سفر کرے تو افطار کرے اور اگر زوال کے بعد نکلے تو پھر روزہ مکمل کرے ۔ پھر فرمایا : یہ بات حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان سے معلوم ہوتی ہے ، فرمایا : میں روزہ رکھتا ہوں اور (بوجہ سفر) افطار کرتا ہوں مگر جب زوال ہو جائے تو پھر مجھ پر ضروری ہو جاتا ہے یعنی روزہ ''
لیکن زرارہ کی صحیح روایت کے مقابلے میں علی بن یقطین کی حضرت امام کاظم علیہ السلام سے مروی موثق روایت ہے :
''عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِي اللَّيْلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ ''(۲۹)
ترجمہ : ''صفوان حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا :اگر کوئی شخص اپنے گھر (کوفہ) سے نہروان کے سفر کے ارادہ سے نکلے کہ جائے گا اور واپس آے گا تو اسے چاہیے کہ رات کو سفر کرنے اور روزہ افطار کرنے کی نیت کرے لیکن اگر اس حالت میں صبح کرے کا سفر کا کوئی ارادہ نہ ہو ہاں البتہ صبح کے بعد ارادہ کرے تو (نماز تو ) قصر کرے گا لیکن اس دن روزہ افطار نہیں کرے گا''
پس امام کاظم علیہ السلام نے افطار اور عدم افطار میں وجود نیت کو ملاک جانا ہے جوکہ اس نے سفر سے پہلے رات کو کیا ہو
اگر ان دو روایتوں کے درمیان تعرض (ٹکراؤ ) ثابت ہو جائے تو اول کو ترجیح دیں گے کیونکہ پہلی روایت تقیہ کے مخالف ہے پس اس سے قول مشہور بھی ثابت ہو جائے گا ۔
۸۔مشہور تفصیل کے قائل ہیں کہ اگر مسافر اپنے وطن کو قبل از زوال پلٹ ائے اور کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے ا اور اسی طرح اگر مسافر بعد از زوال اپنے وطن واپس پلٹ آئے تواس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے جس پر دلیل ابی بصیر کی حضرت امام صادق علیہ السلام سےمروی یہ موثق روایت ہے:
''أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ'' (۳۰)
ترجمہ :''{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ } ابو بصیر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے ان ( حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں سفر کیا ہے اور گھر واپس لوٹ آیا ہے ؟ امام علیہ السلام نے فرمایا : اگر زوال سے پہلے پہنچ جائے تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے اور اسے ماہ رمبارک کا روزہ شمار بھی کرے گا ''
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
لیکن اپنے وطن کو پہنچنے سے پہلے اس کو اختیار ہے کہ روزہ رکھے یا افطار کرئے جس پر دلیل محمد بن مسلم کی حضرت امام باقرعلیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے:
''مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ'' (۳۱)
ترجمہ : ''محمد بن مسلم بیان کرتےہیں کہ میں نےحضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص ماہ رمضان میں سفر سے واپس گھر آرہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ چاشت کے وقت یا اس سے کچھ دیر بعد گھر پہنچ جائے گا تو ؟ فرمایا : اگر اسے گھر پہنچنے سے پہلے راستہ میں طلوع فجر ہو جائے تو اسے اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو (سفر میں) افطار کرے ''
اس روایت میں امام علیہ السلام اختیار کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے وطن کے حد ترخص تک نہیں پہنچا تو وہ مختار ہے چاہے افطار کرے یا نہ کرے ۔اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں
۹۔اگر کوئی مسافر سفر کرئے اور اس علاقے یا شہر میں داخل ہو جائے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اقامت (یعنی دس دن کے ٹھرنے) کاقصد کرئے تو چاہے وہ شخص محل اقامت میں قبل از طلوع فجر یا قبل از زوال داخل ہو دونوں حالتوں میں اس پر روزہ رکھنا واجب ہے ۔جس پر دلیل روایت صحیحہ محمد بن مسلم ہے جوکہ حضرت امام صادق علیہ السلامسے نقل فرماتے ہیں :
''مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ ''(۳۲)
ترجمہ :''{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ }محمد بن مسلم سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کے ضمن میں فرمایا : جب کوئی مسافر طلوع فجر سے پہلے کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں دس روزہ قیام کا پروگرام ہو ۔ تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا لازم ہے اور اگر طلوع فجر کے بعد وہاں پہنچے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے اور اگر چاہے تو رکھ لے ''
اس روایت کے مقابلے میں قول مشہور ہے جو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا واجب ہے اگرچہ قبل زوال پہنچا ہو اور فرق نہیں کرتا ہے کہ قبل از طلوع فجر ہو یا بعد از طلوع فجر ہو ۔
تو اس صورت میں احتیاط مقتضی دلیل ہے چونکہ احتیاط کی وجہ سے قول مشہور کی مخالفت سے اور روایت صحیحہ کی مخالفت سے بچ جائیں گے ۔
۱۰۔ بیمارنہ ہو( یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو) جیسا کہ خداوندہ متعال فرماتے ہیں:
( وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (۳۳)
ترجمہ:''اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانہ میں رکھے''
اور تمام روایات شریفہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مرض روزہ دار کے لیے نقصان دہ ہو اگرچہ دلائل میں اس سے انصراف کیا ہے اور روایات میں اس کی تصریح کی گئی ہے جیساکہ صحیح محمد بن مسلم میں ہے جوکہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں :
''قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرِيضِ إِذَا نَقِهَ فِي الصِّيَامِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَصُم'' (۳۴)
ترجمہ: ''{ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ }محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نےحضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بیماری کی وہ حدکون سی ہے جو اسے روزہ سے کمزور کرتی ہے ؟فرمایا : وہ اپنی طبیعت کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے پس جب طاقت ہو تو روزہ رکھے ''
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
پس اگر اس کے لیے مرض نقصان دہ ہے اور جانتا ہے کہ روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہے یا ضرر کا خوف ہو تو اس پر روزہ رکھنا لازمی نہیں ہے.
۱۱۔ روزہ دار کے لیے مرض سے خوف کا ہونا کافی ہےاوردلیل عقلائی مرض کے نقصان کو مشخص کرنے کے باب سے اس پر دلالت کرتی ہے اور اےس کے علاوہ شارع نے بھی اس کو رد نہیں کیا ہےاور اس پر روایت صحیح حریز بھی ہے جوکہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں :
''مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الرَّمَدِ أَفْطَرَ ''(۳۵)
ترجمہ : ''{حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ } حریز سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: روزہ دار کو جب آشوب چشم کی وجہ سے
آنکھوں کا خطرہ ہو تو روزہ افطار کر سکتا ہے ''
پس اس بنا پر جو دلائل مرض کے خوف کے لیے ذکر کیے گئے وہ روزہ کو افطار کرنے کے لیے حجت ہیں ۔
۱۲۔ اگرماہر ڈاکٹر کہے تو طریقہ عقلائی کی بنا پر اس کی بات حجت ہوگیاور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ۔ پس وہ ماہر ڈاکٹر کی بات کو مانے گا جب مریض کو ڈاکٹر کی بات پر اعتماد اور اطمینان حاصل ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھے کیونکہ ضرر کی تشخص کے باب میں بیان ہوا ہے جس سے شارع نے نہیں روکا ہے اور ہاں اگر اس کی بات پر یقین حاصل نہ ہو تب بھی حجت ہے فقط دو صورتوں میں ماہر ڈاکٹر کی بات حجت نہیں ہو گی
ا۔ اگر آپ جانتے ہو کہ ڈاکٹر نے اشتباہ کیا ہے تو آپ نے علم پر عمل کریں گے کیونکہ حجت ذاتی ہے
ب۔ اور اگر اطمینان ہو کہ ماہر ڈاکٹر نے اشتباہ کیا ہے تو ڈاکٹر کی بات حجت نہیں ہے کیونکہ حجت شرعی اس کے خلاف ہے بس اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ضرر کا خوف مریض کے لیے دو راستوں سے ثابت ہو جاتا ہے خوف وجدانی سے اور ماہر ڈاکٹر کی قول سے ۔
سوال:ایا ہر قسم کا خوف روزہ نہ رکھنے کا موجب ہے ؟
جواب:نہیں ہر قسم کا خوف روزہ نہ رکھنے کا موجب نہیں بنتا ہے بلکہ نقصان کا خوف عقلائی ہو یعنی کوئی اور فرد اس جگہ پر کیوں نہ ہو اگر اس قسم کا خوف رکھتا ہو کیونکہ روایت حریز میں قید (ضرر خوف اگر منشاء عقلائی ہو)سے منصرف ہے
سوال:دلیل اطلاق سب کو شامل ہوتی ہے یا نہیں؟
جواب:ہماری دلیل فقط سیرہ عقلائی ہے جس کو روایت میں بھی مد نظر رکھا گیا ہے پس ضروری ہے کہ حتی الامکان یقین پر اکتفا کریں کیونکہ یقین کے علاوہ اقتضاء نہیں کرتا ہے
روزےکے عام احکام
روزہ توڑنے اورروزے کی قضا اُسی وقت واجب ہوتی ہے کہ جب مذکورہ مبطلات روزہ اشیا ءمیں سے -جنابت پر باقی رہنے کے علاوہ-کو آپ نے اختیار سے جان بوجھ کر استعمال کیا ہو۔چاہے وہ ماہ رمضان میں ہویارمضان کے علاوہ۔
جسے روزہ توڑنے کا علم نہ ہوتو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس مسئلے کا جاننے والا- تو یہ بھی جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے کے حکم میں ہے ۔
روزہ توڑنے کا کفارے کی تین قسموں میں اسے اختیار حاصل ہے {ان میں سے کوئی بھی آپ نی مرضی سے ادا کر سکتاہے}۔جو شخص روزے کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا ہے اس کے لئے استغفار کرلینا ہی کافی ہے۔لیکن جیسے ہی یہ کفارہ دے سکنے کے قابل ہوا تو اس پر کفارہ کا ادا کرنا واجب ہے۔
طلوع فجر میں شک کرنے والا کھا پی سکتاہے۔اوراگر بعد میں اسے پتہ چلے کہ طلوع ہو چکا تھا اب اگر اس نے سب شرائط کی رعایت نہیں کی تھی تو اس پر صرف قضا ہی واجب ہے۔لیکن اگر وہ آپ نی شک کی حالت پر باقی رہا {یعنی اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ طلوع ہو چکا تھا یا نہیں } تواس پرکوئی چیز واجب نہیں ہے{ نہ ہی قضا اور نہ ہی کفارہ}
غروب کے بارے میں شک کرنے والا روزہ نہیں توڑ سکتاہے ۔ اوراگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔ مگر یہ کہ اُس معلوم ہو جاے کہ اس نے جس وقت روزہ توڑا تھا اس وقت غروب ہو چکا تھا اور افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔
اگر کوئی شخص روزہ توڑنے کی نیت کرے لیکن روزہ نہ توڑے تو ایسے شخص پر صرف قضا واجب ہے۔
دلائل:
جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے کفارے کے واجب ہونا مندرجہ ذیل دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے:
ا ۔ مقتضی میں کمی پائی جاتی ہے۔کیونکہ گذشتہ صفحات میں محمد بن مسلم سے منقول صحیح روایت ہے:
"مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاء "(۳۶)
ترجمہ :حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ روزہ دار کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی جب تین چیزوں سے اجتناب کرے ۱ ۔ کھانے پینے سے ۲ ۔ عورتوں (مباشرت سے )سے ۳ ۔ اور پانی میں غوطہ زنی سے )میں " اجتناب" کا تذکرہ پایا جاتاہے۔ اس لفظ کا اطلاق جان بوجھ کر افطار کرنے کے ساتھ ساتھ سہوا روزہ افطار کرنے پر بھی ہوتاہے۔
اور اگر کرئی شک کرے کہ اس کا کھانا پینا سہوا روزہ کو باطل کرتی ہے کہ نہیں تو اس صورت میں براءت جاری ہو گی ۔
ب:لیکن اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ مقتضی تام ہے اور متقضی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہائی جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں امام جعفرصادق علیہ السلام سے مروی حلبی کی صحیح روایت وغیرہ سے ہاتھ اُٹھانا پڑے گا ۔ کیونکہ روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
"مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ لَا يُفْطِرْ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَه "(۳۷)
ترجمہ : {حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ } حلبی سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سےپوچھا گیا کہ ایک شخص نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا ، بعد ازان یاد آیا تو ؟ فرمایا : وہ روزہ نہ کھولے ۔ یہ تو ایک چیز ہے جو خدا نے اسے عطا کی ہے اسے چاہیے کہ روزہ مکمل کرے )
اس روایت جو علت (إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ ) بیان کی گئی ہے وہ عام ہے جو کھانے پینے کے علاوہ دوسرے مبطلات روزہ کو بھی شامل ہوتی ہے۔
بلکہ اس بات کا استفادہ ہم عبداللہ بن سنان کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی اس حدیث سےکرتے ہیں:
"بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلَ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْء "(۳۸)
ترجمہ : " عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : ہر وہ تکلیف جو خدا مسلط کرے اس سلسلہ میں آدمی پر کچھ نہیں ہے "
اس حدیث میں بیان شدہ اس قاعدہ (كُلَ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْء ) کر سکتے ہیں کہ عمدا کھانا پینا روزہ کو باطل کرتا ہے کیونکہ حالت نسیان میں خداوندہ متعال انسان پر غلبہ کرتا ہے اور اس کا عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پس اس پر کوئی چیز واجب (قضاء و کفارہ)نہیں ہوتی ہے
اسی طرح حدیث رفع سے بھی تمسک کرسکتے ہیں بشرطیکہ حدیث (رفع النسیان)(۳۹) رفع فقط عقابت اخروی کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ مطلق ہواور آثار وضعی (روزہ کے باطل کرنے والی چیزے )اور تکلیفی (حرام) اور عقابت اخروی پر دلالت کرتی ہے۔
۲۔ مذکورہ حکم سے طلوع آفتاب تک حالت جنابت میں باقی رہنے کےمستثنی ہونے پر دلیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص قبل از طلوع فجر بیدار ہو اور غسل نہ کرے اور دوبارہ سو جائے (چاہے غسل کا قصد ہو یا نہ ہو)یا بعد از طلوع فجر بیدار ہو تو دونوں صورتوں میں اس پر قضاء واجب ہو جائے گی اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
"مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُقُوبَةً "(۴۰)
ترجمہ : "{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ } معاویہ بن عمار سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت عرض کیا کہ ایک شخص اول شب میں جنب ہوتا ہے اور ماہ رمضان میں صبح تک سوتا رہتا ہے ؟ فرمایا : اس پر کچھ نہیں ہے پھر عرض کیا : اگر ایک بار جاگے اور پھر سو جائے اور صبح تک سوتا رہے تو ؟ فرمایا : بطور سزا اس دن کی قضا کرے "
۳۔ ماہ رمضان کے روزے ہوں یا ماہ رمضان(قضاء"نذر)کے علاوہ ہوں اس پر دلیل حلبی کی صحیح روایات وغیرہ کا اطلاق ہے ۔ اوران میں سے بعض روایات کا ماہ مبارک رمضان کے ساتھ خاص ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
۴۔ جاہل کے عالم کے حکم میں ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جاہل جان بوجھ کر آپ نے ارادے سے ایسا کرتاہے ۔ منتہی وہ یہ نہیں جانتاہے کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ،لہذا مبطلات والی دلیلوں کا اطلاق اس کو بھی شامل ہے۔
۵۔ کفارہ کے تین قسموں (ازاد کرنا ایک غلام کا " ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا " دو ماہ متواتر روزے رکھنا ) میں مختار ہونا تویہ قول مشہور ہے اورروایات چند قسم کی ہیں:
ا۔ روایت میں سے پہلی قسم اختیار پر دلالت کرتی ہے جیساکہ روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
"رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ (۴۱)
ترجمہ : " {حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ} عبداللہ بن سنان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نےاس شخص کے بارے میں جو جان بوجھ کر بلا عذر ماہ رمضان کا ایک روزہ نہ رکھے (یا رکھ کر توڑ دے ) ۔ فرمایا : ایک غلام آزاد کرے یا دو ماہ مسلسل روزہ رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو حسب طاقت صدقہ دے)"
اس روایت میں لفظ (او) کا استعمال ہوا ہے جوکہ اختیار پر دلالت کرتی ہے
ب ۔ روایت میں دوسری قسم ترتیب پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
"عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِاللَّه "(۴۲)
ترجمہ : "جناب علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ نے بھائی حضرت امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں روزہ کی حالت میں اپنی اہلیہ سے مباشرت کی ہے تو اس پر کیا ہے ؟ فرمایا : اس پر ایک قضا ہے اور (کفارہ میں) ایک غلام آزاد کرنا اگر یہ نہ کر سکے تو پے در پے دو ماہ روزے رکھے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو خدا سے طلب مغفرت کرے "
یہ روایت صحیح ہے۔کیونکہ {شیخ حرعاملی }صاحب وسائل الشیعہ کا دیگر کتابوں سے روایات نقل کرنے کا ایک معتبر طریقہ ہے اور وہ یہ ہے ان سب کی انتہاء شیخ طوسی پر ہوتی ہے۔اوراس طریق کی وضاحت انہوں نے "وسائل الشیعہ" کے آخر میں دی ہے۔انہی{جن سے صاحب وسائل نقل کرتےہیں}کتابوں میں سے ایک "علی بن جعفر" کی کتاب بھی ہے۔کیونکہ شیخ کا " الفھرست " علی بن جعفر کی کتاب تک ایک صحیح طریق ہے ۔
اوران دونوں قسم کی حدیثوں کی سند کو اگر مکمل اور صحیح مان لیا جائے تب بھی ان کے درمیان جمع ممکن ہے وہ اس طرح کے دوسری قسم والی احادیث کو اسحباب پر حمل کریں گے کیونکہ پہلی میں قرینہ موجود ہے۔
۶۔ اور اگر ایک بندہ کفارہ(ازاد کرنا ایک غلام کا " ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا " دو ماہ متواتر روزے رکھنا )دینے سے قاصر ہے تو اس کے لیے کفارہ کے بدلے میں استغفار کافی ہے اور اس کے لیے دلیل مذکورہ علی بن جعفر والی حدیث ہے۔
۷- جب کفارہ ادا کر نے کی قدرت آجائے تو اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ کفارہ کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہے۔اگراس کا کوئی خاص وقت معین ہوتا تو اب جب کہ وجوب کفارہ استغفار کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اب اس کے لئے ایک خاص دلیل کی ضرورت ہے حالانکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور کفارہ کی تقسیمات والی دلیلوں میں ہے کہ جب بھی کفارہ ادا کر سکے تو اسے ادا کرے۔
۸۔ طلوع فجر میں شک کرنے والے کے لیے کھانے پینے کے جائز ہونے کی دلیل استصحاب موضوعی ہے(استحباب بقاء اللیل یعنی یہ استصحاب کرے گا کہ ابھی تک رات ہے ۔اور رات میں کھانا پینا جائز ہے۔ لہذا اب بھی اس کے لئے کھانا جائز ہے)
۹۔ اور بعد میں طلوع کا پتہ چلنے کی صورت میں قضا کے واجب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ابھی واجب ادا نہیں کیا ہے اور وہ واجب دونوں حدوں کے درمیان آپ نے آپ کو مبطلات روزہ سے بچائےرکھنا تھا۔ اس صورت میں استصحاب ، حکم تکلیفی کو اٹھا لیتا ہے ۔یعنی اس شخص نے کوئی حرام کام نہیں کیا ہے۔لیکن استصحاب یہاں حکم وضعی کو نہیں اٹھا سکتاہے اور وہ ابھی تک باقی ہے یعنی اس کا روزہ باطل ہے۔یہ سب قاعدے(اولی)کےمطابق ہے لیکن اگر روایت کے مقتضی (قاعدہ ثانوی)کےمطابق یہاں تفصیل کا قائل ہوناچاہیے۔ یعنی اس نے شرائط کی رعایت کی ہے یا نہیں ۔چونکہ سماعہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سےمروی صحیح روایت میں آیاہے :کہ
"أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ "(۴۳)
ترجمہ : "{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ} سماعہ بن مہران سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ کہ میں نے ان ( حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ) سے پوچھا کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں طلوع فجر کے بعد کھایا اور پیا تو ؟ فرمایا : اگر تو اس نے اٹھ کر دیکھا اور فجر نظر نہ آئی اور کھانے پینے کے بعد پتہ چلا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو وہ اس روزہ کو مکمل کرے اس پر قضا نہیں ہے ۔ اور اگر اٹھ کر دیکھے بغیر کھائے پیے اوربعد ازاں دیکھا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس روزہ کو مکمل کرے اور پھر اس کی قضا بھی کرے کیونکہ اس نے تحقیق حال سے پہلے کھایا ہے ۔ لہذا اس پر اعادہ لازم ہے "
اورسماعہ کی روایت کے مضمر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ سماعہ ایک ایسا صحابی ہے کہ جو امام علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے سے روایت نقل نہیں کرتاہے۔
۱۰۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر میں شک کرے اور کھا پی لے اور بعد میں بھی پتہ نہ چلے تو اس کا روزہ صحیح ہے یہاں برات جاری ہو گی چونکہ یہاں قضا کے لئے ہی موضوع محرز نہیں ہوا ہے تو کفارہ کیسے واجب ہو سکتاہے؟( اس لیے کہ وہ شخص جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا روزہ قضاء ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس پر قضا اور کفارہ کیسے آسکتاہے)
۱۱۔ اگر کوئی شخص غروب افتاب میں شک کرے تو اس کے اوپر کھانا پینا حرام ہے کیونکہ استحباب موضوعی (روزہ باطل) دن کے باقی ہونے پر دلالت کرتا ہے
۱۲۔ اس پر قضا اور کفارہ واجب ہے کیونکہ اصل استصحاب کے ساتھ وجدان کے ملانے کے ساتھ ان دونوں کا موضوع ثابت ہوچکا ہے ۔ لہذا اصل برات جاری کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔
۱۳۔ روزہ توڑنے کی نیت کرے لیکن روزہ نہ توڑے تو اس پر قضا اس لئے واجب ہے کہ اس کی نیت میں تسلسل نہیں رہا (یعنی عبادت میں اول سے لیکر آخر تک وہی اس نیت پر باقی رہنا چاہیے اور درمیان میں یہ سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ۔ یہاں پر طلوع فجر سے غروب تک روزے کا وقت ہے لہذا اس دوران اسی نیت پر باقی رہنا چاہیے تھا حالانکہ اس نے وہ نیت درمیان میں توڑی دی ہے اور تسلسل باقی نہیں رہا ہے۔)کیونکہ اس نے واجب کو قصد قربت کے ساتھ ادا ہی نہیں کیا ہے۔ اور چونکہ اس نے روزہ نہیں توڑا ہے جو کہ کفارہ کا موضوع ہے لہذ ا اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔
۱۴۔ اگر کوئی روزہ دار نیت کو آخر وقت تک برقرار نہ رکھ سکے تو اس کو روزے کی قضاء کرنی پڑے گی اس وجہ سے کیونکہ اس نے واجب کو انجام نہیں دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قصد قربت سے آپ نے آپ کو روکا ہے ۔
اعتکاف کے احکام
اعتکاف کی تعریف: عبادت کی قصد سے مسجد میں ٹھرنے کو اعتکاف کہتے ہیں اعتکاف مستحب مؤکدہ ہے اور اعتکاف صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ روزہ رکھے اور روزہ بھی تین دن سے کم نہ ہو اور اس کے لیے روزے کی حالت میں جامع مسجد میں ٹھرنا واجب ہے
اور معتکف کے لیے آپ نی عورتوں کے ساتھ جماع کرنا اور خوشبو (عطر) سونگھنا یا پھولوں کو لذت کے ساتھ سونگھنا اورخریدو فروخت کرنا اور ایک دوسرے پرغلبہ حاصل کرنے کی غرض سے دینی یا دنیوی اُمور پر بحث و مباحثہ کرنا اورضرورت کے علاوہ مسجد سے نکلنا ،جائز نہیں ہے۔اگر مسجد سے نکلے تو اسے سایے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔
دلائل
لغت میں اعتکاف کی تعریف:
۱۔ لغت میں اعتکاف کی تعریف: اعتکاف لغت میں ایک جگہ پر ٹھرنے کو کہتے ہیں
اصطلاح میں اعتکاف کی تعریف:
عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھرنے کو اعتکاف کہتے ہیں .اعتکاف کی اس تعریف پر تمام علماء کا اتفاق ہے اس پر داود بن سرحان کی امام صادق علیہ السلام سے روایت کردہ اس صحیح حدیث سے مدد لی جاسکتی ہے:
"وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ: وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ "(۴۴)
ترجمہ : " {حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }داؤد بن سرحان سے اور وہ حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نےایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ معتکف کو چاہیے کہ وہ کسی خاص ضروری کام کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکلے اورجب تک وپ وآپ س لوٹ نہیں آتا اُسے سایے میں نہیں بیٹھنا چاہیے ۔
لہذا مسجد میں ٹھرنا اعتکاف کہلاتاہے۔
اعتکاف صرف مسجد میں
ہاں ' اختلاف اس بات میں ہے کہ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھرنا ہی کافی ہے یا دُعا اور اس جیسی دوسری عبادات کے لئے اسے الگ سے نیت کرنے پڑے گی؟ پہلے بات بعید نہیں کیونکہ مذکورہ بالا صحیح حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔بلکہ اس سے زیادہ پر دلیل کا نہ ہونا ہی ا س کے معتبر ہونے کے لئے کافی ہے۔
۲۔ اعتکاف کا مسجد میں ہونا ضروری ہے کیونکہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور اس پر روایت بھی دلالت کرتی ہے جیساکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:
"مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْحَدِيث (۴۵)
ترجمہ : "}حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ آپ نی اسناد کےساتھ {حلبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں: اعتکاف نہیں ہوتا مگر روزہ کے ساتھ اور وہ بھی جامع مسجد میں "
ابن بابویہ کا حلبی کی طرف نسبت دینا " مشیخہ " میں صحیح ہے۔
۳۔ اعتکاف کے مستحب مؤکدہ ہونے پر دو دلیل ہیں
ا ۔ انبیاء علیہم السلام کو بیت الحرام کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کرنے کا حکم دینا ۔
جیساکہ خداوندہ متعال قرآن مجید میں فرماتے ہیں :
( وَ عَهِدْنَا إِلىَ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتىِ لِلطَّائفِينَ وَ الْعَاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (۴۶)
ترجمہ:"اور ابراہیم علیھ السّلام و اسماعیل علیھ السّلام سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوںاو ر رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو"
ب۔ حدیث :
"وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْن "(۴۷)
ترجمہ : " سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ آپ نے آباء طاہرین علیہم السلام کے سلسلہ سند سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سےروایت کرتے ہیں فرمایا : ماہ رمضان میں ایک عشرہ اعتکاے بیٹھنا دو حجوں اور دو عمروں کے برابر ہے "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات میں بھی اس کا ذکر ہے ۔
راوی سکونی کی سند اس روایت میں ثقہ ہے کیونکہ شیخ طوسی نے کتاب عدہ میں خبر واحد کی حجیت کی بحث پر اجماع کیا ہے اور اس کی روایت پر عمل کیا ہے ۔
اعتکاف کی پہلی شرط
۴۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے شرط روزہ ہے جیساکہ روایت صحیح حلبی وغیرہ سےیہ بات ثابت ہوتی ہے۔
اعتکاف کی دوسری شرط
۵۔ اور اعتکاف کےتین سے کم نہ ہونے پر دلیل عمر بن یزید کی حضرت امام صادق علیہ السلام سےموثق روایت ہے:
"عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْحَدِيثَ "(۴۸)
ترجمہ : " عمر بن یزید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ : اعتکاف تین دن سے کم نہیں ہوتا "
روایت میں محمد بن علی سے مراد ابن محبوب اشعری قمی ہے جس پر روایت میں حسن بن محبوب قرینہ ہے اور یہ روایت ثقہ ہے پس بے شک محمد بن علی بن محبوب سے کثیر تعداد میں روایات نقل ہوئی ہیں۔
اعتکاف کی تیسری شرط
۶۔ اعتکاف میں مسجد کا جامع ہونا ضروری ہے۔ یہ بات فقہاء میں معروف ہے۔اگرچہ بعض نے مساجد کوصرف چار مسجدوں {مسجد الحرام،مسجد النبی،مسجدکوفہ،مسجد بصرہ}میں منحصر قرار دیاہے۔جبکہ بعض دیگر نے کہ مسجد کے جامع ہونے کے لیے یہی کافی ہےاُس میں ایک بار صحیح نمازجماعت منعقدہوچکی ہو۔فقہاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف کا منشا(سرچشمہ) اس بارے میں پائی جانے والی روایات ہیں۔جوکہ مندرجہ ذیل ہیں :
ا۔روایت صحیح حلبی مسجد جامع کا عنوان ذکر ہوا ہے
ب۔ اور عمر بن زید کی صحیح روایت میں مسجد کا وہ عنوان ذکر ہوا ہے کہ جس مسجد میں فقط ایک دفعہ نماز جماعت صحیح منعقد ہوئی ہو جیساکہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
"وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ- فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ- وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ "(۴۹)
ترجمہ : "مر بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بغداد کی بعض مساجد میں اعتکاف بیٹھنے کے بارے مین کیا فرماتے ہیں ؟فرمایا : اعتکاف نہیں ہوتا مگر اس جماعت والی مسجد میں جس امام عادل نے نماز باجماعت پڑھائی ہو اور مسجد کوفہ و بصرہ ، مسجد مدینہ اور مسجد مکہ میں اعتکاف بیٹھنے میں مضائقہ نہیں ہے "
ج۔ اور روایت عمر بن زید سے مسجد کا عنوان چہار مسجدوں کو دیا گیا ہے اور بعض نے گمان کیا ہے کہ روایت میں امام عادل سے مراد امام معصوم علیہ السلام ہیں اور اسی پر ان کا عقیدہ ہے کہ فقط چہار مسجدوں (مسجد الحرام "مسجد النبی "مسجد کوفہ "مسجد بصرہ ) میں اعتکاف صحیح ہے کیونکہ امام معصوم علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی ہے لیکن روایت میں امام عادل سے مراد تمام امام جماعت (عادل) ہیں پس ہر وہ مسجد جہاں پر نماز جماعت منعقد ہوئی ہو تو وہاں پر اعتکاف صحیح ہے
نتیجہ: حاصل بحث یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کی روایات ہیں
ا ۔ عنوان مسجد جامع کافی ہے اگرچہ اس مسجد میں نماز جماعت برپا نہیں ہوئی ہو
ب۔ اس مسجد میں نماز جماعت منعقد ہوئی ہو اگرچہ اس مسجد پر جامع مسجد کا عنوان صدق نہ کرے
ممکن ہے کہ جامع سے مراد جامع مسجد ہو کہ جہاں پر نماز جماعت صحیح درست طریقے سے منعقد ہوئی ہو یعنی نماز جماعت کی جامع مسجد تھی نہ یہ کہ شہر میں جامع مسجد سے معروف ہو اور وہاں پر نماز جماعت برپا نہ ہو ہاں مگر احتیاط یہ کہ مسجد جامع میں اعتکاف صحیح ہے اور اس مسجد میں نماز جماعت بھی منعقد ہوئی ہو اور اس سے بھی احتیاط یہ ہے کہ اعتکاف چہار مسجدوں منعقد ہو ۔
اعتکاف کی چوتھی شرط
۷ ۔ اعتکاف میں آپ نی بیویوں کے ساتھ نزدیک ہونا جائز نہیں ہے جیساکہ خداوندہ متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں :
( وَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنتُمْ عَكِفُونَ فىِ الْمَسَاجِدِ ) (۵۰)
ترجمہ:" اور خبردار مسجدوںمیں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے مباشرت نہ کرنا۔یہ سب مقررہ حدود الٰہی ہیں ۔ان کے قریب بھی نہ جانا"
اورروایت میں بھی امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں : کہ
"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ "(۵۱)
ترجمہ : { حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ} حسن بن جہم سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا اعتکاف والا آدمی آپ نی زوجہ سے مقاربت کر سکتا ہے ؟ فرمایا : جب تک حالت اعتکاف میں ہے آپ نی زوجہ کے پاس نہیں جا سکتا خواہ رات ہو اور خواہ دن ۔ "
اعتکاف کی پانچویں شرط
۸ ۔ مباشرت کرنا آپ نی بیوی کے ساتھ حرام ہے جو کہ اعتکاف کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اعتکاف کرنے والا اس میں مقصر ہے (دلیل حرمت اس کے پاس نہیں ہے)اور اصل براءت مباشرت کے تمام انواع میں جاری ہو گی ۔
اعتکاف کی چھٹی شرط
۹ ۔ عطر اور پھل کا سونگھنا جائز نہیں ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيع (۵۲)
ترجمہ : "{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }ابو عبید سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو وہ خوشبو نہ سونگھے اور نہ ہی ریحان سے لطف اندوز ہو ۔ نہ کسی سے جھگڑا کرے اور نہ ہی خرید وفروخت کرے "
۱۰ ۔ عطر اور پھول کو لذت کے ساتھ سونگھنا بھی جائز نہیں ہے پس اس پر دلیل انصراف ہے اور عطر کو خود با خود سونگھنا لذت کا ملازمہ ہے اور پھول کے سونگھنے کے بارے میں روایت میں قیدلذت پر تاکید کی گئی ہے یعنی پھول اور عطر سے لذت لینا مساوی ہے اسی بناء پر دونوں سے روایت میں نہی کی گئی ہے
اعتکاف کی ساتویں شرط
۱۱ ۔ اعتکاف میں خرید وفروخت اور بحث و مباحثہ کرنا جائز نہیں ہے جیساکہ امام صادق علیہ السلام نے اوپر والی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے ۔
۱۲۔ اس قصد سے بحث و مباحثہ کرنا کہ ایک دوسرے پر غالب ہونا ہو چاہے دین کے لیے ہو یا دنیا کے لیے ہو جائز نہیں ہے ہاں اگر باطل کو جھٹلانے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے اس پر دلیل انصراف ہے جوکہ روایت میں نہی کی گئی ہے
۱۳ ۔ اور اعتکاف کے دوران مسجد سے خارج ہونا جائز نہیں ہے مگر جو پہلے روایت میں ذکر ہو چکے ہیں جیساکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ {حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }داؤد بن سرحان سے اور وہ حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نےایک حدیث کے ضمن میں فرمایا کہ معتکف کو چاہیے کہ وہ کسی خاص ضروری کام کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکلے اور اگر نکلے تو پھربیٹھے نہ جب تک وآپ س نہ لوٹ آئے اورعورت کا حکم بھی یہی ہے ۔
کتاب زکات
زکات کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟
زکات نو چیزوں پر واجب ہوتی ہے :تین جانوروں پر:(۱ ۔ اونٹ ۲ ۔گائے ۳ ۔ بھیڑ )نقدی پر :(۴۔ سونا ۵۔ چاندی )غلات پر(۶ ۔گیہوں ۷ ۔جو ۸ ۔کھجور ۹ ۔ کشمش)
دلائل:
۱ ۔ فضیل(۵۳) کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اورحضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِك "(۵۴)
"ترجمہ :"{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }زرارہ ، محمد بن مسلم ، ابو بصیر ، برید بن معاویہ عجلی اور فضیل بن یسار سے اور یہ سب حضرات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : خدا وند عالم نے نماز کے ساتھ ساتھ مال میں بھی زکوۃ فرض کی ہے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو چیزوں میں مقرر کی ہے ۔ اور وہ چیزیں یہ ہیں ۱ ۔ سونا ، ۲۔ چاندی ، ۳ ۔ اونٹ ، ۴ ۔ گائے ،بھینس ، ۵ ۔ بھیڑ، بکری ، ۶ ۔ گندم ، ۷ ۔ جو ، ۸ ۔ کھجور ، ۹ ۔ خشک انگور ۔ اور ان کے علاوہ باقی چیزوں سے زکات معاف کی گئی ہے
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں ۔
اور اس روایت کے مقابلے میں محمد بن مسلم کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهَا قَالَ ع الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُه "(۵۵)
ترجمہ " محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان ( حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام میں سے ایک امام )سے سوال کیا کہ کن دانوں سے زکوۃ دی جاتی ہے ؟ فرمایا : گندم ، جو ، مکئی ، باجرا ، چاول ، بے چھلکے کے جو ، مسور اور تل یہ سب اور ان جیسے دانوں کی زکوۃ دی جاتی ہے ۔
مذکورہ بالا دو روایتوں میں ظاہری طور پر ٹکراؤ پایا جاتاہے۔ لیکن ان دونوں روایتوں کواس طرح سے جمع کیا جاسکتاہے کہ دوسری حدیث کو استحباب پر حمل کردیا جائے(یعنی پہلی والی روایت میں وہ چیزیں بیان ہوئیں ہیں کہ جن میں زکوۃ واجب ہے ۔ جب کہ دوسری روایت میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جن میں زکواۃ مستحب ہے۔)
زکات کے عام شرائط :
زکات واجب نہیں ہوتی مگر یہ اس میں مندرجہ ذیل شرطیں پائی جاتی ہیں :
۱۔مال کا مالک بالغ ہو۔
۲۔ عاقل ہو۔
۳۔ آزاد ہو
۴۔ مالک ہو۔
۵۔ مال کے استعمال کرنے پر قادر ہو۔
۶۔ مال حد نصاب تک پہنچ گیا ہو ۔
زکات واجب ہونے کی شرائط اور ان کے دلائل
۱۔ بالغ ہو
نقدین یعنی سونے اورچاندی میں "بالغ" ہونے کی شرط متفق علیہ ہے ۔جبکہ ان کے علاوہ باقی میں اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتاہے۔
بلوغ کے مطلقا ( چاہے زکوۃ ہو یا زکوۃ کے علاوہ دیگر واجبات ، چاہے سونا چاندی ہو یا ان کے علاوہ دیگر اشیاء پر) شرط ہونے کو ممکن ہے کہ حدیث " رفع قلم " سے بھی ثابت کیا جا سکتاہے۔ اور جن لوگوں نے یہ دعوی کیا ہے کہ یہ حدیث رفع "احکام تکلیفیہ" کے ساتھ خاص ہےاور احکام وضعیہ کو شامل نہیں ہوتا ہے حدیث رفع کا طلاق پر دلالت کرنے کے بعد کوئی اس دعوی کی وجہ پائی نہیں جاتی ہے ۔
(اشکال : یہ حدیث اہل سنت سے نقل ہوئی ہے اور یہ استدلال کے قابل نہیں ہے )
جواب: اس حدیث کی سند کے ضعف کا جبران اس حدیث پر عمل کرنے کی شہرت سے ہوجاتاہے۔اوراس کی دلیل "قاعدہ کبری الانجبار"(۵۶) ہے جیساکہ مشہور ہے۔
۲۔عاقل ہو
عقل کے شرط ہونےکے لیے دو دلیلیں ہیں :
ا ۔ عقل کو ثابت کرنے لیے حدیث رفع(رفع القلم)(۵۷) کافی ہے یعنی پاگل پر زکات واجب نہیں ہے
ب ۔ اگر حدیث رفع سے چشم پوشی کریں تو قاصر مقتضی کے لیے زکات کے دلائل کافی ہیں کیونکہ وجوب زکات حکم تکلیفی پر دلالت کرتے ہیں پس پاگل پر زکات واجب نہیں ہوتی ہے
اور اس بات کی توجیہ اس طرح سے کرنا کہ یہاں بچے اورمجنون کے مال پر زکوۃ واجب ہے اور اب ان کے مال سے زکات نکالنا ان کے سرپرست اورولی کی ذمہ داری ہے۔ توجیہ کا جواب یہ ہے بچے اورمجنون کے سرپرست کے لئے اس قسم کے حکم اور تکلیف میں شک ہے ۔ اور جب اصل تکلیف میں شک ہو تو وہاں اصالۃ البراۃ جاری ہوتی ہے( لہذا یہاں پر بھی یہ جاری ہوگی اورحکم دیا جائے گا کے ان کے ولی اور سرپرست پر بھی زکوۃ واجب نہیں ہے۔)
۳۔ آزاد ہو
غلام پر زکات واجب نہیں ہے اس کی دلیل عبد اللہ بن سنان کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے:
"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ مَالِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْ ء"(۵۸)
ترجمہ: "عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک غلام ہے اور اس کے پاس کچھ مال ہے آیا اس پر زکوۃہے ؟ فرمایا : نہیں ۔ پھر عرض کیا : آیا اس کے مالک پر ہے ؟ فرمایا : نہیں اگرچہ "
اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں ۔
یہ قول اس پر مبنی ہے کہ غلام مالک ہو ا جیساکہ مروی صحیح سے ظاہر ہے اور اگر مالک نہ ہو تو پس مسئلہ روشن ہے ۔
یہ بات اس صورت میں درست ہے اگرغلام کو مالک مانا جائے جیساکہ مذکورہ روایت کے ظاہر سے بھی یہی سمجھ آتا ہے اور اگر اس دلیل کو نہیں مانے تو زکات غلام پر واجب
نہیں ہوتی ہے کیونکہ غلام کا مالک ہونا ثابت ہی نہیں تو زکات کس طرح واجب ہوگی ۔
۴ ۔ مالک ہو
زکات کے واجب ہونے میں سے ملکیت کی شرط مسلمات میں سےہے یعنی مکلف تین جانوروں کا (اونٹ، گائے ، بھیڑ) اور غلات کا(گیہوں ،جو ،کھجور ،کشمش)اور نقدی مال کا(سونا، چاندی) مالک ہو تب اس پر زکات واجب ہو گی پس اسی بنآپ ر مندرجہ ذیل موارد میں زکات واجب نہیں ہوتی ہے ۔
ا۔واھب جس شخص نے ھبہ کیا ہو اور موھوب جس کو ہبہ دیا ہے اس نے ہبہ والی چیز کوقبضے میں نہیں لیا ہے تو اس صورت میں زکات واجب نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی شخص نے گذشتہ سال چالیس بکریاں ھبہ کی تھیں اور جس شخص کو ھبہ کی تھیں اس نے قبول بھی کیا تھا لیکن ابھی تک جس نے ھبہ کیا تھا اس کو وہ بکریاں نہیں دی ہیں پس جس کو ھبہ دیا ہے وہ مالک نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں ھبہ دینے والے پر زکات واجب ہوتی ہے۔
ب ۔ اگر کوئی (موصی بہ )وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد (موصی لہ )فلان شخص کو وہ باغ دے دینا اور اس شخص نےایک سال گذرنے کے بعد بھی وصیت کو قبول نہیں کیا ہے تو اس صورت میں جس کو وصی بنایا ہے اس پر زکات واجب نہیں ہے کیونکہ ابھی تک وصی مالک نہیں ہے ۔
ج ۔ مباحات عامہ وہ مال ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہے "مثال کے طور پر صحراء میں بہت زیادہ حیوانات اور کھجور کے درخت موجود ہیں اور ان کا کوئی مالک نہیں ہے" پس اس صورت ان تمام اموال پر زکات واجب نہیں ہو گی
د ۔ وقف شدہ چیزوں پر زکات واجب نہیں ہوتی ہے " مثال کے طور پر اگر کوئی شخص باغ کو دوسروں کے لیے وقف کرے تو جن کے لیے وقف کیا ہے ان پر زکات واجب نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں اور جو کچھ باغ میں ہے وہ وقف کرنے والے کے لیے ہے" پس اس پر زکات واجب ہے جس نے وقف کیا ہے
ملکیت کے شرط کے لیے دو دلیل بیان کی گئی ہیں :
ا ۔ قران پاک میں ملکیت کے شرط کے لیے آیت میں ذکر کیا گیا ہے جیساکہ خدا وندہ منان ارشاد فرماتے ہیں:
( خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ) (۵۹)
ترجمہ :"(اے رسول)آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجیے،اس کے ذریعے آپ انھیں پاکیزہ اور با برکت بنائیں"
ظاھرا مال کاعنوان (اموالھم)اس صورت میں صادق آتا ہے جب مال کی ملکیت شخص کے لیے ہو ۔
ب ۔ اگر کوئی مال کسی کی ملکیت نہ ہو اور شک کرے کہ اس پر زکات واجب ہے یا نہیں تو اس صورت میں اصل براءت کا قاعدہ جاری ہو گا یعنی اس مال پر زکات واجب نہیں ہے کیونکہ حکم میں شک کرنا موضوع کے شک کرنے کا باعث بنتا ہے ۔
۵۔تصرف کی قدرت
مال میں تصرف کی قدرت کی شرط مسلمات میں سے ہے پس اسی بنا ءپر اموال شبیہ ومشکوک پر زکات واجب نہیں ہوتی ہے جوکہ مندرجہ ذیل ہیں :
ا ۔ وہ مال جو کسی نے چوری کیا ہوہے اور معلوم نہیں ہو ہے کہ ابھی وہ مال کہاں ہے اگرچہ ابھی تک اس چوری کے مال کی ملکیت باقی ہو ہے ۔
ب ۔ اگر اموال کسی اور کےپاس ہاتھ میں ہے اور مالک حقیقی کو بھی جانتا ہوہے لیکن اس شخص کے پاس کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہوہے کہ ثابت کرئے کہ یہ مال اس کا ہے جس کے پس مال ہے وہ شخص اس کی ملکیت سے انکار کر رہا ہے جیساکہ زرارہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے موثق روایت ہے :
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ "(۶۰)
ترجمہ :" زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا : جس کا مال غائب ہو کہ جب تک اسے آپ نا مال وآپ س نہ مل جائے تب تک اس پر زکوۃ نہیں ہے اور جب مل جائے تو صرف ایک سال کی زکوۃ ادا کرے گا اور اگر وہ اس غائب مال کو وآپ س لینے پر قدرت رکھتا تھا مگر عمدا نہیں لیا تو پھر ہر سال کی زکوۃ ادا کرے گا "
شیخ طوسی نے روایت ابن فضال کی کتاب سے نقل کیا ہے شیخ طوسی اور ابن فضال کے درمیان ۳۰۰ سال کا فاصلہ ہے اور سند کو کتاب مشایخ اور کتاب تھذیب میں لائی ہے اور یہ سند علی بن محمد بن زبیر پر مشتمل ہے جو کہ موثق نہیں ہے پس روایت قابل استدلال نہیں ہے مگر یہ کہ مشایخ نے علی بن محمد بن زبیر سے روایت نقل کرنے کی اجازت دی ہے بس ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اس روایت کو ثقہ جانے کیونکہ اجازت ایسے افراد سے ہے اگر ثقہ نہ جانے تو یہ لغو وفضول ہے ۔
زکات کا نصاب :
پس اگرچہ یہ شرائط عمومی میں سے ہے مگر بے شک اختلاف کمیت میں ہے کہ جن چیزوں پر زکات واجب ہوتی ہے پس ابھی شرائط خصوصی سے بحث کرتے ہیں ۔
حیوانات پر زکات واجب ہونے کی شرائط
حیوانات پر زکات واجب ہونا عمومی شرائط کے بعد ہے اور شرائط خصوصی مندرجہ ذیل ہیں :
ا۔ اونٹ کے بارہ نصاب پائے جاتےہیں ۔
۱ ۔پانچ اونٹوں پر ایک عدد بھیڑ
۲ ۔دس اونٹوں پر دو عدد بھیڑیں۔
۳ ۔ پندرہ اونٹوں پر تین عدد بھیڑیں۔
۴ ۔ بیس اونٹوں پر چار عدد بھیڑیں ۔
۵ ۔ پچیس اونٹوں پر پانچ عدد بھیڑیں۔
۶ ۔ چھبیس اونٹوں پر ایک (بنت مخاص )اونٹ کا بچہ جس کا ایک سال کامل ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو گیا ہو ۔
۷۔ چھتیس اونٹوں پر ایک (بنت لبون )اونٹ کا بچہ جس کا دو سال کامل ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو گیا ہو۔
۸۔ چھتالیس اونٹوں پر یک (حقہ)اونٹ جس کا تین سال کامل ہو اور چوتھے سال میں داخل ہو گیا ہو ۔
۹۔ اکسٹھ اونٹوں پر ایک(جذعہ)اونٹ جوکہ پانچویں سال میں داخل ہو گیا ہو۔
۱۰۔ چھتر اونٹوں پر دو بنت لبون ۔
۱۱۔ ایکانوے اونٹوں پر دو حقہ۔
۱۲۔ ایک سو ایکیس اونٹوں میں سے ہر ایک پچاس پر ایک حقہ اور ہر ایک چالیس پر ایک بنت لبون زکات موجود ہے ۔
ب۔ گائے کے دو نصاب ہیں :
۱۔ تیس گائے پر ایک تبیع (وہ گائے جو کہ دوسرے سال میں داخل ہو)۔
۲۔ چالیس گائے پر ایک مسنہ(وہ گائے جو کہ تیسرے سال میں داخل ہو )۔
اگر ان دو نصابوں سے زیادہ ہو تو معاف ہے کیونکہ اس کے لیے ممکن ہے کہ ان دو نصابوں کے ذریعے سےحساب کرے اور جو دو نصابوں کے دومیان فاصلہ ہے اگر نصاب بعدی تک نہیں پہنچا تو تب بھی زکات معاف ہے۔
ج۔ بھیڑکے پانچ نصاب ہیں :
۱۔ چالیس بھیڑیں پر ایک بھیڑ زکات ہے۔
۲۔ ایک سواکیس بھیڑ وں پر دو بھیڑیں زکات ہیں ہے۔
۳۔ دوسو ایک بھیڑوں پر تین بھیڑیں زکات ہیں۔
۴۔ تین سو ایک بھیڑ وں پر چار بھیڑ یں زکات ہیں ہے۔
۵۔ چار سو اور اس سے زیادہ ہو تو ہر ایک سو کیلئے ایک بھیڑ زکات ہے ۔
ب۔ پورا ایک سال صحراء میں چرا ہو ۔
ج۔ اونٹ اور گائےپورا سال بیکار رہا ہو ۔
د۔ ایک مکمل سال مالک کے پاس رہا ہو اور مذکورہ بالا تمام شرائط بھی پائے جاتے ہوں :
دلائل
۱۔ اونٹ کے نصاب کےبارے میں زرارہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی موثق روایت ہے :
"زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشَرَةٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ بِوَاحِدَةٍ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ حِقَّة "(۶۱)
ترجمہ {حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : پانچ اونٹوں سے کم تر پر کوئی چیز واجب نہیں ہے ۔ ہاں البتہ جب پانچ ہو جائیں تب ان میں ایک بکری واجب ہے اور دس ( نو) تک ایک رہے گی ۔ اور جب دس ہو جائیں تو ان میں دو بکریاں واجب ہیں بعد ازاں پندرہ (چودہ ) تک دو رہیں گی اور جب پندرہ ہو جائیں تو تین بکریاں اور بیس میں چار اور جب پچیس(۲۵) ہو جائیں تو پانچ بکریاں واجب ہوں گی اور جب ایک عدد کا اضافہ ہو جائے ( یعنی چھبیس(۲۶) ہو جائیں تو پینتیس(۳۵) تک ایک 'بنت مخاص ' ( وہ اونٹ کا بچہ جو دوسرے سال میں داخل اور اس کی ماں حاملہ بننے کے قابل ہو ) واجب ہو گی اور اگر اس کے پاس بنت مخاص نہ ہو تو پھر نر ابن لبون اور جب ان میں ایک عدد کا اضافہ ہو جائے (چھتیس ہو جائیں ) تو پینتالیس(۴۵) تک تو ایک بنت لبون واجب ہو گی ۔ اور اگر ان میں ایک عدد کا اضافہ ہو جائے ( چھیا لیس بن جائیں تو ) ساٹھ ( ۶۰) تک ایک حقہ ( چوتھے سال میں داخل ہو اور حاملہ ہونے کے لائق ہو )واجب ہو گی اور اسے حقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب وہ سواری کے لائق ہو گئی ہے اور حاملہ ہونے کے بھیاور اگر اس میں ایک عدد کا اور اضافہ ہو جائق ( اکسٹھ(۶۱) ہو جائیں ) تو بچھتر(۷۵) تک ایک جذعہ ( جو پانچویں سال میں داخل ہو اور جس کے اگلے دانت گر جائیں )واجب ہو گی اور اگر اس میں ایک عدد کا اضافہ ہو جائے(چھتر(۷۶) ہو جائیں ) تو نوے(۹۰) تک دو بنت لبون واجب ہو گی ۔ اور اگر اس میں ایک عدد کا ہو جائے ( اکانویں (۹۱ ) اور ہو جائے ) تو پھر ایک سو بیس تک دو حقہ واجب ہو گی اور اگر ایک سو بیس پر ایک عدد کا اضافہ ہو جائے (ایک سو اکیس ہو جائیں ) اور اس کے بعد جس قدر زیادہ ہو جائیں تو ہر پچاس عدد پر ایک حقہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون واجب ہو گی "
اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
مگر صحیح فضیل(۶۲) میں زکات کی نصاب میں اختلاف پچیس اور چھبیس میں پایا جاتا ہے جیساکہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُم "(۶۳)
ترجمہ : "فضیل حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اونٹوں کی زکوۃ کے سلسلہ میں فرمایا : ہر پانچ اونٹ میں ایک بکری ہے یہاں تک کہ پچیس اونٹ ہو جائیں تو پھر ایک بنت مخاص ( وہ اونٹی کا بچہ جو ایک سال کامل کا ہو ، اور دوسرے سال میں داخل ہو ) ، پھر زائد میں کچھ نہیں ہے ۔ یہاں تک کہ پنتیس(۳۵) تک پہنچ جائے جب اتنی ہو جائیں تو ان میں ایک بنت لبون
( جو تیسرے سال میں داخل ہو )
زرارہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت اس طرح نقل ہوئی ہے :
"فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِين "(۶۴)
ترجمہ : "(جب پچیس(۲۵) ہو جائیں تو پانچ بکریاں واجب ہوں گی اور جب ایک عدد کا اضافہ ہو جائے ( یعنی چھبیس(۲۶) ہو جائیں تو پینتیس(۳۵) تک ایک 'بنت مخاص ' ( وہ اونٹ کا بچہ جو دوسرے سال میں داخل اور اس کی ماں حاملہ بننے کے قابل ہو ) واجب ہو گی ا) "
پس چھبیس اونٹوں پر ایک بنت مخاص زکات ہے
اور فضیل(۶۵) کی حضرت امام علیہ السلام سے مروی صحیح روایت اس طرح نقل ہوئی ہے :
"أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ "(۶۶)
ترجمہ :" (جب پچیس(۲۵) ہو جائیں تو پانچ بکریاں واجب ہوں گی اور جب ایک عدد کا اضافہ ہو جائے ( یعنی چھبیس(۲۶) ہو جائیں تو پینتیس(۳۵) تک ایک 'بنت مخاص)"
پس پچیس سے پینتیس تک ایک بنت مخاص زکات ہے اور یہاں تک نظر پہنچ جاتی ہے کہ صحیح فضلاء کی عبارت (و زادت واحدہ)اس عبارت کے بعد ساقط ہے اور اسی طرح روایت کے اخر تک ہے
۲۔ فضیل کی صحیح روایت گائے کے نصاب پر بھی دلالت کرتی ہے جیساکہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
"أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى السَّبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى الثَّمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى تِسْعِين "(۶۷)
ترجمہ : "{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ فضیل} حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : ہر تیس گایوں میں ( جو گائے کا پہلا نصاب ہے جبکہ کل دو ( ۲) ہیں اور اس سے کم پر کچھ نہیں ہے ) ایک تبیع ( ایک سال سے دو سال تک کا بچھڑا ) واجب اور ہر چالیس گایو ں میں ( جوکہ دوسرا نصاب ہے ) ایک مسنہ ( وہ بچھڑا جو دو سال کا ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو یا تبیعہ ایک سال سے دو سال تک کی بچھڑی ) اور تیس و چالیس کے درمیان ( ۹ گایوں )پر کچھ نہیں ہے ۔ ہاں چالیس میں ایک مسنہ ہے پھر چالیس کے بعد ساٹھ تک ( ۱۹ گایوں پر ) پر کچھ نہیں ہے ۔ ہاں جب ساٹھ ہو جائیں تو ان میں دو تبیع ہیں پھر ستر تک ( نو گایوں پر کچھ نہیں ہے ) ہاں جب پورے ستر ہو جائیں تو ان میں ایک تبیع اور ایک مسنہ ہے پھر اسی ( ۸۰ ) تک (۰ ۹ )گایوں پر کچھ نہیں ہے ) ہاں جب اسی ( ۸۰ ) مکمل ہو جائیں تو پھر ہر چالیس میں ایک مسنہ ہے( یعنی کل دو مسنے ہیں )بعد ازاں نوے تک ( ۹۰ )گایوں پر کچھ نہیں ہے )"
۳۔ فضیل(۶۸) کی صحیح روایت بھیڑ کے پانچ نصاب پر بھی دلالت کرتی ہے اور یہ روایت بھی حضرت ا مام صادق علیہ السلام سے منقول ہے اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں :کہ
"أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشَّاءِ فِي كُلِ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ "(۶۹)
ترجمہ: "{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ فضیل }حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بکریوں کے متعلق فرمایا : ہر چالیس بکریوں میں ( جوکہ بکری کے پانچ نصابوں میں سے پہلا نصاب ہے )زکوۃ میں ایک بکری واجب ہے اور چالیس سے کم پر کچھ نہیں ہے ۔ اسی طرح چالیس کے بعد ایک سو بیس تک مزید کچھ نہیں ہے بلکہ وہی ایک بکری ہے ۔ ہاں جب اس میں ایک بکری کا اضافہ ہو جائے اور ایک سو اکیس ہو جائیں ( جوکہ ایک دوسرا نصاب ہے )تو پھر دو ( ۲ ) بکریاں واجب ہیں ۔ پھر دو ( ۲ ) سو تک مزید کچھ واجب نہیں بلکہ یہی دو بکریاں واجب ہیں ۔ ہاں البتہ جب اس میں ایک بکری کا اضافہ ہو جائے یعنی دوسوایک ہو جائیں (جوکہ تیسرا نصاب ہے )تو اس میں تین بکریاں واجب ہیں ۔ پھر تین سو تک مزید کچھ واجب نہیں بلکہ یہی تین بکریاں ہیں ۔ ہاں جب اس میں ایک کا اضافہ ہو جائے یعنی تین سو ایک ہو جائیں ( جوکہ چوتھا نصاب ہے ) تو پھر چار بکریاںواجب ہیں جو چارسو بکریوں تک باقی رہیں گی ۔اس کے بعد جب مکمل چارسو ہو جائیں تو پھر ہر سو بکری پر ایک بکری واجب ہو گی "
لیکن محمد بن قیس کی صحیح روایت بھیڑ کے چار نصاب پر دلالت کرتی ہے جیساکہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
"انها اذا بلغت ثلاثمأة و کثرت ففي کل مأة شاة "(۷۰)
ترجمہ :"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }محمد بن قیس سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : ہاں جب ان مین ایک کا اضافہ ہو جائے یعری تین سو تک تین بکریاں ہیں ۔ اور بعد ازاں جب بکریان زیادہ ہو جائیں تو پھر ہر ایک سو بکری میں ایک بکری واجب ہو گی "
پس اس روایت کا لازمہ بھیڑ کے پانچ نصاب سے انکار ہے پس اس بنا پر فضیل کی صحیح روایت کے مطابق ۳۰۱ سے لے کر ۴۹۹ تک چار بھیڑ زکات واجب ہے لیکن محمد بن قیس کی صحیح روایت کے مطابق ۳۰۰ سے لے کر ۴۹۹ تک تین بھیڑ زکات ہے اور اگر ان دو روایتوں کے درمیان تعرض مستقر ہو تو ان کو جمع کرنے سے دلالت ممکن نہ ہو توپس اس صورت میں
مناسب ہے کہ روایت محمد بن قیس کو چھوڑ دیں کیونکہ تقیہ کےموفق ( اہل سنت ) ہے۔
۴ ۔ اونٹ اور گائے سے کام لیا گیا ہو تو اس صورت میں زکات واجب نہیں ہے جس پر فضلاء فضل کی حضرت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَة "(۷۱)
ترجمہ "{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ فضیل }حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نےاونٹوں کی زکوۃ والی حدیث کے ضمن میں فرمایا : وہ حیوانات ( اونٹ و گائے ) جن سے کام لیا جائے ان پر زکاۃ نہیں ہے بلکہ صرف ان حیوانات پر ہے جو خود چراگاہ میں چریں۔ "
اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
پس فقط ان جانوروں پر زکات واجب ہے جو چرنے کے لیے جاتے ہیں ۔
۵ ۔ اگر حیوان پورا سال مالک کی ملکیت نہ ہو یعنی وہ حیوان بارہ مہینے میں داخل نہ ہو تو اس صورت میں مالک پر زکات واجب نہیں ہے پہلے والی روایت صحیح بھی اسی کے بارے میں ہے اور جیساکہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
"الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ "(۷۲)
ترجمہ :"{ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }فضیل بن یسار سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا: وہ اونٹ یا گائے جن سے بار برداری یا پانی کھینچنے یا ہل چلانےکا کام لیا جائے ان پر کچھ زکات وغیرہ نہیں ہے ۔ اور ہر وہ حیوان جسے مالک کے پاس سال نہ گزرے اس پر بھی کچھ نہیں ہے ہاں جب سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوۃ واجب ہو جائے گی "
اس کس علاوہ دوسری روایات بھی اس پ دلالت کرتی ہیں ۔
نقدی مال (سونا و چاندی)پر زکات واجب ہونے کے شرائط
نقدی مال پر زکات واجب ہونے کے لیےشرائط عمومی کے ساتھ ساتھ شرائط خصوصی بھی لازمی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
سونے کا نصاب
ا ۔ سونے (دینار) کا پہلانصاب بیس مثقال ہے اور بیس کے بعد ہر چار پر ایک نصاب ہے اور مقدار واجب ۱/۴۰مثقال سونا ہے اور چاندی کا پہلا نصاب دو سو درہم ہے اور دو سو کے بعد ہر چالیس درہم ایک نصاب ہے اور مقدار واجب ۱/۴۰ مثقال چاندی ہے ۔
ب ۔وہ سکہ (سونا و چاندی)جو بازار میں کسب ومعاملے میں رائج ہوں ۔
ج ۔ وہ مال جو مالک کے پاس ایک سال (یعنی بارویں مہینے میں داخل ہو)پڑا ہوا ہو ۔
دلائل
۱۔ دینار (سونے) کا نصاب بیس مثقال سے شروع ہوتا ہے اور ہر چار دینار جو اضافہ ہو جائے تو وہ بعدوالی نصاب میں داخل ہو جائے گا اور زکات کی مقدار ۱/۴۰ہے اور اس پر دس سے زیادہ روایاتیں پائی جاتی ہیں جیساکہ علی بن عقبہ کی اور بعض ہمارے اصحاب میں سے حضرت مام باقر علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی موثق روایت ہے :
"لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً "(۷۳)
ترجمہ:"علی بن عقبہ اور دیگر چند راوی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:بیس مثقال سونے سے کم تر پر زکوۃ واجب نہیں ہے ۔ اور جب پورے بیس مثقال ہو جائے تب نصف مثقال زکوۃ واجب ہے ۔ بعد ازاں جب تک چوبیس مثقال نہ ہو جائیں تو اس زائد مقدار پر زکوۃ نہیں ہے ۔ ہاں جب پورے چوبیس مثقال ہو جائیں تو اس میں ایک مثقال کے۳/۵ زکوۃ واجب ہے پھر جب تک اٹھائیس مثقال مکمل نہ ہو جائیں تب تک زائد مقدار پر کچھ نہیں ۔ پس اٹھائیس مثقال پر زکوۃ ہے اور اس کے بعد ہر چار مثقال پر زکوۃ ہے (اس سے کم پر نہیں ہے )
اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
دینار شرعی اٹھارہ چنے کے دانے کےوزن کے برابر ہے اور ۱/۴ و بیس مثقال پر آدھا دینار زکات ہے اگر چار مثقال اضافہ ہوجائیں تو اس کی زکات ۳/۵ ہو گی ۱/۱۰ + ۱/۴+۲۰= ۱/۲
لیکن ان دس روایتوں کے مقابلے میں اور روایات بھی ہیں جوکہ پہلے نصاب کو چالیس دینار مانتے ہیں جیساکہ فضیل(۷۴) کی حضرت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"فِي الذَّهَبِ فِي كُلِ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ "(۷۵)
ترجمہ :" فضیل بن یسار سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا:سونے کی ہر چالیس مثقال ( دینار ) میں ایک مثقال زکوۃ ہے ۔ اور چالیس مثقال سے کم پر کوئی چیز نہیں ہے "
ان دو طرح کی روایاتوں کو آپ س میں جمع کرنا یہ ہے کہ ظاہر کو نص پر حمل کرتے ہیں اس صورت میں کہ ان کے درمیان میں دلالت جمعی موجود ہو یعنی دوسری روایتیں ۲۰ سے ۴۰ دینار تک زکات کے واجب نہ ہونے کے قائل ونص وصریح ہے اور پہلی دس روایتیں زکات کے واجب ہونے کے بارے میں ظہور رکھتی ہیں لیکن اس حمل کا لازمہ یہ اتا ہے کہ حدفاصل ۲۰ سے ۴۰ تک کے درمیان اول روایت میں (ففیھا نصف مثقال) ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہو کیونکہ ضروری ہے کہ حد فاصل ۲۰ سے ۴۰ دینار کے درمیان تک استحباب کے قائل ہوں اور ۴۰ دینار سے زیادہ واجب کے قائل ہو جائیں تو ان کے درمیان عرف میں دلالت جمعی نہیں ہے اور دونوں روایتوں کا ایک دوسرے پر حمل کرنا محال ہے پس اس بنآپ ر ان کے درمیان ابتدائی تعرض نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان ثابت و مستقر ہے کیونکہ مستقر تعارض میں ایک کو ترجیح دینا ' سنت قطعی پر موافقت ہے پس اول روایت سنت قطعی ہے اس کو مقدم و ترجیح دی گئی ہے اور دوسری روایت کو بعید جانا گیا ہے ۔
چاندی کا نصاب
۲ ۔چاندی کا نصاب اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ { ۲۰۰ درھم (چاندی )سے کم پر زکات نہیں ہے اگر ۲۰۰ درھم تک پہنچ جائے تو اس صورت میں ۵ درھم زکات واجب ہے اور یہی مقدار ہے چاہے جتنا زیادہ ہو جائے اور ۲۴۰ درھم سے کم پر بھی ۵درھم زکات واجب ہے اور اگر ۲۴۰ درھم سے زیادہ ہو جائے تو ۶ درھم زکات واجب ہو جائے گی}زرارہ اور بکیر ابن اعین کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی موثق روایت ہے :
"فِي الزَّكَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَّا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سِتَّةُ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سَبْعَةُ الدَّرَاهِمِ وَ مَا زَادَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ كُلُّ ذَهَبٍ الْحَدِيث "(۷۶)
ترجمہ: "زرارہ امامین علیہما السلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا : چاندی جب تک دو سو درہم تک نہ پہنچ جائے اس پر کچھ نہیں ہے ۔ ہاں جب دو سو تک پہنچ جائے تو اس میں پانچ درہم زکوۃ ہے اور جب اس سے بڑھ جائے تو ہر چالیس درہم میں ایک درہم ہے اور ہر دہائی سے زائد مقدار ( انتالیس ) پر کچھ نہیں ہے "
اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس ٹر دلالت کرتی ہیں ۔
۳ ۔ وہ سکّہ (سونا و چاندی)جو بازار میں کسب ومعاملے میں رائج ہوں جیساکہ علی بن یقطین کی حضرت امام کاظم علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"علي بن يقطين عن أبي إبراهيم يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ قِيمَتُهُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عِنْدَكَ عَلَيْهِ حَوْلٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّة شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاة "(۷۷)
ترجمہ: " {حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }علی بن یقطین سے روایت
کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس بہت سارا مال قریبا سال تک پڑا رہتا ہے ۔ آیا اس کی زکوۃ دوں ؟ فرمایا : نہ جب تک پورا سال نہ گزر جائے اور جب تک وہ رکاز نہ ہو اس پر کوئی چیز نہیں ہے راوی نے عرض کیا کہ رکاز کیا ہے ؟ فرمایا : وہ سونا چاندی جس پر سکہ نقش ہو پھر فرمایا کہ اگر اس سے بیچنا چاہو تو اسے پگھلا دو کیونکہ سونے چاندی کے پگھلے ہوئے ٹکڑوں پر زکوۃ نہیں ہے "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
پس اسی بنآپ ر ہمارے زمانے میں سونا و چاندی پر زکات نہیں ہے کیونکہ بازار میں سونا وچاندی کے سکّوں پر معاملات رائج نہیں ہیں ۔
۴ ۔ وہ مال جو مالک کے پاس ایک سال (یعنی بارویں مہینے میں داخل ہو) سےپڑا ہوا ہو اس پر زکات واجب ہو گی اس پر دلیل علی بن یقطین کی مروی صحیح روایت مندرجہ بالا موجود ہے۔
غلّات پر زکات واجب ہونے کے شرائط
غلّات(گیہوں،جو،کھجور، کشمش) پر زکات واجب ہونے کے لیے شرائط عمومی کے ساتھ ساتھ شرائط خصوصی بھی لازمی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
ا ۔ ان کے نصاب کی مقدار پانچ وسق(اونٹ کا بار) ہے اور ہر وسق ۶۰ صاع کے برابر ہے اور اس کا وزن ۸۴۷ کلو گرام کے برابر ہے جبکہ زکات کی واجب مقدار ۱/۲۰ غلّات ہے
اگر زراعت کو موٹر وغیرہ سے ابیاری کی گئی ہو اور اس کے علاوہ زکات کی واجب مقدار ۱/۱۰ہے ۔
ب ۔ غلّات پر زکات اس وقت واجب ہو گی جب اس شخص کی ملکیت ثابت ہو اگرچہ اس شخص نے خود کاشت نہیں کیا(زراعت کو خریدا ہو ) ہو البتہ زکات کے واجب ہونے کے وقت میں اختلاف ہے ۔
دلائل
زمین سے اگنے والی چیزوں کے بارے میں دو قسم کی روایات پائی جاتی ہیں ۔
ا ۔ وہ روایت کہ جس میں نصاب کےپانچ وسق بیان کئےگئےہیں جو کہ ۳۰۰ صاع کے برابر ہیں ۔
ب ۔ اور وہ روایت جس میں نصاب کے ۶۰ صاع بیان کئےگئے ہیں ۔
{ایک وسق ۶۰ صاع کے برابر ہے اور ہر صاع ۱۱۷۰ درھم کے برابر ہے اور ہر درھم ۷/۱۰مثقال شرعی کے برابر ہے اور ہرمثقال شرعی ۳/۴مثقال صیرفی کے برابر ہے اور ہر مثقال صیرفی ۴/۶ گرام کے برابر ہے پس غلّات کا تقریبا ۶۶/۸۴۷کلو گرام ہے }
۱۔ وہ دلائل جو نصاب کی مقدار پردلالت کرتی ہیں وہ زیادہ روایات ہیں جو کہ دس سے بھی زیادہ ہیں جیساکہزرارہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَ الْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ، فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَ مَا كَانَ فِيهِ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ، وَ الدَّوَالِي، وَ النَّوَاضِحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَوِ السَّيْحُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْءٌ، إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاء "(۷۸)
ترجمہ: {حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }زرارہ سے اور وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : جو گندم ، جو ، خرما اور انگور زمین سے اگتے ہیں ۔ اور بمقدار پانچ وسق ہو جائیں جبکہ ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور یہ ہوئے تین سو صاع تو اس میں دسواں حصہ زکوۃ کا ہے اور جو اجناس رسیوں ( چھوٹے ڈولوں سے )اور ان سے بڑے ڈولوں سے جنہیں بیل یا اونٹ کھینچتے ہیں سیراب کئے جائیں ان سے بیسواں حصہ واجب ہو گا اور جو اجناس بارش کے پانی سے یا آب جاری سے سیراب ہوں یا جن کوپانی سے سے سیراب نہ کیا جائے بلکہ آپ نی آپ نی زیر زمین جڑوں سے تراوٹ حاصل کریں ان سے دسواں حصہ واجب ہو گا ۔ اور تین سو صاع سے کم ترمقدارپر کچھ نہیں ہے اور جو فصلیں زمین سے اگتی ہیں ان میں سوائے ان چار اجناس میں اور کسی چیز میں زکوۃ واجب نہیں ہے "
اور یہ حکم اوپر والی روایت کے مطابق ہے اوراس کے مقابلے میں حلبی کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ قَالَ فِي سِتِّينَ صَاعا "(۷۹)
ترجمہ: "عبید اللہ حلبی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ گندم ، جو ، انگور اور خرما کی کتنی مقدار پر زکوۃ واجب ہے ؟ فرمایا : ساٹھ صاع پر "(۸۰)
اور اگر ان دونوں روایاتوں کے درمیان عرفا جمع کرنا ممکن ہو تو دوسری روایت کو استحباب پر حمل کریں گے اور اس پر عمل کرنا ہو گا اور اگر ان کو عرفا جمع کرنا ممکن نہ ہو تو ان کے درمیان تعرض وجود میں آئی گی اور اس صورت میں لازمی ہے کہ دوسری قسم کی روایات کو چھوڑ دیں کیونکہ پہلی قسم کی روایاتیں زیادہ ہیں اور قطعی سنت کو تشکیل دیتے ہیں لہذا دوسری قسم کی روایاتیں قطعی سنت کی مخالفت میں ہیں پس ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔
پس اسی بنآپ ر ان دو روایاتوں کے درمیان تعرض ثابت و مستقر ہے اور پہلی روایت ترجیح رکھتی ہے کیونکہ اس طرح کی روایات زیادہ ہیں اور سنت قطعی ہے اور دوسری روایت کو بعید جانا گیا ہے ۔
غلات پر زکات واجب ہونے کی مقدار
۲ ۔ غلّات پر زکات واجب ہونے کی مقدار ۱/۲۰ و ( ۱)/۱۰ہے جس پر دلیل روایت زرارہ جو کہ اوپر بیان ہوئی چکی ہے ۔
۳ ۔ ملکیت کی دو قسمیں ہیں :
ا ۔ زراعت کے ذریعے سےملکیت کا حاصل ہونا ۔
ب ۔ خرید وفروخت کے ذریعے سے ملکیت کا حاصل ہونا ۔
زکات کے واجب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زراعت کے ذریعے سے مالک ہوا ہو پس زکات دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ زکات کے واجب ہونے کے وقت مالک ہو یعنی گیہوں اور جو پک جائے ' اور کھجور پیلے اور سرخ ہو جائیں ' اور کشمش یعنی انگور کچے ہوں اس وقت مالک ہو اور مالک ہونا زراعت کے وقت اور جو پکنے وپیلے وسرخ و انگور کے غورے کے بعد ہوتو زکات واجب نہیں ہے پس ضروری نہیں ہے کہ کاشت کاری کے وقت یا کھجور اور انگور کا مالک ہو پس اسی بنآپ ر اگر پکنے سے پہلے زراعت کی خریداری کرے تو زکات خریدار پر واجب ہو گی اور اگر اس کے علاوہ ہو تو زکات فروخت کرنے والے پر واجب ہو گی اور غلّات کو ےکاشت کرنے سے زکات واجب نہیں ہوتی ہے اس شرط کے نہ ہونے پر تنہا دلیل اجماع ہے اور روایات بھی عمومیت کے ثابت ہونے سے قاصر ہے کیونکہ اس مقام بیان پر نہیں ہے کہ اطلاق و عمومیت کو ثابت کرے جس پر تمام مسلمین کا اتفاق ہے۔
۴ ۔ زکات کے واجب ہونے میں مشہور اس بات کے قائل ہیں ہکہ جب گیہوں وجو پک جائیں اور کھجور پیلے یا سرخ ہو جائیں اور کشمش کا غورہ بن جائے تو اس وقت زکات واجب ہو گی لیکن بعض{صاحب کتاب عروۃ الوثقی محقق طباطبائی یزدی }کہتے ہیں کہ گیہوں و جو کے پکنے کے وقت کو زکات کے واجب ہونے کو نہیں جانا گیاہے بلکہ{ محقق} نے کہا ہے کہ جب گیہوں وجو پر عرف عام میں عنوان صدق آ جائے تو زکات واجب ہو گی اور روایت میں بھی عنوان صدق بیان ہوا ہے اور کھجور پر عنوان پھل صدق آ جائے یعنی پھل کھانے کے قابل ہوں جو کہ وہی کھجور کے پیلے وسرخ ہونے پر دلالت کرتی ہے اور کشمش میں بھی فقط عنوان انگور صدق آ جائے۔
اشکال :
اگر معیار و میزان صدق عنوان ہو تو پھر کیوں کشمش پر زکات واجب ہونے کے لیے انگور کے غورے کے پیدا ہونے کا وقت بیان کیا ہے مگر ورایت میں کشمش کا ذکر ہے ۔
جواب : زکات کے واجب ہونے کا دارو مدار انگور کے عنوان کا صدق ہونا ہے اگرچہ کشمش کا عنوان نصاب کے تحقق ہونے کے لیے ملاک ہے یعنی انگور کشمش ہو جائے اور پانچ وسق ہو تو اس صورت میں زکات واجب ہو گی کیونکہ سلیمان بن خالد کا مفاد بھی اسی طرح ہے جیساکہ امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے
"لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً "(۸۱)
ترجمہ : سلیمان بن خالد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : خرما میں زکات نہیں ہے جب تک پانچ وسق تک نہ پہنچ جائے اور یہی حکم انگوروں کا ہے جب تک خشک ہو کر پانچ وسق(۸۲) کو نہ پہنچ جائیں "
پس زکات کے واجب ہونے کا وقت اور نصاب کے مقدارتک پہنچے کے وقت کے علاوہ ہے۔
زکات کے مستحقین
زکات کے مصارف مندرجہ ذیل ہیں :
۱'۲ ۔ فقیر ومسکین :مسکین کی حالت فقیر سے بدتر ہے اگر فقیر احتیاج کا دعوی کرے اوراس کے دعوی پرپہلے علم ہو یا اطمینان حاصل ہو تو اس کی تصدیق جائے گی اور اس کو فقیر شمار کیا جائے گا اگرچہ اس کے بارے میں بچپن سے جانتے اور اس کے بارے میں اطلاع نہ ہو کہ ابھی بے نیاز ہو گیا ہے جیساکہ غالبااسی طرح ہے ۔
۳ ۔ وہ لوگ جو زکات کے جمع کرتے ہیں اور ان کا حساب کرتے اور مستحقین تک زکات پہنچاتے ہیں اور اسی طرح بہت سے امور جن کو انجام دینا ان پر لازمی کیے گئے ہیں پر مامور ہوں اورزکات کے مامورین کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں ہے ۔
۴ ۔ وہ مسلمان جن کا عقیدہ ایمان اسلام کےبارے میں ضعیف ہو تاکہ ان زکات دینے سے عقیدہ اسلام کی تقویت کا سبب بنے اور کہا گیا کہ کافروں کو بھی شامل ہوتی ہے اگر زکات دینے سے اسلام کی محافظت کریں اور اسلام کی طرف رغبت پیدا کریں ی یا کافروں سے جھاد کرے ۔
۵ ۔ غلام کو زکات دے سکتے ہیں تاکہ آپ نے آپ کو ازاد کروائے ۔ اورغلام مکاتب ہے یا غیر مکاتب اور مکاتب ہونے کی صورت میں مکاتب مطلق ہے یا مشروط ا ۔ تمام صورتوں میں مال کی طرف محتاج ہے تاکہ آزاد ہو جائے اگرچہ دین کی خاطر ہو یاسختی میں زندگی بسر کر رہا ہویا فقط آزاد ہونے کے لیے مال کی طرف محتاج ہو ۔
۶ ۔ وہ مقروض جو آپ نا قرضہ اداء کرنے سے عاجز ہو مگر اس شرط کے ساتھ کہ زکات کو معصیت میں استعمال نہ کرے ۔
۷ ۔ زکات کا استعمال کرنا تمام اعمال خیر میں جس میں خیر میں اور فقط جھاد کے ساتھ خاص نہیں ہے
۸ ۔ ابن سبیل کو دینا یعنی وہ مسافر جس کے پاس توشہ راہ تمام ہو گیا ہو ۔
زکات کے مصرف اور دلائل
۱ ۔ زکات کے استعمال کو محدود کرنا ان چیزوں میں جن کا ذکر ہو چکا ہے جس پر دلیل قرآن مجید کی آیت ہے جیساکہ خدا وندعالم فرماتے ہیں :
( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيهْا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمْ وَ فىِ الرِّقَابِ وَ الْغَرِمِينَ وَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم ) (۸۳)
ترجمہ :"یہ صدقات تو صرف فقیروں ' مساکین اور صدقات کے کام کرنے والوں کے لیے ہیں اوران کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو اور غلاموں کی ازادی اور قرضداروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک مقرر حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا ' حکمت والا ہے "
یہ آیت زکات کے استعمال ہونے پر دلالت کرتی ہے ۔
۱۔۲ فقیر اور مسکین
لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسکین کی حالت فقیر سے بدتر ہے جیساکہ محمد بن مسلم کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ "(۸۴)
ترجمہ :"{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ } محمد بن مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے امامین علیہما السلام میں سے ایک امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں ؟ ( اور ان میں باہمی فرق کیا ہے ) ؟ فرمایا : فقیر وہ ہے جو سوال نہیں کرتا ۔ مگر مسکین وہ ہے جو اس سے زیادہ مشقت میں ہے اس لیے وہ سوال کرتا ہے "
اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
مسکین اور فقیر میں فرق
مسکین کی حالت فقیر سے بدتر ہے کیونکہ فقیر وہ ہے جو گدائی نہیں کرتا ہے لیکن مسکین وہ ہے جو فقیر سے زیادہ تلاش کرتا ہے اور لوگوں سے مدد کی درخواست کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر لفظ فقیر ومسکین جملے میں استعمال ہوئےہوں تو اس کے معنی میں اختلاف ہو گا اور اگر جملے میں استعمال نہ ہوں تو اس کا مفہوم عام ہے دونوں کو شامل ہو جاتی ہیں
۲ ۔ اگر کوئی شخص فقیر ہونے کا دعوی کرے تو اس کا یہ دعوی دو دلیلوں سے ثابت ہو گا اور اس کو زکات دی جائے گی
ا ۔ اگر اطمینان ہو جائے کہ فقیر سچ کہہ رہا ہے کیونکہ اطمینان حجت عقلائی ہے اور شارع نے بھی اس سے منع نہیں کرتاہے پس فقیر کا دعوی قبول کیا جائے گا ۔
ب ۔ اور اگر اس کے دعوی پر اطمینان حاصل نہیں ہو تو اس صورت میں استصحاب کا قاعدہ جاری ہو گا کیونکہ اکثر وغالبا افراد تولد کے وقت فقیر ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی مال ومتاع نہیں ہوتا ہے اور اگر شک کریں کہ اس کا فقر غنی ہونے میں تبدیل ہوا ہے یا نہیں ؟ تو صورت میں استصحاب کا قاعدہ جاری ہو گا تو اس صورت میں اس کا فقر ہونا ثابت ہو جائے گا ۔
۳ ۔ عاملین
جس کی تفسیر جس کا معنی ذکر ہو چکا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ لفظ کے ظاہرپر اعتماد کیا ہے جوکہ اطلاق ہے اور اس دلیل کے واسطے سے روشن ہو جائے گا کہ عاملین کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں ہے اس دلیل کے علاوہ ممکن ہے کہ اس عاملین کے مقابلے میں اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں اور اس کو قرینہ مقابلے کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور عاملین کو جدا ذکر نہیں کیا گیا ہے ۔
۴ ۔مولفۃ قلوبہم
آیت کی تفسیر میں "ولمؤلفة قلوبهم " سے مراد مسلمان لیا گیا ہے { مستحقین کون سے لوگ ہیں ؟ ایا وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ضغیف ہے یا وہ لوگ جو کافر ہیں لیکن ان کے قلوب نرم کرنے کے لیے زکات دیتے ہیں تاکہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں یا وہ لوگ جو کافر ہیں لیکن مسلمانوں کی دفاع کرتے ہیں یا مسلمانوں کے نفع کے لیے کفار سے جھاد کرتے ہیں }جوکہ بعض روایات کی وضاحت کی مدد سے حاصل ہوتی ہے جیساکہ
زرارہ کی حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے:
"زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي ذَلِكَ شُكَّاكٌ فِي بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ ص أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ بِالْمَالِ وَ الْعَطَاءِ لِكَيْ يَحْسُنَ إِسْلَامُهُم (۸۵)
ترجمہ :"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ } زرارہ سے روایت بیان کرتے ہیں اور وہ حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کوتے ہیں ہیں کہ میں نے اس ایت (وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) کے بارے میں امام علیہ السلام سوال کیا ؟ فرمایا : سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی توحید کے تو قائل تھے اور خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کا جو آپ نی گردنوں سے اتار پھینکا تھا مگر ابھی ان کے دلوں میں یہ معرفت داخل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تالیف قلب کرتے تھے ان کو پڑھاتے لکھاتے اور معرفی کراتے تھے اور زکوۃ سے ان کو ایک حصہ دیتے تھے تاکہ وہ وہ (اسلام میں ) رغبت کریں اور رسالت کو پہچانیں "
اوراگر روایت کا اختصاص ظاہرا کامل ہو تو اس حالت میں صحیح روایت آیت کے اطلاق پر قید ہو جائے گی لیکن ظاہرا روایت کےاختصاص میں اشکال پایا جاتا ہے لہذا آیت اطلاق پر مستحکم ہے ۔
۵ ۔غلام
غلام کی تفسیر کسی حد تک گذر چکی ہے پس اس پر آیت کریمہ اطلاق کرتی ہے ۔
۶ ۔ مقروض
اگر مقروض قرض دینے سے عاجز ہو جائے تو وہ آپ نا قرضہ زکات سے دے سکتا ہے اگرچہ یہ شرط آیت کے اطلاق ہونے کے مخالف ہے اور عجز کی قید آیت میں بیان نہیں کی گئی ہے اور دوسری دلیلیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارایقین ہے کہ عاجز کو زکات حاصل کرنے کے لیے اس میں شرط جانتے ہیں ۔
وہ لوگ جو معصیت کے کاموں کی وجہ سے مقروض ہوئے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ۔
ا ۔ وہ لوگ جنہوں نے معصیت کی ہے لیکن توبہ نہیں کی تو ان کے لیے زکات کا استعمال آپ نا قرضہ لوٹانے کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اگر ان کو زکات دی جائے تو ان کی معصیت میں تقویت کا باعث بنتی ہے
ب ۔ وہ لوگ جنہوں نے معصیت کی ہے لیکن توبہ کر لی ہے تو پھر بھی احتیاط ہے کہ زکات کا استعمال نہ کرئے کیونکہ یہ ایک مسئلہ اجتماعی ہے پس ضروری ہے کہ اجماع کی مخالفت نہ کرے پس اسی بنآپ ر چاہے معصیت کرنے والے نے توبہ کی ہو یا نہیں کی ہو تو آپ نا قرضہ لوٹانے کے لیے زکات نہیں لے سکتا ہے۔
۷ ۔اللہ کی راہ
اللہ کی راہ میں تمام اعمال خیر میں زکات دینا اور یہ جھاد کے ساتھ خاص نہیں ہے جس پر آیت (انما الصدقات ) اطلاق کے ساتھ دلالت کرتی ہے
اشکال :بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دو دلیلوں کے ساتھ فی سبیل اللہ سے مراد فقط جھاد ہے
ا ۔ اطلاق ایت میں فی سبیل اللہ جھاد کو شامل ہوتی ہے
ب ۔ اخبار اور روایات ہمارے پاس ہیں جوکہ فی سبیل اللہ کی تفسیر جھاد سے کرتے ہیں پس اسی بنا پر زکات کو جھاد میں استعمال کر سکتے ہیں اور اسلام کی جنگ کافروں کے مقابلے میں زکات کو بھیجا جا سکتا ہے ۔
جواب : یہ تفسیر مستحکم نہیں ہے کیونکہ کثرت استعمال کی اثر کی وجہ سے انصراف حاصل ہوتا ہے اور فی سبیل اللہ فقط جھاد میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ فی سبیل اللہ اور بہت زیادہ موارد میں استعمال ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو اخبار و روایات بیان کی گئی ہیں ان کی سند ودلالت ضعیف ہے ۔
۹ ۔ ابن سبیل کو دینا ۔
جس کی تفسیر پہلے ذکر ہوئی ہے (یعنی وہ مسافر جس کے پاس توشہ راہ تمام ہو گیا ہو ) اور یہ اس کا لغوی معنی ہے ۔
مستحقین کے اوصاف
زکات وصول کرنے والے مستحقین کے شرائط مندرجہ ذیل ہیں :
۱۔ ایمان:
پس کافر اور سنی کو زکات نہیں دی جائے گی مگر ان کو (المؤلفة قلوبهم )یعنی دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اور (سبیل الله ) اللہ کی راہ میں دینا لیکن وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ دی جائے گی اور اگر سنی زکات کو غیر مؤمن کو دے لیکن بعد میں وہ شخص ولایت ائمہ کو قبول کرے تو اس صورت میں وہ شخص زکات کو وآپ س پلٹائے گا ۔
۲ ۔ زکات کے مستحق کو اہل معصیت نہیں ہونا چائیے
کیونکہ زکات دینے سے اس کو معصیت کرنے میں تقویت ملتی ہے اور معصیت کار شجاع ہو جاتا ہے ۔
۳ ۔واجب النفقہ نہ ہو
اس شخص کو زکات نہیں دی جائے گی جس کا نفقہ زکات دینے والے کے اوپر واجب ہو کیونکہ جائز نہیں ہے مگر ان موارد میں دیا جا سکتا ہ کہے جن موارد میں نفقہ واجب نہیں ہے ۔
۴ ۔ غیر سید ہو
اگر مستحقُ زکات سیّدہو اور زکات دینے والا غیر سیّد ہو تو اس صورت سیّد کو زکات نہیں دی جائے گی بلکہ سیّد کوسیّد زکات دے سکتا ہے اور سیّد کوواجب زکات دینا غیر سیّد کی طرف سے حرام ہے لیکن سیّد کو مستحب صدقہ وغیرہ دینا جائز ہے سیّد وہ ہے جس کا بآپ فقط سیّد ہو اور اس کی نسبت ہاشمیوں کی طرف دی جائے گی اور یہ نسبت ماں کی طرف سے نہیں ہے اور سیّد ہونا ثابت نہیں ہو گا مگریہ قسم ہو اور اس کے کلام سےاطمینان حاصل ہو ۔
دلائل
۱ ۔ زکات کافر اور سنی کو نہیں دی جائے گی کیونکہ برید بن معاویہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء "(۸۶)
ترجمہ :"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }برید بن معاویہ عجلی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک حدیث کےضمن میں فرمایا : ہر وہ عمل اور کام جو کوئی شخص آپ نی ناصبیت اور گمراہی کے دور میں بجالائے اور پھر خدائے منان اس پر احسان فرمائے اور اسے ولایت ( اہل بیت کی دولت) عطا فرمائے تو اسے سابقہ عہد کے بجالائے ہوئے اعمال پر اجر وثواب ملے گا ۔ سوائے زکوۃ کےکیونکہ وہ اسے بے محل صرف کرتا رہا ہے کیونکہ یہ اہل ولایت کے لیے ہے ( لہذا اس کا اعادہ کرنا پڑے گا ) لیکن نماز وحج اور روزہ کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے "
پس اسی روایت کی روح سے کافر کو اولیت کی بناء پر زکات نہیں دی جائے گی ۔
۲ ۔ اہل سنت فقراء کو (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) میں سےزکات دینا جائزہےکیونکہ(الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) کی تفسیر اہل سنت اور کافر بھی شامل ہو جاتی ہے جیساکہ پہلے کہا گیا ہے ۔
اہل سنت اور کافروں کو سہم (سبیل اللہ ) سے زکات دی جا سکتی ہے لیکن اگر زکات دینا سنی اور کافر کو مؤمن کی مصلحت کے لیے ہو تو یہ ایسا ہے جیساکہ حقیت میں آپ نے مؤمن کو زکات دی ہو ۔
۳ ۔ اور اگر سنّی شیعہ( مستبصر ) ہو جائے تو اس پر واجبات کی قضاء واجب نہیں ہے لیکن اس پر زکات واجب ہےجس پر دلیل برید بن معاویہ کی صحیح روایت ہے جو کہ پہلے ذکر ہو چکی ہے لیکن اگر زکات کو آپ نے لیے استعمال کیا ہو تو اس حالت میں اس پر زکات واجب نہیں ہےکیونکہ زکات کے پلٹانے کی دلیل منتفی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ پہلی والی صحیح روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے ۔
۴ ۔ اور اگر تمام زکات لینے والے مستحقین اہل معصیت ہوں تو ان کو پہلی والی شرط کے مطابق زکات نہیں دی جائے گی کیونکہ زکات دینا نہی از منکر کے وجوب کے خلاف ہے اسی طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کا با عث بنتی ہے اور معصیت کرنے میں ان کو دلیری اور شجاعت ملتی ہے کیونکہ معصّیت پر حوصلہ افزائی دین میں مبغوض اور نا پسندیدہ ہے ۔
۵ ۔ زکات دینا اس مستحق کو جس کا نفقہ اس کے اوپر واجب نہ ہو ا جس پر دلیل عبدالرحمن بن حجاج کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ "(۸۷)
ترجمہ :"{ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ } عبدالرحمن بن الحجاج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : پانچ اشخاص ایسے ہیں جن کو کچھ بھی زکوۃ نہیں دی جائے گی : ۱ ۔ بآپ ۲ ۔ ماں ۳ ۔ اولاد ۴ ۔ مملوک ۵ ۔ بیوی ۔ کیونکہ یہ اس کے ( واجب النفقہ ) عیال ہیں ۔ جو اس کے لیے لازم ہیں "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
لیکن دلیل استثناء یہ ہے جیساکہ انفاق کرنا قرضہ اداء کرنے کے لیے ۔ پس صحیح عبدالرحمن بن حجاج لازم نفقہ کے ساتھ خاص ہے اس کے بعد اطلاقات کے ساتھ تمسک کریں گے { مثلا از باب قرضہ یا سبیل اللہ زکات کو ماں بآپ یا قرضہ ادا کرنے کے لیے یا بآپ کے شادی کے اخراجات یا آپ نے فرزند کےتعلیم حاصل کرنے کے لیے زکات دے جو کہ اطلاقات قرآنی سے ثابت ہے لیکن قرضہ اور تعلیم کے حاصل کرنے کا خرچہ واجب نفقہ کے باب میں سے نہیں ہیں۔}
۶ ۔ مستحق سیّد ہو اور زکات دینے والا غیر سیّدہو تو اس صورت سیّدکو زکات نہیں دی جائے گی جس پر دلیل زرارہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے موثق روایت ہے :
"أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقَةُ الرَّسُولِ ص تَحِلُّ لِجَمِيعِ النَّاسِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَانٍ غَرِيبٍ "(۸۸)
ترجمہ "زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا بنی ہاشم میں سے بعض کا صدقہ دوسرے بعض کے لیے حلال ہے ؟ فرمایا : ہاں (پھر فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام لوگوں بنی ہاشم وغیرہ کے لیے جائز ہے اور ان میں سےبعض کے صدقات دوسرے بعض کے لیے جائز ہیں مگر کسی غیر (ہاشمی ) کے صدقات ان کے لیے جائز نہیں ہے "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
۷ ۔واجب زکات فقط سادات پر حرام ہے لیکن مستحب صدقات بلکہ تمام واجب صدقات جیساکہ کفارات اور ردمظالم اور لقطہ(وہ مال جو مل گیا ہو) حرام نہیں ہیں جس پر دلیل اسماعیل بن فضل ہاشمی کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے موثق روایت ہے :
"سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاة "(۸۹)
ترجمہ"اسماعیل بن فضل ہاشمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ صدقہ جو بنی ہاشم پر حرام ہے وہ کون سا ہے ؟ فرمایا : وہ ( لوگوں ) کی زکوۃ ہے راوی نے عرض کیا کہ آیا بنی ہاشم میں سے بعض کا صدقہ دوسرے کے لیے جائز ہے ؟ فرمایا : ہاں "
اور اس کے علاوہ اس دعوے کے ثبوت کے لیے مناسب قصور ہی کافی ہے کیونکہ موثق زرارہ میں صدقات کا لفظ واجب زکات میں انصراف ہے ۔
۸ ۔ اگر زکات غیر سادات کا ہو تو زکات سادات کو نہیں دی جائے گی اور کلام اس میں ہے کہ ہاشمی ہونا ماں کی طرف سے ہو تو ہاشمی ہے یا ہاشمی ہونا بآپ کی طرف سے ہو تو ہاشمی ہونا ثابت ہوگا چاہے اسکی ماں سیدہ ہو یا نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں دو نظریے ہیں جوکہ مندرجہ ذیل ہیں :
ا ۔ وہ شخص جس کا نہ والد سید ہو اور نہ والدہ سیدہ ہو تو وہ غیر ہاشمی ہے صاحب کتاب حدائق اور سید مرتضی کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا والد سید ہو یا والدہ سیدہ ہو تو وہ شخص ہاشمی ہو گا اور ان کی دلیل یہ ہے (ان ولد البنت ولد ایضا )(۹۰) کہ بیٹی کا بچہ بیٹے کے بچے کی طرح ہے پس جس کی ماں سیدہ ہو تو اس کا بچہ بھی ہاشمی ہو گا پس اس کے لیے لازمی ہے کہ غیر ہاشمی سے واجب زکات نہیں لے ۔
ب ۔ جس کا بآپ ہاشمی ہو تو اس کی نسبت ہاشمی کی طرف دی جائے گی ۔
اول نظریے پر اعتراض کیا گیا ہے اور ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ رسول ص کی بیٹی کی اولاد رسول ص کی اولاد ہیں اور قرآن میں حضرت عیسی علیہ السلام کو نسل ابراھیم علیہ السلام سے قرار دیا گیا ہے اگرچہ حضرت عیسی علیہ السلام کا بآپ نہیں تھا اور حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت حضرت ابراھیم علیہ السلام کی طرف دینا ماں کی وجہ سے ہے لیکن ہاشمی کا عنوان کلام میں صدق کرتا ہے جب اس کا بآپ ہاشمی ہو کیونکہ عربوں کے درمیان یہ رسم ورواج تھا کہ بیٹوں کی نسبت خاندان کی طرف دی جاتی تھی اور اگر بیٹیوں کی شادی ہوجاتی تو اس کی نسبت شوہر کے خاندان کی طرف دی جاتی تھی کیونکہ بیٹے آپ نے بآپ کے تابع ہوتے تھے جیساکہ بنی تمیم کے عنوان کا صدق کرنا ماں کے عنوان کی طرف سے کافی نہیں ہے ۔
۹ ۔ اگر کوئی سید ہونے کا دعوی کرے تو اس کے دعوے کی تصدیق نہیں کی جائے گی لیکن کاشف الغطاءفرماتے ہیں کہ (قیاسا علی دعوی الفقر حیث تقبل)(۹۱)
ترجمہ ( جس طرح فقیر کا دعوی قبول کیا جاتا ہے اسی طرح ہاشمی ہونے کا دعوی بھی قبول کیا جائے ۔
کاشف الغطاء کے کلام پر دو اشکال ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
ا ۔ فقیر کے دعوی کو ہاشمی کے دعوی کے ساتھ قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکہ اکثرو غالب انسان شروع سےفقر کے ساتھ مبتلا ہیں اور اگر کوئی شک کرے تو قاعدہ استصحاب جاری ہو گا لیکن ہاشمی کا دعوی اس کے خلاف ہے کیونکہ اول سے مشکوک ہے اور کسی صورت میں ثابت نہیں ہے جب تک کہ شک ہو تو اس صورت میں قاعدہ استصحاب جاری نہیں ہو گا ۔
ب ۔ اگر آپ کا منظور یہ ہو کہ (الانسان اعرف بحاله )یعنی انسان آپ نے نسب کے بارے میں دوسروں سے زیادہ اگاہ تر ہے پس مسلمان کہ جس نے ہاشمی ہونے کا دعوی کیا ہے اس کا دعوی قبول کیا جائے جسطرح کہ فقیر کا دعوے کی تصدیق کی ہے
جواب : اس کا جواب یہ ہے کہ آگاہ تر ہونا فقیر کی نسبت سے اور مسلم کی نسبت سے واضح ہے لیکن نسب کی نسبت سے واضح نہیں ہے ۔
۱۰ ۔ ہاشمی ہونا قسم اور اطمینان کے ذریعے سے ثابت ہو گا جس پر پہلے دلیلیں بیان ہو چکی ہیں ۔
زکات کے عام احکام
مالک کے لیے جائز اور صحیح ہے کہ وہ زکات کے مال کو جدا کرے اورالگ رکھے اور زکات کے علاوہ بقایا مال میں تصرف کرے اور معزول( جدا شدہ مال زکات کے لیے ) مال مستحقین کا ہے اور مالک کے ہاتھ میں امانت ہے اور اس کا ضامن بھی نہیں ہو گا زکات کے لیے جدا شدہ مال کو جابجا کرنا اور تبدیل کرنا جائز نہیں ہے اگر مالک مستحق کے مصداق میں خطاء کرے یعنی اس شخص کو زکات دیا ہے اور اعتقاد بھی رکھتا تھا کہ وہ شخص فقیر ہے اور اس کو زکات دے لیکن بعد میں معلوم ہو جائے کہ وہ شخص فقیر نہیں تھا تو اس صورت میں زکات کے مال کو اگر اس شخص کو دیا ہے اور اس نے تلف نہیں کیا ہے تو لازمی ہے کہ اس مال کو وآپ س پلٹائے اور اگر تلف ہو گیا اور اس شخص نے اس مال میں افراط وتفریط نہیں کیا ہے تو اس صورت میں مزکی(زکات دینے والا ) ضامن نہیں ہے بلکہ فقیر ضامن ہے اس شرط کے ساتھ کہ فقیر واقع حال(فقیر کو پتہ تھا کہ جو کچھ لیا ہے وہ زکات ہے اور اس کا مستحق نہیں تھا)سے اگاہ ہے ۔
اگر مزکی نے گمان کیا تو اس کے اوپر زکات واجب ہے اور اس کا گمان غلط تھا لیکن مال کو عنوان زکات فقیر واقعی کو دے دیا ہے اگر یہ مال بعد از دفع فقیر تلف ہو جائے تو اس مال کو زکات کا مال اور زکات دینا حساب نہیں کیا جائے گا جوکہ تمام اموال سے تعلق پیدا کرے گا اور اگر مال باقی ہے تو جائز ہے کہ فقیر کی طرف رجوع کرے اور فقیر سے زکات طلب کرے اور اگر زکات تلف ہو گیا ہو اور فقیر مزکی کے اشتباہ سے واقف نہیں تھا تو فقیر کے لیے جائز ہے کہ اس کے بدل کا مطالبہ کرے ۔
دلائل
۱ ۔ عزل(جدا کرنا) کے دو معانی ہیں جوکہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
ا ۔ عزل کا معنی مباح (حکم تکلیفی )ہے کیونکہ مال مالک اور مستحقین کے درمیان مشترک ہے اور تصرف مال مشترک مال میں تصرف جائز نہیں ہے پس مالک حق عزل نہیں رکھتا اور اس کا تصرف کرنا حرام ہے ۔
ب ۔ عزل کا معنی صحت وصحیح(حکم وضعی) ہے اگرچہ جواز عزل مشترک مال میں خلاف قاعدہ ہے لیکن اگر مالک کی ولایت پر دلیل ہو کہ مالک کا تصرف زکات کے مال میں ظاہر ہے اور شارع نے مالک کو ولایت دی ہے کہ زکات کو عزل کرے اور اس کا عزل کرنا صحیح ہےیعنی مال معزول (زکات کے لیے جدا شدہ مال)مال مستحقین ہے اور افراط وتفریط کیے بغیر مال تلف ہو جائے تو مالک ضامن نہیں ہے اور زکات کے معزول کرنے میں فقراء کا معزول مال حق میں تعین و تشخص پیدا کرتا ہے ۔
جیساکہ یونس بن یعقوب کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُ عَلَيَ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لَا يَضُرُّكَ (۹۲)
ترجمہ :"یونس بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مہینہ میں مجھ پر زکوۃ واجب ہو جاتی ہے ۔ آیا اس ارادہ سے اس کی ادائیگی میں دیر کرنا جائز ہے شاید کوئی سائل آ جائے تو میرے پاس کچھ مال موجود ہو ؟ فرمایا : جب سال پورا ہو جائے تو آپ نے مال کی زکوۃ ادا کر( علیحدہ کر) اور اسے کسی چیز سے مخلوط نہ کرے ۔ پھر جس طرح بھی چاہے ادا کرے ۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر میں لکھ لوں ( کہ اس قدر زکوۃ میرے ذمہ واجب الاداء ہے ) تو آیا یہ ٹھیک ہے ؟ فرمایا : ہاں یہ چیز ضرر رساں نہیں ہے "
اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
اب جب مالک کی ولایت عزل پر ثابت ہو گئی اور اس کے اوپر ثمرات و فائدے مرتب ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
۱ ۔ اگر عزل (زکات کے مال کو جدا کرے )کرے اور معزول زکات کےمال کو تلف کر دے یعنی حق مستحقین کو تلف کر دے ۔
۲ ۔ اور اگر عزل(زکات کے مال کو جدا کرے) نہ کرے اور مال میں سے کچھ تلف ہو جائے تو شرکاء کے اوپر خسارت تقسیم ہو گی فرض کرتے ہیں کہ وہ مال جو زکات سے متعلق ہے مثلا دو میلیون روپے ہے اور زکات ایک لاکھ روپے ہے اگر مالک نے زکات ایک لاکھ روپے کو عزل کیا ہے اور زکات بغیر تفریط کے تلف ہو جائے تو اس مال پر اور زکات نہیں ہے اور تمام خسارت مستحقین کے حق میں ہو گی لیکن اگر مال میں زکات کے لیے عزل (زکات کے مال کو جدا کرے)نہیں کیا ہے اور وہی مقدار یعنی ایک لاکھ روپے تلف ہو گیا ہے تو مستحقین کو پانچ ہزار روپے اور مالک کو ۹۵ ہزار روپے کی خسارت ہو گی لیکن ابھی تک مال میں ۹۵ ہزار روپے کی زکات موجود ہے ۔
۲ ۔ اگر مزکی مال میں سے زکات کو جدا کرے لیکن سھوا فقیر کو زکات دے جوکہ فقیر نہیں تھا اور مزکی نے گمان کیا تھا کہ وہ فقیر ہے اگرچہ زکات فقیر کے پاس باقی ہے تو اس صورت میں زکات کو اس سے وآپ س لے گا اور فقیر حقیقی و واقعی کو دے کیونکہ مال معزول فقراء کی ملکیت ہے اور مال غیر کو کسی اور کو نہیں دے سکتا ہے ہاں اگر مال زکات کو جدا نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے مال کوزکات کی مقدار کے برابر فقیر کو عطاء کرے اور بعد میں پتہ چلے کہ اس نے اشتباہ کیا ہے اور لینے والا بھی فقیر واقعی نہیں تھا تو اس صورت مین زکات کا وآپ س لینا واجب نہیں ہے اور اگر اس زکات کے بدلے مین دوسرا مال موجود ہو یعنی زکات دینے والے کے پاس اس زکات کے علاوہ دوسرا مال موجود ہو اور اس مال زائد سے زکات کو دے سکتا ہے تو وہ اس مال زائد سے زکات کا بدل دے اور اگر اس کے لیے زکات کا بدل دینا ممکن نہ ہو یعنی زکات دینے والے کے پاس اس مال کے علاوہ مال زائد نہیں ہے تو اس صورت میں اس مال کا وآپ س لینا واجب ہے کیونکہ یہ وآپ س لینا زکات کے دینے کے لیے مقدمہ ہے کیونکہ واجب کا مقدمہ واجب ہے ۔
۳ ۔ اور اگر مالک زکات کو الگ کرے اور زکات کو فقیر غیر واقعی کو عطاء کرے اور بعد میں مالک کو پتہ چلے کہ وہ شخص مستحق نہیں تھا اور فقیر غیر حقیقی زکات کو تلف کر دے تو اس صورت میں اگر مالک زکات کےمال میں افراط و تفریط نہ کرے تواس مال کا ضامن نہیں ہے جوکہ فقیر غیر حقیقی نےتلف کیا تھا لیکن اگر فقیر غیر حقیقی کو علم تھا کہ وہ مستحق نہیں اور زکات لے تو اس صورت میں فقیر غیر واقعی ضامن ہو گا کیونکہ اس پر قاعدہ علی الید جاری ہو گا (علی الید ما اخذت حتی تؤدی )(۹۳) یعنی لینے والا ضامن ہے ۔
۴ ۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے مال پر زکات واجب ہوئی ہے اور فقیر کو زکات عطاء کرے اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کے مال پر زکات واجب نہیں ہوئی تھی اور اس نے اشتباہ کیا تھا اور وہ مال جو اس نے بطور زکات فقیر کو دی ہے تو وہ اس مال کو دوسرے زکات میں حساب نہیں کر سکتا ہے جوکہ بعد میں اس شخص پر زکات واجب ہو گی کیونکہ ہمارے پاس اجزاء پر دلیل نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کے مال پر زکات واجب ہوئی ہے اور فقیرکو دے لیکن بعد میں مالک آپ نے اشتباہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ مال پر زکات واجب نہیں ہوئی تھی اور زکات کا عین بھی فقیر کے پاس باقی ہے تو اس صورت میں مالک کے لیے جائز ہے کہ فقیر کی طرف رجوع کرے اور آپ نے مال کو وآپ س لے کیونکہ وہ مال فقیر کی ملکیت نہیں ہوئی ہے اور مالک کی ملکیت میں باقی ہے۔
اور اگر مالک آپ نے اشتباہ و خطاء معتقد ہو جائے کہ اس کے مال پر زکات واجب ہوئی ہے اور فقیر کو زکات دے اور فقیر زکات کو تلف کر دے تو اس صورت میں مالک کے لیے جائز ہے فقیر سے تلف شدہ زکات کا مطالبہ کرے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ فقیر مالک کے اشتباہ سے واقعا آگاہ ہو کیونکہ اس پر دلیل قاعدہ علی الید ہے ہاں اگر فقیر مالک کے اشتباہ سے واقعا اگاہ نہ ہو اور گمان کے طور پر زکات لے اور اس کا استعمال بھی کر لے تو اس صورت میں فقیر ضامن نہیں ہو گا کیونکہ فقیر جاھل تھا ۔
زکات فطرہ
زکات فطرہ بالغ پر ، عاقل پر، ازاد پر اور وہ شخص جوکہ زکات کے واجب ہونے کے وقت بیہوش نہ ہو تو زکات ان پر واجب ہو گی ۔
مشہور کا عقیدہ یہ کہ تمام شرائط کا ایک لحظے میں قبل از تحقق غروب عید فطر کی رات ہے اور مشہور ہے کہ زکات فطرے کے واجب ہونے کا پہلہ لحظہ غروب عید فطر کی رات ہے اور وہ شخص جس نے عید فطر کی نماز نہیں پڑھی تو زکات فطرہ کا آخری لحظہ عید کے دن ظہر کے زوال کاہونا ہے ۔
اگر زکات فطرہ واجب ہونے کے وقت عزل (زکات فطرہ کو جدا کرے)کرے اور اس زکات فطرہ کو تاخیر سے دینا عقلائی طور پرجائز ہے کیونکہ زکات جدا کرنے سے معین ہو جاتا ہے ۔
زکات کا نکالنا ہر مکلف آپ نے طرف سے اوران اشخاص کے طرف سےجن کا وہ کفیل ہے نکالنا واجب ہے جیساکہ مہمان کا زکات ، لیکن اس صورت میں جب ان پر عیلولہ(نفقہ اور کفالت )صدق کرے تو زکات واجب ہو گی زکات فطرہ کی مقدار ایک صاع جوکہ تین کلو گرام عوام ناس میں غالبا مشہور ہے اور اس زکات فطرہ کی قیمت بھی ادا کرنا جائز ہے اور اے کا استعمال بھی زکات کے استعمال کی طرح ہے ۔
دلائل
۱ ۔ تین دلیل کے ساتھ زکات فطرہ واجب ہے اور زکات فطرہ زکات مال کے مقابلے میں ہےاور یہ مسّلما ت میں سے ہے اور اس پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں جن میں سے بعض کو بعد میں بیان کیا جائے گا
اسی طرح آیت کی تفسیر کی گئی ہے جیساکہ قرآن میں خداوندعالم ارشاد فرماتے ہیں
( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلى ) (۹۴)
ترجمہ :"بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا 'جس نے آپ نے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی "
یہ آیت زکات کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے
ب ۔ اور دوسری دلیل روایات سے ثابت ہے(۹۵) اور اس آیت کی روایات میں اس طرح تفسیر کی گئی ہے کہ:
" وہ لوگ سچے ہو گئے جن لوگوں نے زکات فطرہ ادا کیا اور آپ نے خدا وندہ متعال کو یاد کیا پھر عید کی نماز پڑھی"
زکات فطرہ واجب ہونے کی شرائط اور دلائل
۱۔۲ عقل اور بلوغ
۲ ۔ زکات فطرہ کےواجب ہونے میں شرط بلوغ وعقل پردو دلیلیں ہیں جوکہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
ا ۔ مقتضی قاصر ہے کیونکہ خطابات بچے اور مجنون کو شامل نہیں ہوتا ہے
ب ۔ حکومت حدیث (رفع القلم)(۹۶) رفع زکات پر دلالت کرتی ہے حدیث رفع اطلاق پر دلالت کرتی ہے اور احکام تکلیفی و وضعی اور عاقبت اخروی کو شامل ہوتی ہے حاکم کی دلیل (حدیث رفع )حالت تفسیری میں اور دلیل پر نظارت محکوم ہے جوکہ زکات فطرہ پر دلالت کرتی ہے ۔
۳ ۔ استطاعت
زکات فطرہ کے واجب ہونے میں سے ایک شرط مالدار ہونا ہے کہ اس قدر اس شخص کے پاس مال ہو کہ وہ آپ نے سال بھر کا خرچہ پورہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں فقیر پر زکات واجب نہیں ہے جیساکہ حلبی کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا "(۹۷)
ترجمہ :"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ} حلبی سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ سے پو چھا گیا کہ جو شخص خود زکوۃ وصول کرتا ہے ( اورن آپ نی گزر اوقات کرتا ہے ) آیا اس پر فطرہ واجب ہے ؟ فرمایا : نہ "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
مگر اس کے مقابلے میں زرارہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے صحیح روایت ہے :
"زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ "(۹۸)
ترجمہ:"{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ } زرارہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ فقیر و محتاج جیسے صدقہ دیا جاتا ہے ۔ آیا خود اس پر فطرہ ہے ؟ فرمایا : ہاں اسی سے فطرہ دے جو اسے صدقہ دیا گیا ہے "
اول روایت نص ہے جوکہ زکات کے عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے اور دوسری روایت ظاہر وجوب زکات پر دلالت کرتی ہے پس تو اس صورت ممکن ہے کہ دوسری روایت کو استحباب پر حمل کریں ۔
۴ ۔ آزاد ہو
آزاد ہونے کی شرط زکات واجب ہونے کے لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ غلام فقیر ہے اور ممکن نہیں ہے کہ غلام مالک ہو جائے اور اگر اس دلیل کو بھی قبول نہ کریں تو تنہا دلیل ہمارے پاس تسالم ہے ۔
۵ ۔ پاگل نہ ہو
مشہور ہے کہ جس مال کے اوپر زکات واجب ہوئی ہے اس کا مالک تمام وقت (عید فطر کے غروب کے رات سے لے کر عید فطر کے زوال تک)با ہوش ہو اور اگر تمام وقت باہوش نہ ہو بلکہ کچھ وقت با ہوش ہو تو اس پر بھی زکات واجب نہیں ہے لیکن قول مشہور کے بارے میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اور فقط اطلاق کی دلالت اس کو شامل ہو گی ۔
اشکال : اگر کوئی شخص زمان بے ہوشی کی حالت میں زکات فطرہ ادا نہیں کر سکتا تو جب ہوش میں آ جائے تو زکات فطرہ کی قضاء کرئے گا یا نہیں ؟
جواب :تکلیف قضاء دلیل خاص کا محتاج نہیں ہے اور اس قسم کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر وجوب قضاء میں شک کریں تو اس صورت میں قاعدہ اصل براءت جاری ہو گی ۔
اور وہ جو کہا گیا ہے اس بنآپ ر وہ شخص جو سویا ہوا ہے اور وہ شخص جس کے پس شرعی عذر ہو مثلا غافل شخص اور وہ شخص جو بھول گیا ہو ، اگر ان اشخاص کا عذر زکات فطرہ کے واجب ہونے کے وقت ہو تو ان پر زکا ت فطرہ واجب نہیں ہے لیکن جب اجماع دلیل کے خلاف حکم نہ کرئے ۔
ایک مسئلہ
مشہور ہے کہ اگرشرائط وجوب زکات فطرہ ایک لحظے کے لیے قبل از غروب عید فطر کی رات حاصل ہو جائے تو زکات واجب ہو گی اس کو صدوق علیہ الرحمہ نے علی بن ابی جعفر سےروایت میں نقل فرمائی ہے جیساکہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :
"عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ "(۹۹)
ترجمہ :"{ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }معاویہ بن عمار سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مولود کے بارے میں جو عید الفطر کی رات پیدا ہو۔ یا جو یہودی و نصرانی عید الفطر کی رات اسلام لائے ۔ فرمایا کہ ان پر فطرہ نہیں ہے ۔ ہاں فطرہ صرف اس پر ہے جو ماہ رمضان کو درک کرئے "
پس اس بناء پر کہ روایت کے خاص ہونے کے بغیر واضح دلالت کرتی ہے کہ مکلف پر ماہ رمضان کا درک کرنا واجب ہے۔
پس اس بناء پر کہ مشہور شرط جانتے ہیں کہ تمام واجب ہونے کی شرائط ماہ رمضان میں قبل از غروب حاصل ہو جائیں اگرچہ عید فطر کی رات آخری لحظ میں حاصل ہو ں اور اس شخص میں واجب ہونے کے شرائط جمع ہوں اور اس میں تسلسل ہو تاکہ اس شخص پر صدق کرئے کہ اس نے ماہ رمضان کو درک کیا ہے اور شرائط کا جمع ہونا ماہ مبارک کے بعد کافی نہیں ہے ۔
فطرہ نکالنے کا وقت
ابتدائی وقت زکات فطرہ کے واجب ہونے کے لیے عید فطر کی رات کے غروب کو جانا گیا ہے اس پر دلیل روایت معاویہ جو کہ پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے دلالت کرتی ہے کہ زکات فطرہ کے واجب ہونے کے شرائط قبل از غروب اور اس کا تسلسل تا غروب ہو اور اس عبارت سے سمجھا جاتا ہے کہ زکات کے واجب ہونے کا وقت غروب ہے چونکہ اسی دلیل سے کہ شرائط کا جمع ہونا قبل از غروب شرط جانا گیا ہے ۔
۸ ۔ زکات فطرہ کے واجب ہونے کا وقت غروب عید فطر کی رات سے شروع ہوتا ہے اور عید فطر کے دن زوال تک ہے اور اس حکم پر روایت سے کوئی واضح دلیل نہیں ہے لیکن اصحاب کے درمیان مشہور یہ ہے ہاں اگر کوئی شہرت فتوائی کو حجت مانے تو ممکن ہے کہ شہرت فتوائی سے استنا و پرعمل کرئے اگرچہ دلیل نہیں ہے لیکن تحقیق بھی اس صورت میں اہمیت نہیں رکھتی ہے کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ اگر زکات کو عید کے ظہر تک جدا(عزل) نہیں کیا ہے تو بعد از ظہر زکات فطرہ کو جدا کرئے جس پر دلیل زرارہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا (۱۰۰)
ترجمہ:"زرارہ بن اعین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں جس نے مستحق کے ملنے تک فطرہ الگ کرکے رکھ دیا تھا ۔ فرمایا : جب آپ نی ذمہ داری پر علیحدہ کر دے تو وہ برئ الذمہ ہو جائے گا ۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو مستحقین تک پہنچانے کا ضامن ہو گا "
اور اس صحیح روایت سے مدد لی جاتی ہے کہ زکات فطرہ کے واجب ہونے کے وقت میں زوال کے بعد تسلسل پایا جاتا ہے ۔
اور اگر کوئی شخص عید فطر کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زکات فطرہ کو نماز پڑھنے سے پہلے جدا کرئے جس پر دلیل اسحاق بن عمار کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے موثق روایت ہے :
"إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ "(۱۰۱)
ترجمہ :"اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فطرہ کے متعلق سوال کیا ؟ فرمایا : جب اسے علیحدہ کر دیا جائےتو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نماز عید سے پہلے دیا جائے یا نمازکے بعد "
۹ ۔ اگر زکات فطرہ کو جدا کیا ہے تو عقلائی نقطہ نظر کی بنا پر زکات فطرہ کو تاخیر سے دینا جائز ہے جس پر دلیل اسحاق بن عمار کی روایت پہلے گذر گئی ہے لیکن تاخیر میں عقلائی نقطہ نظر اس وجہ سے معتبر ہے کہ واجب کو انجام دینے میں سستی نہ ہو اور احتیاط یہ تقاضہ کرتی ہے کہ زکات فطرہ کو جلدی ادا کرئے کیونکہ یہ جانے کا احتمال ہے کہ نماز کے بعد زکات فطرہ کو دینا عرفی بعدیت( تاخیر ) ہو { یعنی عرف حکم کرتا ہے کہ زکات فطرہ کو بعد از نماز دینا ممکن ہے }
۱۰ ۔ اگر مکلف زکات فطرہ کو جدا کرئےتو زکات اسی معزول (جدا شدہ )میں متعین ہو جائے گی اور مستحقین کی ملکیت ہو جائے گی اور مکلف کے لیے اس زکات کو دوسری چیز سے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مال معزول میں تصرف پر ولایت نہیں رکھتا ہے ۔
۱۱ ۔ زکات فطرہ کےواجب ہونے کا میزان کفالت ( نان خور )ہے جیساکہ عمر بر یزید کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے : "عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ "(۱۰۲)
ترجمہ :"عمر بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایک شخص کے پاس اس کا کوئی برادر ایمانی مہمان ہوتا ہے اور فطرہ کا وقت آ جاتا ہے آیا یہ اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرے گا ؟ فرمایا : ہاں تمام عیال کی طرف سے فطرہ واجب ہے خواہ نر ہوں یا مادہ ، چھوٹے ہوں یا بڑے اور آزاد ہوں یا غلام "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
مہمان کا فطرہ
۱۲ ۔ اس دلیل سے مہمان کی حالت روشن ہو جائے گی کہ زکات فطرہ کا واجب ہونا مہمان کا تابغ ہے کہ اس پر کفالت صدق کرئے پس بناءبر کہ وجوب کا دارو مدار عنوان صدق عیلولہ(نان خور) ہے اور مہمان کی وضیعت بھی معلوم ہو جائے یعنی مہمان کو عرفا نان خور کہا جائے تاکہ میزبان پر زکات فطرہ واجب ہو جائے پس اگر کوئی شخص قبل از عید فطر کسی کا مہمان ہو جائے اور عیدالفطر کا دن آ جائے تو اس صورت میں اگر مہمان پر عنوان نان خور صدق آ جائے تو زکات فطرہ میزبان کو ادا کرنی ہو گی اور فقط مہمان کا عنوان صدق کرنا کافی نہیں ہے جیساکہ لازمی نہیں ہے کہ پورے ماہ رمضان مہمان ہو یا ماہ رمضان کے نصف کف بعد مہمان ہو اور یا اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی اس مسئلہ میں پائے جاتے ہیں ۔
فطرہ کی مقدار
۱۳ ۔ زکات کی مقدار ایک صاع (تقریبا ۳ کلو گرام )ہے جیساکہ معاویہ بن وھب کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے :
"مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَفمَنِ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ "(۱۰۳)
ترجمہ :"معاویہ بن وھب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فطرہ کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے کہ اس سلسلہ میں سنت یوں جاری ہے کہ خرما کا ایک صاع یا خشک انگور کا ایک صاع یا جوکا ایک صاع ۔ ہاں عثمان کا دور تھا اور گندم زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے لوگوں کے لیے جو کے ایک صاع کے متبادل گندم کا نصف صاع مقرر کیا تھا"
لیکن حلبی کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے رموی صحیح روایت ہے :
"الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ عَنْ كُلِ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِين "(۱۰۴)
ترجمہ :"حلبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : صدقہ فطرہ تمہارے اہل عیال میں سے ہر شخص کی جانب سے گندم ، جو ، خرما یا خشک انگور کا نصف صاع مسلمانوں کے فقیر و نادار لوگوں کے لیے ہے "
اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ۔
لیکن روایت حجیت سے ساقط ہیں کیونکہ اصحاب نے اس قسم کے مضامین سے دوری کی ہے اور اس پر عمل نہیں کیا ہے ۔
۱۴ ۔ مگر دارو مدار زکات یہ ہے کہ غالب کھانا لوگوں کا ہو حالانکہ اس کے باوجود بعض روایات میں چار قسم کے غلاّت آئے ہیں اور بعض قسم کی چیزوں کا بھی زکات میں ذکر ہواہے مثال کے طور پر دودھ اور پنیر وغیرہ وغیر ہ ہیں جس پر دلیل زرارہ اور ابن مسکان کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِ قَوْمٍ مِمَّا يَغْذُونَ عِيَالَهُمْ لَبَنٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ "(۱۰۵)
ترجمہ :"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ ب آپ نی سند کے ساتھ } زرارہ اور ابن مسکان سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں فرمایا : ہر قوم کو اس چیزسے فطرہ دینا چائیے جو وہ خود کھاتے ہیں اور آپ نے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں خواہ وہ دودھ ہو یا خشک انگور وغیرہ "
اور تمام روایات اور توجہ کے ساتھ اس روایت کو ضروری ہے کہ چار قسم کے غّلات اور اس جیسی دوسری چیزوں کو ایک مثال کے طور پر حمل کریں گے اور زکات کے مصادیق کی تعداد میں روایات میں اختلاف بھی اس حمل کی تائید کرتے ہیں ۔
۱۵ ۔ صاع کی مقدار پہلے ذکر ہو چکی ہے ہے جوکہ چار مد کے برابر ہے اور ہر مد تقریبا ۷۵۰ گرام ہے ۔
۱۶ ۔ زکات فطرہ میں غّلات کا حساب کر کے قیمت کا دینا جائز ہے جس پر دلیل عمار بن اسحاق صیرفی کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی موثق روایت ہے :
"إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ "(۱۰۶)
ترجمہ :" عمار بن اسحاق صیرفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں آپ علیہ السلام فطرہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ؟ آیا میں ان نام بردہ چیزوں کی بجائے بطور قیمت چاندی دے سکتا ہوں ؟ فرمایا : ہاں یہ تو اس شخص کے لیے زیادہ مفید ہے ۔ وہ اس سے جو چاہے گا ( حسب ضرورت ) خریداری کرے گا "
اور اس علاوہ دوسری روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں ۔
فطرہ کا مصرف
۔ زکات فطرہ کا استعمال مال کی زکات کے استعمال کس ساتھ یکساں ہے کیونکہ زکات فطرہ مصادیق زکات مال اور صدقہ ہیں اور اطلاق آیت بھی اس کو شامل ہوتی ہے ( انما الصدقات ) جس میں زکات کے استعمال کو مطلقا ذکر کیا گیا ہے ۔
کتاب خمس
جن چیزوں پر خمس واجب ہے ۔
خمس سات چیزوں پر واجب ہے جوکہ مندرجہ ذیل ہیں :
۱ ۔ جنگ کا مال غنیمت
۲ ۔ معدن
جس کی قیمت ۲۰ دینار ہو اور اگر نصاب میں شک کرے کہ ۲۰ دینار ہے کہ نہیں تواس صورت میں خمس واجب نہیں ہے اور معدن سے اخراجات نکالنے کے بعد باقی معدن خمس کے متعلق ہو جائے گی البتہ اخراجات نکالنے سے پہلے خمس کے نصاب کا حساب کیا جائے گا ۔
۳ ۔ گنج
یعنی خزانہ جس کی قیمت ۲۰ دینار یا ۲۰۰ درھم ہو اور ضروری ہے کہ گنج دینار و درھم سونے کے سکّے ہوں اور اس کا نصاب کاحساب و اخراجات لینا معدن کی طرح ہے ۔
۴ ۔غواصی کے جواہرات
دریا میں غوطہ خوری کے ذریعے سےحاصل ہونے والے جواہرات ہوں اور اس سے اخروجات نکالنے کے بعد اس کی مقدار ایک دینار ہو جائے تو اخراجات نکالنے کے بعد اس میں سے خمس دیا جائے گا۔
۵ ۔ حلال مال جو حرام سے مخلوط ہو جائے
اور مال حرام قابل شناخت نہ ہو اور اس کا مالک و مقدار بھی معلوم نہ ہو ۔
۶ ۔ وہ زمین جس کو کافر ذمی مسلمان سے خریدے ۔
۷ ۔ سالانہ زندگی کے اخراجات سے زیادہ مال ہو ۔
خمس واجب ہونے کی اشیاء اور ان کے مصارف
۱ ۔خمس کے واجب ہونے پر مندرجہ ذیل دو دلیلیں ہیں :
ا ۔ خمس کا واجب ہونا ضروریات دین میں سے ہے ۔
ب ۔ اور آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے جیساکہ خدا وندعالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں :کہ
( وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شىَءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىَ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيل ۔۔ ) (۱۰۷)
ترجمہ :"اور جان لو کہ جوغنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ' اس کے رسول اور قریب ترین رشتے داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے ۔۔"
اور آیت میں لام (لله و للرسول و ۔۔۔۔) ملکیت کے لیے ہے پس ان کا مالک اللہ ورسول ہیں تو اس بنآپ رخمس کا دینا واجب ہے تمام مسلمین اجمالا اصل خمس کے واجب ہونے کے قائل ہیں اور ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے اختلاف عمومی ہے کیونکہ اہل سنت فقط جنگ کے مال غنیمت کےقائل ہیں لیکن امامیہ عموم کے قائل ہیں یعنی جس چیز پر مال غنیمت کا عنوان صدق کرے اس پر خمس ہے اور غنائم جنگی سے غنیمت عام ہے اور اگر خمس کے وجوب کو غنائم جنگی میں منحصر کر دیں تو ہمارے زمانے میں یا تو خمس کا مصداق نہیں ہے یا تو پھر بہت کم ہے ۔
حالانکہ امامیہ کے درمیان معروف ہے کہ خمس کے موارد عام ہیں دو دلیلوں کے ذریعے سےجوکہ مندرجہ ذیل ہیں :
ا ۔ لغت(۱۰۸) کے لحاظ سے غنیمت عام ہے اور غنیمت تمام فوائد کو شامل ہوتی ہے اورفقط غنائم جنگی کے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس طرح قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے جیساکہ خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ
( تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ) (۱۰۹)
ترجمہ :"تم دنیاوی مفاد کے طالب ہو جب کہ اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں "
اور آیت کی سیاق اختصاص پر دلالت نہیں کرتی ہے کیونکہ کلی مطالب کو بعض مصادیق پر تطبیق کرنا ممکن ہے ۔
ب۔ اور خاص روایات ہیں جن کو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا ۔
۲ ۔ جنگی غنائم پر خمس ثابت ہے جس پر دلیل قدر متیقن آیت کریمہ ہے بلکہ جنگی غنائم خمس کے موارد میں سے ہے ۔
۳ ۔ معادن پرخمس واجب ہونے میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے جس پر دلیل زرارہ کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ "(۱۱۰)
ترجمہ :" زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امامحمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ معادن میں کس قدر حصہ واجب ہے ؟ فرمایا : جہاں تک رکاز (زمین کے اندرقدرتی گڑی ہوئی دھاتوں ) کا تعلق ہے ان میں خمس (پانچواں حصہ ) واجب ہے "
تمام روایات بلکہ آیت کی اطلاق غنیمت پر معادن کے واجب ہونے کے اثبات کے لیے کافی ہے ۔
۴ ۔ جب معدن کا نصاب ۲۰ دینار ہو جائے تو اس کا خمس دینا ہو گا جس پر دلیل بزنطی کی حضرت امام رضا علیہ السلام سےصحیح روایت ہے:
"أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَارا "(۱۱۱)
ترجمہ "{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ ب آپ نی سند کے ساتھ }احمد بن محمد بن ابو نصر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ جو چیز معدن ( کان ) سے برآمد ہو آیا اس کی قلیل و کثیرمقدار پر کچھ واجب ہے ؟ فرمایا : جب تک اس کی مقدار اس حد تک نہ پہنچ جائے جس میں زکوۃ واجب ہوتی ہے یعنی بیس دینار تب تک اس میں کچھ نہیں ہے ہاں جب بیس دینار تک پہنچ جائے تو اس میں خمس واجب ہے "
مگر اس روایت کا دوسری روایت سے ٹکراؤ ہے جس میں خمس کے نصاب کو ایک دینار بیان کیا گیا ہے جیساکہ حضرت امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں :کہ
"عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ "(۱۱۲)
ترجمہ : "محمد بن علی بن ابو عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ جو لؤلؤ( و المرجان )اور یاقوت اور زبرجد سمندر سے نکلتے ہیں اور جو سونا اور چاندی کان سے برآمد ہوتے ہیں آیا اس میں زکوۃ ہے ؟ فرمایا : جب ان کی قیمت ایک دینار تک پہنچ جائےتو اس میں خمس ( پانچواں حصہ ) واجب ہے "
ممکن ہے کہ ان دو روایتوں جمع کریں اور بعض علماء نے دوسری روایت کو استحباب پر اور اول کو وجوب پر حمل کیا ہے اگر ہماری دلیل کامل و تام نہ ہو تو اس صورت میں مجبور ہیں کہ دوسری روایت سے چشم پوشی کریں گے کیونکہ وہ روایت شاذ ہے اور اس کی نسبت کسی کو نہیں دی گئی ہے مگر ابی صلاح حلبی کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے ۔
اور بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ دوسری روایت راوی (محمد بن علی بن ابی عبداللہ) ضعیف ہے تو اس صورت میں دو روایتوں کے درمیان جمع کی دلالت کی طرف محتاج نہیں ہے کیونکہ دوسری روایت ضعیف اور اس کے ساتھ اس کا راوی بھی مجہول ہے ۔
اور ممکن ہے کہ ان کو اس طرح جواب دیا جائے : کہ جو روایات بزنطی جیسے اصحاب اجماع نقل کرتے ہیں(۱۱۳) ان میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔
۵ ۔ اگر معادن کو نکالے اور اس کے نصاب میں شک کرے تو اس پر خمس نہیں ہے ۔
اگر معادن کا نکلنا تدریجی تھا اور ابھی شک کرئے کہ نصاب تک پہنچ گیا ہے یا نہیں ۔لیکن جب معادن کی مقدار کم تھی اور یقین بھی تھا کہ مقدار نصاب تک نہیں پہنچی ہے اور جب معادن کی مقدار زیادہ ہو گئی تب بھی شک کریں کہ مقدار نصاب تک پہنچ گئی ہے کہ نہیں ، تو اس صورت میں استصحاب کا قاعدہ جاری ہو گا یعنی معادن کی مقدار نصاب تک نہیں پہنچی ہے پس اس معادن پر خمس واجب نہیں ہے اور اس قاعدہ کو استصحاب عدم نعتی کہا جاتا ہے ۔
اگر ایک دفعہ زیادہ مقدار میں معادن خارج ہو جائے لیکن شک کریں کہ آیا مقدار نصاب تک پہنچی ہے یا نہیں ؟ معادن نکالنے سے پہلے نصاب کا وجود نہیں تھا کیونکہ معادن نکلا ہی نہیں تھا تو صورت میں استصحاب کا قاعدہ جاری ہو گا اور اس معادن پر خمس واجب نہیں ہے اور اس قاعدہ کو استصحاب عدم ازلی کہا جاتا ہے یا دلیل برات ہے البتہ اگر استصحاب کی طرف رجوع کرنا ممکن نہ ہو ۔
۶ ۔ معادن کو نکالنے کے لیے جو اخراجات کیے گئے ہیں اسے پہلے جدا کر لیا جائے اس باقی ماندہ معادن پر خمس واجب ہو جائے گی جس پر دلیل حضرت امام جواد علیہ السلام کی روایت ہے :
"الخُمُسُ بَعدَ المَؤونَةِ "(۱۱۴)
ترجمہ :"{حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ ب آپ نی سند کے ساتھ }محمد بن حسن اشعری سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا جس میں یہ استدعا کی کہ مجھے بتائیں کہ آدمی جو کچھ کم یا زیادہ کماتا ہے اور ہر قسم کے ذریعہ معاش سے کماتا ہے اور جائیدادکی آمدنی بھی ہے آیا سب پر خمس ہے ؟ اور کس طرح ہے ؟ امام علیہ السلام نے آپ نے دسخطوں سے لکھا کہ خمس اخراجات کے بعد ہے "
یہ روایت کلی قانون کی صورت میں نقل ہوئی ہے ۔
پس اس بناء پر خمس کے واجب ہونے کا موضوع نہیں ہے مگر خمس کے واجب ہونے کا موضوع غنیمت اور فائدہ ہے اور اسی طرح آیت بھی غنیمت پر دلالت کرتی ہے معادن پر خمس واجب ہو نا اور اس جیسی دوسری چیزیں پر اس دلیل کے ساتھ ہے کہ سب غنیمت کی مصداق ہیں اور روشن ہے کہ غنیمت کا عنوان اس وقت صدق نہیں کرتا ہےجب تک معادن سے اخراجات جدا نہیں کیے ہوں ۔
۷ ۔ خمس کی نصاب کی مقدار میں مجموع کو مد نظر رکھا گیا ہے اور باقی ماندہ مقدار کی لحاظ نہیں کی گئی ہے لیکن اس کے خلاف صاحب جواہر کا نظریہ {نصاب کی مقدار حق زحمت نکالنے کے بعد ہے }ہے جس پر دلیل اطلاق کا بلوغ پر دلالت کرنا ہے جوکہ روایت صحیح بزنطی میں پہلے گذر چکی ہے ۔
۸ ۔ گنج پر بغیر کسی اشکال کے خمس واجب ہوتا ہے جس پر دلیل ابن ابی عمیر ہے کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے:
"ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ (۱۱۵)
ترجمہ :{حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ }آپ نی کتاب المقنع مین فرماتے ہیں کہ محمد بن ابی عمیر نے روایت کی ہے کہ خمس پانچ چیزوں مین واجب ہے ۱ ۔ خزانہ ۲ ۔ معدن ۳ ۔ غوطہ زنی ۴ ۔ غنیمت اور پانچویں چیز ابن ابی عمیر بھول گئے "
اور سند کا مرسل ہونا روایت کی صحت کو نصان نہیں پہنچاتی ہے کیونکہ اس کا راوی ابن ابی عمیر ہے
کیونکہ عرف کی دیدگاہ سے ایک کی تعبیر ایک بندہ اور زیادہ پر اطلاق ہوتی ہے اور تین بندےاور زیادہ عدد ہیں کہ احتمال حساب کے ذریعے سے اس گروہ کا جمع ہونا کذب پر محال و بعید ہے اور مشایخ کے درمیان ابن اب؛عمیر اوردیگر افراد امام عادل میں سے ہیں ۔
۹ ۔ گنج کا نصاب ۲۰ دینا ریا ۲۰۰ درھم تک ہو جائے تو اس مقدار پرخمس واجب ہو جائے گی جس پر دلیل بزنطی کی حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ "(۱۱۶)
ترجمہ :"احمد بن ابو نصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ دفینہ کی کتنی مقدار میں خمس واجب ہوتا ہے ؟ فرمایا : جتنی مقدار میں زکوۃ واجب ہوتی ہے (یعنی بیس دینار )اس میں یہاں خمس واجب ہے "
اس کے بعد اگر قبول کریں کہ زکات واجب نہیں ہوتی ہے جب تک ۲۰ دینار یا ۲۰۰ درھم تک اس کی مقدار پہنچ نہ جائے ۔
۱۰ ۔ اور گنج کو سونا وچاندی ہونا چائیے اور وہ سکّے بازار میں رائج ہوں کیونکہ سابقہ صحیح روایت میں اس کو بیان کیا گیا ہے جیساکہ زکات غّلات اور جانوروں کے علاوہ کسی دوسری چیز پر واجب نہیں ہے اور خمس واجب نہیں ہے مگر سونا اور چاندی کے سکّوں پر جوکہ بازار میں رائج ہوں ۔
۱۱ ۔ گنج میں حق زحمت(نکالنے کے اخراجات) کا حساب معادن کی طرح ہے جوکہ بیان ہو چکا ہے ۔
۱۲ ۔ دریا میں غوطہ خوری کے ذریعے حاصل ہونے والے مال پر خمس واجب ہوتی ہے جیساکہ روایت سابقہ میں ابن ابی عمیر اور روایت صحیح عمّار جوکہ بعد میں آنے والی ہے اور اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس بات کی تائید کردی ہیں ۔
۱۳ ۔ غوطہ خوری کے ذریعے سے حاصل ہونے والے مال کے مقدار کا نصاب ایک دینار ہے جیساکہ روایت بزنطی میں محمد بن علی بن ابی عبداللہ نے ارشاد فرمایا ہے جوکہ پہلے معادن کی بحث میں بیان ہو چکا ہے ۔
۱۴ ۔ غوطہ خوری میں حق زحمت ( نکالنے کےاخراجات ) کا حساب معادن اور گنج کی طرح ہے جوکہ پہلے بیان ہو چکا ہے ۔
۱۵ ۔ حلال مال جو حرام سے مخلوط ہو جائےتو اس پر بھی خمس واجب ہے جس پر دلیل عمار بن مروان کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ "(۱۱۷)
ترجمہ :"{حصرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ } عمار بن مروان سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ فرما رہے تھے کہ جو چیز معدن سے نکلے یا سمندر سے اور مال غنیمت اور وہ مال حلال و حرام سے مخلوط ہو جائے اور اس کے مالک کا کوئی پتہ نہ چل سکے اور دفینہ ان سب میں خمس واجب ہے "
اس کے علاوہ دوسری روایات بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہیں ۔
۱۶ ۔ حلال مال جو حرام سے مخلوط ہو جائےتو ضروری ہے کہ مال حرام کی مال حلال سےتمیز و تشخیص نہیں دی جائے کیونکہ اگر تشخیص دی جائے تو ہر مال کا ایک خاص حکم ہے ۔
۱۷ ۔ حلال مال جو حرام سے مخلوط ہو جائےتو اس کا مالک مجہول ہونا چائیے جس پر دلیل پہلی والی صحیح روایت ہے اور اگر مالک معلوم ہو تو اس صورت میں اس کے ساتھ مصلحت کریں گے تاکہ مجہول مال کی مقدار معین کر سکیں ۔
۱۸ ۔ مال حرام کی مقدار بھی معلوم نہیں ہونی چائیے کیونکہ اگر معلوم ہو جائے کہ خمس سے زیادہ ہے یا کم ہے تو اس صورت میں یہ احتمال نہیں دی جا سکتا ہے کہ اس پر خمس واجب ہو کیونکہ خمس اس وقت واجب ہوتا ہے بلکہ پہلی والی صحیح روایت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مال حرام کی مقدار کے بارے میں مطـلقا جاہل ہو تو تب تمام مال کا خمس دے گا ۔
۱۹ ۔ وہ زمین جس کو کافر ذمی مسلمان سے خریدےتو اس پر خمس واجب ہے جس پر دلیل ابی عبیدۃ حذاءسے کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ "(۱۱۸)
ترجمہ :{ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }ابو عبید ۃ الحذاء سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے جو کافر ذمی کسی مسلمان سے زمین خرید لے اس پر خمس لازم ہے "
۲۰ ۔ زندگی کے سالانہ نفقہ کے خرچہ سے جو باقی(نفع) بچ جائے اس پر خمس واجب ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن ابن جنید اسکافی اور ابن ابی عقیل عمانی جوکہ قدماء میں مشہور ہیں ان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ مال زائد پر خمس واجب نہیں ہے لیکن ان دونوں فقیہ کی طرف سے علّامہ کی کتاب مختلف میں موجود ہے لیکن عدم وجوب خمس کو واضح طور پر دیکھا نہیں گیا ہے ۔(۱۱۹)
آیت غنیمت کے اطلاق کے علاوہ حد تواتر تک پہنچنے والی وہ خاص روایات ہیں جوکہ اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں جیساکہ سماعہ کی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی موثق روایت ہے ۔
"سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ "(۱۲۰)
ترجمہ :"{حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ } سماعہ سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے خمس کے متعلق سوال کیا ؟ فرمایا : جوکہ کچھ لوگ کم یا زیادہ کماتے ہیں اس میں خمس واجب ہے "
اور ہو سکتا ہے کہ اس موثق کو روایات دیگر مثلا ( الخمس بعد المؤونۃ) کے ساتھ مقید کریں اور اسی طرح جیساکہ صحیح علی بن مھزیار میں یہ قید بیان کی گئی ہےاور یہ روایت ایک خط ہے کہ ابراھیم بن محمد الھمدانی نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور امام علیہ السلام اس خط کے جواب میں فرمایا جوکہ علی بن مھزیار نے دیکھا اور پڑھا اور امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں :کہ
"فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ "(۱۲۱)
ترجمہ :"ابراہیم بن محمد ہمدانی نے ان ( امام علی نقی علیہ السلام ) کو خط لکھا کہ علی (مہزیار ) نے مجھے آپ کے والد ماجد ( امام محمد تقی علیہ السلام ) کی تحریر پڑھائی ہے امام علیہ السلام نےان کے جواب میں لکھا جسے علی بن مہزیار نے بھی پڑھا کہ اس کے اور اس کے اہل وعیال کے اخراجات اور حاکم کے خراج کے بعد ( بچت ) پر خمس ہے "
اگرچہ ھمدانی کا موثق نہ ہونا روایت کو نقصان نہیں پہنچاتاہے کیونکہ علی بن مھزیار نے خود امام علیہ السلام کے جواب کو پڑھا ہے ۔
اور اس طرح یہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مسائل کا مبتلی بہ ہونا اور یہ کہ لوگوں کا اس مسئلہ سے سروکار ہے آپ س اس کا لازمہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے امام علیہ السلام کے زمانے میں خمس کا حکم روشن ہو حالانکہ یہ احتمال بھی نہیں دیا جا سکتا ہے کہ واضح حکم واجب نہیں ہو اور اگر سال بھر کے خرچہ سے زائد مال پر خمس کا حکم واجب نہ ہوتا تو اس پر تمام فقھاء نے اتفاق نہ کیا ہوتامگر بعض قدماء نے اتفاق نہیں کیا ہے ۔
پس اس بناء پر لازمی ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کا حکم واجب ہے ۔
زندگی کے سالانہ اخراجات سے زائد مال پر خمس کے خاص احکام
تمام وہ فائدہ جو سالانہ آپ نے اہل وعیال کے اخراجات پر صرف کرنے کے بعد بچ جائے تو اس زائد مال پر خمس واجب ہے اگرچہ وہ مال کسب وکاروبار کے ذریعے حاصل نہیں کیا گیا ہو لیکن مشہور اس کے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مال جو کسب وکاروبار کے ذریعےسے حاصل ہو تو اس پر خمس واجب ہے ۔
ہاں اگر میراث کے ذریعے مال حاصل ہوجو عام طور پر وراثت کے ذریعے سے ملتا ہے ۔
اور تحفہ وھدیہ کے ذریعے مال حاصل ہو لیکن وہ قیمتی نہ ہو ۔
اور مہر و عوض طلاق خلع جو شوہر کو بیوی کی طرف سے ملے تو ان تمام حالتوں میں خمس واجب نہیں ہے ۔ البتہ سال بھر کے اخراجات جدا کرنے کے بعد ہو ۔
اور جب کوئی شخص بغیر کسب وکاروبار کے علاوہ پہلی منفعت حاصل کرے تووہی اس کا خمس کا سال ہو گا اور وہ شخص جو کسب وکاروبار کو شروع کرئےاورمنفعت حاصل ہوتے ہی اس کا مال خمس کے متعلق ہو جائے گااگرچہ خمس کو سال کے آخر تک دینا اس کے لیے جائز ہے کیونکہ شارع نے اس میں نرمی و ارفاق کیا ہے ۔
بچے اور پاگل کے مال پر خمس واجب نہیں ہے ۔
دلائل:
۱ ۔ فائدہ حاصل کرنے کے بعد سالانہ اخراجات کو نکال کر خمس دیا جاتا ہے جس پر دلیل آیت کا اطلاق تر دلالت کرنا اور بعض روایات جیساکہ سماعہ کی موثق روایت ہے جو پہلے گذر چکی ہے ۔
احتمال یہ دیتے ہیں کہ خمس اس فائدے کے ساتھ خاص ہے جوکہ کسب وکاروبار کے ذریعے سے حاصل ہو یا اس احتمال کا دعوی اجماع ہے یا اس دلیل کے ساتھ ہےکہ مسئلہ ابتدائی ہے کیونکہ اگر مطلق فائدے میں واجب ہو تو یہ مشہور ہے اور یا مشہورنے سماعہ جیسی روایت سے اعراض کیا پس روایت سماعہ حجیت سے ساقط ہو جاتی ہے اور یااس کے علاوہ بھی دلیلیں ہیں ۔
یہ اس طرح کے احتمال میں اشکال و تامل کی علت یہ ہے کہ قدماء کی عبارت میں کسب و کاروبار پر اختصاص نہیں پایا جاتا ہے بلکہ کسب کاروبار کو بطور باب مثال ذکر کیا گیا ہے جیساکہ پیداوار کی راہ سے اور تجارت سے اور زراعت سے فائدہ حاصل ہو البتہ بعض قدماء کی عبارت میں تصریح ہے کہ تمام فوائد پر خمس واجب ہے۔
۲ ۔ اگر میراث کے ذریعے مال حاصل ہوجو عام طور پر وراثت کے ذریعے سے ملتا ہے اور وہ ھدیہ(خمس کے واجب ہونے کے شرائط ) جو ذکر ہو چکا ہےتو ان پر خمس نہیں ہے جس پر دلیل علی بن مھزیار کی حضرت امام محمدتقی علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
"فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَب ۔۔۔۔۔"(۱۲۲)
ترجمہ :"خدا تم پ رحم کرے غنائم اور فوائد سے مراد وہ غنیمت ہے جسے آدمی حاصل کرتا ہے ، یا وہ فائدہ ہے جو آدمی کماتا ہے یا کسی آدمی کا کسی کو کوئی قابل قدر تحفہ و ہدیہ دینا یا میراث جس کے حاصل ہونے کا گمان )نہ ہو ۔۔۔"
۳ ۔ مہر و عوض طلاق خلع سے بھی خمس کو استثناء ہے مہر و عوض طلاق خلع جو شوہر کو بیوی کی طرف سے ملے تو ان دونوں صورتوںمیں خمس واجب نہیں ہےاورمھر اور عوض خلع پر فائدہ صدق نہیں کرتا ہے کیونکہ عورت جو مھر لیتی ہے وہ خود آپ نے ہاتھوں سے شوہر کے اختیار میں رکھتی ہے اور عوض خلع شوہر کی طرف سے حقوق زوجیت میں کوتاہی ہے جوکہ شوہر کے لیے ثابت ہے پس واقع میں عورت مھرمیں ایک چیز کو دیناہے اور دوسرے چیز کو پا لینا ہے اور اسی طرح عوض خلع میں بھی ہے ۔
۴ ۔ اور یہ ضروری کہ سال بھر کا خرچہ جدا کیا جائے جس پر دلیل مکاتبہ ہمدانی کی روایت دلالت کرتی ہے جو کہ گذر چکی ہے اور بہت سی روایات اس کی تائید کرتی ہیں اس کا حکم اخراجات کے علاوہ ہے جو کہ فائدے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ مال جو زندگی کے اخراجات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے اور وہ دلیل کے لیے محتاج نہیں ہے کیونکہ اس پر فائدہ ومنفعت صدق نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ سال کے اخراجات سے زیادہ ہوں ۔
۵ ۔ ضروری ہے کہ پہلے سال بھر کا خرچہ نکال لیا جائے اس کے بعد خمس کو ادا کیا جائے کیونکہ یہاں پر اطلاق مقامی دلالت کرتی ہے جوکہ سال کا خرچہ نکالنا ہے کیونکہ معمولا روزمرہ زندگی میں لوگ سال بھر کے خرچے کا حساب کرتے ہیں اور اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ مہینہ میں یا روزانہ خرچے کا حساب کرتے ہیں اور زمانے حاضر میں اکثر ممالک میں بھی سال بھر کے خرچے کا حساب کیا جاتا ہے اور روایت میں کلمہ مؤونہ کا استعمال ہمطلق ہوا ہے پس ضروری ہے کہ عرف کے مطابق سال بھر کے اخراجات نکالے جائیں ۔
۶ ۔ خمس کاسال شروع ہونے کے لیے دلیل جو ذکر ہو چکی ہے وہ قول مشہور ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کسب وکاروبار کرتے ہیں جونہی وہ تجارت شروع کرتے ہیں وہی ان کا خمس سال ہے اور ہر سال اسی تاریخ کو جوکاروبار شروع کیا تھا تو خمس واجب ہے چاہے اس میں اس کو منفعت حاصل ہو یا نہ ہو ۔
اور وہ لوگ جو مزدوری وغیرہ کرتے ہیں تو جونہی ان کو منفعت حاصل ہو تو وہی ان کا خمس کا سال ہو گا اور ہر سال اسی تاریخ کو مال زائد پر خمس واجب جائے گی ۔
۷ ۔ اور منفعت حاصل ہوتے ہی مال پرخمس واجب ہو جائے گی جس پر دلیل آیت غنیمت ہے اور روایت سماعہ بھی اس پر دلالت کرتی ہ جوکہ پہلے گذر چکی ہے کیونکہ ظاہری تعبیر قرآن ( فان للہ خمسہ ) اور روایت ( ففیہ الخمس ) خمس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے لیکن جب اس پر فائدہ صدق کر
خمس کو تاخیر سے دینا ایک سال تک جائز ہے اور یہ شارع کی طرف سے سہولت ونرمی ہے جوکہ سالانہ اخراجات کو نکالنے کے بعد ہے اور یہ اخراجات ایک دفعہ حاصل نہیں ہوتے ہیں بلکہ اخراجات بطور تدریجی حاصل ہوتے ہیں یعنی یہ اخراجات فوری طور پر حاصل نہیں ہوتے ہیں اور اس کے امکان کے بارے میں پہلے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ۔ پس اخراجات کا تدریجی حاصل ہونے کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ خمس کو تاخیر سے دینا جائز ہے
{خمس کے ادا کرنے میں کچھ باقی نہیں رہا کہ اگر خمس کو فوری ادا کیا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے بلکہ بعض نے مستحب جانا ہے }
۸ ۔ اگر بچے اور پاگل کے پاس مال ہو اور ان کے سالانہ اخراجات سے زیادہ ہے تو ان کے مال پر خمس واجب نہیں ہے اور اے پر دلیل حدیث رفع ہے جس میں ان کے حکم سے قلم اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ حکم تکلیفی ( خمس کا دینا واجب ) ان سے اٹھا لیا ہے بلکہ حکم وضعی ( ان کے مال پر خمس ) کو بھی ان سے اٹھالیا گیا ہے ۔
حدیث رفع حکم تکلیفی کے ساتھ خاص ہے پس ان کے مال پر خمس واجب ہے ہاں لیکن تکلیف کے عمومی شرائط نہیں ہیں تو اس صورت میں ان کو خمس دینا واجب نہیں ہے پس ضروری ہے کہ ان کے سرپرست و ولی خمس کو ادا کرے یا اس صورت میں جب عاقل یا بالغ ہو جائیں تو پھر خمس کو خود ادا کریں لیکن یہ بھی قاعدہ برات کی وجہ سے منتقی ہے ۔
خمس کو تقسیم کرنے کی کیفیت
مشہور کہتے ہیں کہ خمس کو چھ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن میں سے تین حصے امام علیہ السلام کے ہیں اور تین حصےسادات کے ہیں اور ساتھ یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ دنیا کے تمام سادات میں تقسیم کیا جائے اور سھم امام علیہ السلام کے مال کے استعمال کرنے کی کیفیت میں اختلاف پایا جاتاہے ۔
دلائل :
۱۔ یہ کہ خمس چھ حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اس قول کےخلاف جو کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ خمس پانچ حصّوں میں تقسیم ہوتا ہے انھوں نے سھم خدا کوآیت غنیمت کے ذریعے سے حذف کیا ہے اورہاں یہ بات اس بناء پر درست ہو گی جب غنیمت کو مطلق فائدہ جانا جائے تو یہ مسئلہ روشن ہےاور اگربناء جنگی غنیمت کے ساتھ مختص ہو تو اس حالت میں کیونکہ آیت میں غیر جنگی غنیمت کے استعمال کا ذکر نہیں ہوا ہے اور یہ ذکر نہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا استعمال کرنا مطلق غنیمت پرہے اور اگر اس طرح نہ ہوتا تو امام علیہ السلام کے لیے لازمی ہوتا کہ لوگوں کے لیے بیان کرتے اور اس کے استعمال کی طرف اشارہ کرتے ۔
۲ ۔ خمس کے تین حصّے امام علیہ السلام کے لیے ہیں جس پر دلیل احمد بن محمد بن ابی نصر کی حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی صحیح روایت ہے :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ) فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ، وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ ، أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى ؟ كَذَلِكَ الْإِمَامُ .(۱۲۳)
ترجمہ :"{ حضرت شیخ کلینی علیہ الرحمہ آپ نی سند کے ساتھ }احمد بن محمد ابو نصر سے روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے خدا وندعالم کے اس ارشاد کے بارے میں پوچھا گیا " واعلمو انما ۔۔۔۔ "عرض کیا : جو خدا کا حصّہ ہے وہ کس کے لیے ہے ؟ فرمایا : وہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ کے لیے ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے ہے وہ امام علیہ السلام کے لیے بھی ہے پھر عرض کیا کہ اگرمستحقین کا ایک گروہ زیادہ ہو اور دوسرا کم تو پھر کیا کیا جائے ؟فرمایا : یہ امام علیہ السلام کے صواب دید پر منحصر ہے تم خیال نہیں کرتے کہ حضرت رسول خد ا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے ؟ کیا وہ آپ نی صوابدید کے مطابق نہیں خرچ کیا کرتے تھے ؟اسی طرح امام علیہ السلام بھی آپ نی صوابدید کے مطابق خرچ کریں گے "
پس اسی بنا پر دور حاضر میں تمام اخماس حضرت امام زمان اراحنا لہ الفداء کو دیا جائے ۔
مسئلہ کا حکم واضح و روشن ہے اگر امام علیہ السلام کی ملکیت بناء کو ملکیت شخصی جانےتاہم اگر ملکیت کو منصب و مکان جانے تو تب بھی امام علیہ السلام کے لیے ملکیت ثابت ہے کیونکہ امام علیہ السلام کی ملکیت من حیث تقییدی نہ کہ تعلیلی ، جسطرح کہ روایات میں امام علیہ السلام کی تعبیر کی گئی ہے ، کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وجہ سے نہیں ہےجس طرح چاہے اس میں تصرف کرئےپس ملکیت شخصی ومنصبی کی تقدیر کی بناء پر فقیہ نائب امام علیہ السلام کی بنیاد پر جو کہ صاحب امام زمان علیہ السلام ہیں تو اس مال میں فقیہ دخالت و تصرف کر سکتا ہے ۔
۳ ۔ اور قول مشہور کے مطابق تین حصّے آخری سادات و بنی ہاشم کے لے مخصوص ہیں جو کہ اہل سنت کے قول(۱۲۴) کے برعکس ہے اور شاید جس قول کی نسبت ابن جنید(۱۲۵) کی طرف دی گئی ہے شاید وہی قول ہو اس شرط کے ساتھ کہ سادات و بنی ہاشم بے نیاز و محتاج ہوں اس امر و حکم کی ضرورت کے مطابق دعوی کیا گیا ہے کہ ان کا موجودہونا دلیل کے محتاج نہیں ہے ۔
بعض روایات جن کی سند ضعیف(۱۲۶) ہیں وہ بھی اس امر پر دلالت کرتی ہیں اور سند کا ضعیف ہونا اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ اس کی ضرورت ہے ۔
۴ ۔ لیکن ضرورت کیوں نہیں ہے کہ خمس تمام اصناف میں مساوی تقسیم ہو کیونکہ خمس کی آیت تقسیم کرنے کو بیان و ظاہر کر رہی ہے نہ کہ ان کی ملکیت کو ، اس پر دو دلیلیں ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
ا۔بے شک آیت میں کلمہ "الیتامی " "المساکین " جمع اور الف ولام کی صورت میں آئیں ہیں اور ظاہری خکم یہ ہے کہ یہ تمام یتیموں اور مسکینوں کو شامل حال ہے یعنی ان کے درمیان مساوی سے تقسیم کیا جائے اگرچہ اس طرح سے ممکن ہو یہ احتمال نہیں دیتے ہیں کہ خدا وند عالم کا بھی یہی ارادہ ہو ۔
ب۔ تو اس صورت میں سھم ابن سبیل کو محفوظ رکھنا لازمی آتا ہے اگرچہ ابن سبیل شھر میں نہ ہو اور یہ احتمال بھی نہیں دے سکتے ہیں ۔
پس ان دو قرینوں کی بناء پر واضح ہو جاتا ہے کہ خمس کی آیت استعمال کرنے کو بیان کر رہی ہے نہ کہ ان کی ملکیت کو ۔
زمان غیبت میں سھم امام علیہ السلام کے استعمال کرنےکے بارے میں صاحب حدائق(۱۲۷) نے چودہ اقوال ذکر کیئے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو نقل کریں لیکن وہ اقوال جوبعض متاخرین کے درمیان معروف ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں ۔
سھم امام علیہ السلام کا مسئلہ شک کی حالت میں ہے کہ آیا سھم امام علیہ السلام کو دفن کیا جائے یا امانت دینا وصیت کے ذریعے سے نسل در نسل ،اور بھی احتمالات میں جن کو صاحب حدائق نقل کیا ہے اور یہ سب احتمالات سھم امام علیہ السلام کے تلف ہو نے کے موجب بنتے ہیں اور ان کے تلف ہونے پر ہمارے پاس کو ئی دلیل عقلی نہیں ہے تو اس صورت میں ہم مجبور ہیں کہ سھم امام علیہ السلام اس طرح استعمال کریں کہ امام علیہ السلام راضی ہو جائیں اور یہ رضایت حاصل نہیں ہوتی مگر دین اسلام کی تقویت کے لیے یا وہ لوگ جو دین اسلام کی تقویت کے لیے کوشاں ہیں اورسھم امام علیہ السلام کے استعمال کی روشن ترین مصادیق حوزہ علمیہ ہے کہ ان کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہوتی ہے ۔
لازمی ہے کہ سھم امام علیہ السلام کا استعمال زیر نظر مجتہد و فقیہ ہو تاکہ سھم امام علیہ السلام اس کو دیا جائے یا اس سے اجازت لی جائے اور اجازت لینے کا ملازمہ اس ضرورت کی بناء پر ہے کہ لوگوں کی مرجعیت سے رابطہ ہو اور یا اس دلیل کی بناء پر ہو کہ وہ شخص امام علیہ کی طرف سے نائب ہے اگرچہ ہمارے پاس فقیہ کے بارے میں کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ لازمی طور پر اس کو دیا جائے ہاں حد اقل یہ احتمال دے سکتے ہیں اور یہ احتمال دینا کافی ہے کہ خمس کے اموال میں کسی شخص کا تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر اس صورت میں اس کے لیے جائز ہو گا جب اس کو فقیہ کی رضایت کے بارے میں قطع و یقین ہو ۔
___________________
۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج ۱ ،ص ۱۳،باب ۱
۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱ ۳،باب ۱
۳ ۔ سورہ حج ایت ۷۸
۴ ۔ سورہ بقرہ ایت ۱۸۷
۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۹ ۳،باب ۴ ، حدیث ۱
۶ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱۰۳،باب ۳۵، حدیث ۱
۷۔ و کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۶۳،باب۱۶ ، حدیث ۲
۸ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص ۶۴باب ۱۶ ، حدیث ۵
۹ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۸،باب ۱۳ ، حدیث ۴
۱۰ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۳۴،باب ۲ ، حدیث ۴
۱۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۶۹،باب ۲۲ ، حدیث ۱
۱۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۴۳،باب ۶ ، حدیث ۱
۱۳ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۴۲،باب ۵ ، حدیث ۴
۱۴ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۴۱،باب ۵ ، حدیث ۲
۱۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص ۸۶،باب ۲۹ ، حدیث ۱
۱۶ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۸۸ ،باب ۲۹ ، حدیث ۸
۱۷ ۔ سورہ توبہ ایت نمبر ۵۴
۱۸ ۔اس آیت سے (انھم کفروا باللہ و رسولہ) عمومیت سمجھ میں آتی ہے اگرچہ ایت منافقین کے بارے میں ہے لیکن کفار کو بھی شامل ہوجاتی ہے کیونکہ جب ان سے نفقہ قابل قبول نہیں ہے تو بطریق اولی کفار سے روزہ قابل قبول نہیں ہے پس ثابت ہوا کہ اسلام روزہ کے صحیح ہونے میں شرط ہے ۔
۱۹ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ،ج ۱ ،ص۰ ۱۲،باب ۲۹ ، حدیث ۵
۲۰ ۔ سورہ مائدہ آیت ۲۷
۲۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص ۲۲۸،باب ۲۵ ، حدیث ۲
۲۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۲۲۹،باب ۲۶ ، حدیث ۱
۲۳ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۲۳۲،باب ۲۸ ، حدیث ۴
۲۴ ۔ سورہ بقرہ ایت نمبر ۱۸۵
۲۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۲۰۰،باب ۱۱ ، حدیث ۱
۲۶ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱۸۴،باب ۴ ، حدیث ۱
۲۷ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱۸۰،باب ۲ ، حدیث ۵
۲۸ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱۸۶،باب ۵ ، حدیث ۳
۲۹ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱۸۷،باب ۵ ، حدیث ۱۰
۳۰ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱۹۱،باب ۶ ، حدیث ۶
۳۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱۹۰،باب ۶ ، حدیث ۳
۳۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱۸۹،باب ۶ ، حدیث ۱
۳۳ ۔ سورہ بقرہ ایت نمبر ۱۸۵
۳۴ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۲۲۰،باب ۲۰ ، حدیث ۳
۳۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۲۱۸،باب ۱۹ ، حدیث ۱
۳۶۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۳۱،باب ۱ ، حدیث ۱
۳۷ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۰،باب ۹ ، حدیث ۱
۳۸ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۲۲۶،باب ۴ ۲ ، حدیث ۱
۳۹ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۵ ۱ ،ص۳۶۸،باب ۵۶ ، حدیث ۱
۴۰ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۶۱،باب ۱۵ ، حدیث ۱
۴۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۴۵،باب ۸ ، حدیث ۱
۴۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۴۸،باب ۸ ، حدیث ۹
۴۳ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۱۱۵،باب ۴۴ ، حدیث ۳
۴۴ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۵۰،باب ۷ ، حدیث ۳
۴۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۵۰،باب ۳ ، حدیث ۱
۴۶ ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۲۵
۴۷ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۳۴،باب ۱ ، حدیث ۳
۴۸ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۴۵،باب ۴ ، حدیث ۵
۴۹ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۴۰،باب ۳ ، حدیث ۸
۵۰ ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۸۶
۵۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۴۵،باب ۵ ، حدیث ۱
۵۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۵۴،باب ۱۰ ، حدیث ۱
۵۳ ۔ کتاب میں فضلاء آیا لیکن روایت میں فضیل ذکر ہوا ہے ۔
۵۴ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۵۵،باب ۸ ، حدیث ۴
۵۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۶۲،باب ۹ ، حدیث ۴
۵۶ ۔ اگر کوئی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن علما اس پر عمل کرتے آئے ہیں تو علما کا عمل کرنا اس روایت کی ضعف کو پورا کرے گا اسی کا نام قاعدہ انجبار ہے۔ اس قاعدہ کو فقہ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے بہت سے ضعیف روایتیں اسے طریقے سے قابل عمل بن جاتے ہیں۔ ۵۷ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۰ ۱ ،ص۴۵،باب ۴
۵۸ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج ۹ ،ص۹۲،باب ۴ ، حدیث ۳
۵۹ ۔سورہ توبہ ایت نمبر ۱۰۳
۶۰ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج ۹ ،ص۹۵،باب ۵ ، حدیث ۷
۶۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج ۹ ،ص۱۰۸،باب ۲ ، حدیث ۱
۶۲ ۔ کتاب میں فضلاء آیا لیکن روایت میں فضیل ذکر ہوا ہے ۔
۶۳ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۱۱،باب ۲ ، حدیث ۶
۶۴ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۱۵،باب ۴ ، حدیث ۱
۶۵ ۔ کتاب میں فضلاء آیا لیکن روایت میں فضیل ذکر ہوا ہے۔
۶۶ عاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة؛ ج۹، ص: ۱۱۲
۶۷ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۱۵،باب ۴ ، حدیث ۱
۶۸ ۔ کتاب میں فضلاء آیا لیکن روایت میں فضیل ذکر ہوا ہے۔
۶۹ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۱۶،باب۶ ، حدیث ۶
۷۰ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۱۷،باب ۶ ، حدیث ۲
۷۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۲۰،باب ۷ ، حدیث ۵
۷۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۲۱،باب ۸ ، حدیث ۱
۷۳ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۳۸،باب ۱ ، حدیث ۵
۷۴ ۔ کتاب میں فضلاء آیا لیکن روایت میں فضیل ذکر ہوا ہے ۔
۷۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۴۱،باب ۱ ، حدیث ۱۳
۷۶ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۴۵،باب ۲ ، حدیث ۱۰
۷۷ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۵۵،باب ۸ ، حدیث ۲
۷۸ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۷۶،باب ۱ ، حدیث ۵
۷۹ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۱۷۸،باب ۱ ، حدیث ۱۰
۸۰ ۔ ۶۰ صاع کی مقدار تقریبا ۱۶۹.۸۲۷۸۴ کلو گرام ۔
۸۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۱۷۷،باب ۱ ، حدیث ۷ ۔
۸۲ ۔ ایک وسق کی مقدار ساٹھ صاع ہے جو کہ تقریبا ۱۶۹.۸۲۷۸۴ کلو گرام ہے اس حساب سے پانچ وسق کی مقدار ۸۴۹.۱۳۹۲ کلو گرام ہے۔
۸۳ ۔سورہ التوبہ ایت نمبر ۶۰
۸۴ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۲۱،باب ۱ ، حدیث ۲
۸۵ ۔ کتاب ،اصول کافی مؤلف ، شیخ کلینی ، ج ۲ ص ۴۱۱
۸۶ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۲۱۶،باب ۳ ، حدیث ۱
۸۷ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۲۴۱،باب ۱۳ ، حدیث ۱
۸۸ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۲۷۵،باب ۳۲ ، حدیث ۶
۸۹ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۲۷۴،باب ۲ ۳ ، حدیث ۵
۹۰ ۔ حدائق ناظرہ ج ۱۲ ص ۳۹۶
۹۱ ۔ جواھر الکلام ج ۱۶ ص ۱۰۵
۹۲۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۰۷،باب ۵۲ ، حدیث ۲
۹۳۔ قاعدہ ید ایک فقہی قاعدہ ہے جس کے مطابق آدمی اس چیز کا مالک بنتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہو۔ جب کوئی چیز یا مال کسی کے قبضے میں ہو دوسروں کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ قاعدہ اثبات مالکیت کی دلائل میں سے ایک ہے۔
۹۴ ۔سورہ الاعلی ایت نمبر ۱۴ ' ۱۵
۹۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۱۸،باب ۱ ، حدیث ۵
۹۶۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۴۵،باب ۱
۹۷ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۲۱،باب ۲ ، حدیث ۱
۹۸ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۲۴،باب ۳ ، حدیث ۲
۹۹ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۵۲،باب ۱۱ ، حدیث ۱
۱۰۰ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۵۶،باب ۱۳ ، حدیث ۲
۱۰۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۵۷،باب ۱۳ ، حدیث ۴
۱۰۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۲۷،باب ۵ ، حدیث ۲
۱۰۳ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۳۵،باب ۶ ، حدیث ۸ ،الوافی ج۱۰ ص ۲۵۳
۱۰۴ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۳۶،باب ۶ ، حدیث ۱۱
۱۰۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۴۳،باب ۸ ، حدیث ۱
۱۰۶ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۳۴۷،باب ۹ ، حدیث ۶
۱۰۷ ۔ سورہ انفال ایت نمبر ۴۱
۱۰۸ ۔ لغت لسان عرب ۔ مادہ (غنم ) کسرہ کے ساتھ
۱۰۹ ۔ سورہ نساء ایت نمبر ۹۴
۱۱۰ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۴۹۲،باب ۳ ، حدیث ۳
۱۱۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۴۹۵،باب ۴ ، حدیث ۱
۱۱۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۴۹۳،باب ۳ ، حدیث ۵
۱۱۳ ۔ جوکہ تین راویوں "بزنطی ، صفوان اور ابن ابی عمیر "میں سے ایک بزرگ راوی ہے بلکہ ان پر اصحاب کی اجماع ہے جس کی وجہ سے راوی کے اعتبار کی حد کو دو بالا کر دیتا ہے {اور شیخ طوسی نے ان راویوں کو "بزنطی و صفوان اور ابن ابی عمیر "سے تعبیر لا یردون ولا یرسلون الّا عن ثقة کیا ہے۔
۱۱۴ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۴۹۹،باب ۸ ، حدیث ۱
۱۱۵ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۴۹۴،باب ۳ ، حدیث ۷
۱۱۶ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۴۹۶،باب ۵ ، حدیث ۲
۱۱۷ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۴۹۴،باب ۳ ، حدیث ۶
۱۱۸ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۵۰۵،باب ۹ ، حدیث ۱
۱۱۹ ۔ جواہر الکلام ج ۱۶ ص ۴۵
۱۲۰ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۵۰۳،باب ۸ ، حدیث ۶
۱۲۱ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۵۰۱،باب ۸ ، حدیث ۴
۱۲۲ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۵۰۱،باب ۸ ، حدیث ۵
۱۲۳ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۵۱۹،باب ۲ ، حدیث ۱
۱۲۴ ۔ کتاب ، المحّلی ، ج ۷ ص۳۲۷ ، کتاب ، المغنی ، ج ۶ ص۴۱۳
۱۲۵ ۔ کتاب ، جواھر الکلام ، ج ۱۶ ص ۸۸
۱۲۶ ۔ کتاب ،وسائل الشیعہ ۔ مؤلف ، محمد بن حسن حرعاملی ج۹ ،ص۵۰۹،باب ۱ ، حدیث ۲
۱۲۷ ۔ کتاب ، حدائق الناضرہ ، ج۱۲ ص۴۳۷
فہرست
انتساب! ۴
مقدمہ ۵
کتاب کا تعارف: ۵
مؤلف کا تعارف: ۵
ضرورت ترجمہ: ۵
کتاب کے مشتملات: ۶
کتاب صوم ۷
روزہ کو باطل کرنے والی چیزیں ۷
روزہ کےصحیح ہونے کی شرائط: ۱۷
مذکورہ احکام کےدلائل : ۱۷
روزےکے عام احکام ۲۷
دلائل: ۲۷
اعتکاف کے احکام ۳۳
دلائل ۳۳
لغت میں اعتکاف کی تعریف: ۳۳
اصطلاح میں اعتکاف کی تعریف: ۳۳
اعتکاف صرف مسجد میں ۳۴
اعتکاف کی پہلی شرط ۳۵
اعتکاف کی دوسری شرط ۳۵
اعتکاف کی تیسری شرط ۳۵
اعتکاف کی چوتھی شرط ۳۶
اعتکاف کی پانچویں شرط ۳۷
اعتکاف کی چھٹی شرط ۳۷
اعتکاف کی ساتویں شرط ۳۸
کتاب زکات ۳۹
زکات کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟ ۳۹
دلائل: ۳۹
زکات کے عام شرائط : ۴۰
زکات واجب ہونے کی شرائط اور ان کے دلائل ۴۰
۱۔ بالغ ہو ۴۰
۲۔عاقل ہو ۴۱
۳۔ آزاد ہو ۴۱
۴ ۔ مالک ہو ۴۲
۵۔تصرف کی قدرت ۴۳
زکات کا نصاب : ۴۴
حیوانات پر زکات واجب ہونے کی شرائط ۴۴
ا۔ اونٹ کے بارہ نصاب پائے جاتےہیں ۔ ۴۴
ب۔ گائے کے دو نصاب ہیں : ۴۵
ج۔ بھیڑکے پانچ نصاب ہیں : ۴۵
دلائل ۴۵
سونے کا نصاب ۵۰
دلائل ۵۰
چاندی کا نصاب ۵۲
غلّات پر زکات واجب ہونے کے شرائط ۵۳
دلائل ۵۴
غلات پر زکات واجب ہونے کی مقدار ۵۵
اشکال : ۵۶
زکات کے مستحقین ۵۷
زکات کے مصرف اور دلائل ۵۷
۱۔۲ فقیر اور مسکین ۵۸
مسکین اور فقیر میں فرق ۵۸
۳ ۔ عاملین ۵۹
۴ ۔مولفۃ قلوبہم ۵۹
۵ ۔غلام ۶۰
۶ ۔ مقروض ۶۰
۷ ۔اللہ کی راہ ۶۰
۹ ۔ ابن سبیل کو دینا ۔ ۶۱
مستحقین کے اوصاف ۶۱
۱۔ ایمان: ۶۱
۲ ۔ زکات کے مستحق کو اہل معصیت نہیں ہونا چائیے ۶۱
۳ ۔واجب النفقہ نہ ہو ۶۱
۴ ۔ غیر سید ہو ۶۲
دلائل ۶۲
زکات کے عام احکام ۶۶
دلائل ۶۶
زکات فطرہ ۷۰
دلائل ۷۰
زکات فطرہ واجب ہونے کی شرائط اور دلائل ۷۱
۱۔۲ عقل اور بلوغ ۷۱
۳ ۔ استطاعت ۷۱
۴ ۔ آزاد ہو ۷۲
۵ ۔ پاگل نہ ہو ۷۲
ایک مسئلہ ۷۲
فطرہ نکالنے کا وقت ۷۳
مہمان کا فطرہ ۷۵
فطرہ کی مقدار ۷۵
فطرہ کا مصرف ۷۷
کتاب خمس ۷۸
جن چیزوں پر خمس واجب ہے ۔ ۷۸
۱ ۔ جنگ کا مال غنیمت ۷۸
۲ ۔ معدن ۷۸
۳ ۔ گنج ۷۸
۴ ۔غواصی کے جواہرات ۷۸
۵ ۔ حلال مال جو حرام سے مخلوط ہو جائے ۷۸
۶ ۔ وہ زمین جس کو کافر ذمی مسلمان سے خریدے ۔ ۷۸
۷ ۔ سالانہ زندگی کے اخراجات سے زیادہ مال ہو ۔ ۷۸
دلائل: ۸۶
خمس کو تقسیم کرنے کی کیفیت ۸۸
دلائل : ۸۹