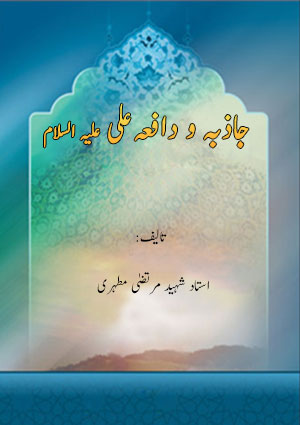یہ کتاب برقی شکل میں نشرہوئی ہے اور شبکہ الامامین الحسنین (علیہما السلام) کے گروہ علمی کی نگرانی میں اس کی فنی طورپرتصحیح اور تنظیم ہوئی ہے
نام کتاب: جاذبہ و دافعہ علی علیہ السلام
تالیف: استاد شہید مرتضیٰ مطہری
ترجمہ: غلام حسین سلیم
بسم الله الرحمن الرحیم
پیش لفظ
امیر المومنین علی علیہ السلام کی عظیم اور ہمہ گیر شخصیت اس سے کہیں زیادہ وسیع اور پہلو دار ہے کہ کوئی اس کے تمام پہلوؤں کو مکمل طور پر سمجھ سکے اور فکر کے گھوڑے دوڑائے۔ ایک فرد زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک یاچند مخصوص اور محدود پہلوؤں کو مطالعہ اور غور و فکر کے لیے منتخب کرے اور اسی پر قانع ہو۔
اس عظیم شخصیت کے وجود کے مخٹلف پہلوؤں میں سے ایک مختلف انسانوں پراس کا مثبت یا منفی اثر ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا وہ طاقتور ''جاذبہ'' اور '' دافعہ '' ہے، جو اب بھی اپنا بھرپور اثر دکھاتا ہے اوراس کتاب میںاسی پہلو پر گفتگو ہوئی ہے ۔
انسانی روح و جان میں رد عمل پیدا کرنے کے نقطہئ نظر سے افراد کی شخصیت یکساں نہیں ہے۔ جس نسبت سے شخصیت حقیر تر ہوتی ہے اتنا ہی کمتر خیالات کو وہ اپنی طرف کھینچتی اور دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتی ہے اور جتنی شخصیت عظیم تر اور طاقت ور ہوتی ہے اتنی ہی فکر انگیز اور رد عمل پیدا کرنے والی ہوتی ہے خواہ رد عمل موافق ہو یا مخالف۔
فکر انگیز اور رد عمل پیدا کرنے والی شخصیات کا ذکر زبانوں پر زیادہ آتا ہے۔ بحث و مباحثہ اور اختلافات کا موضوع بنتی ہیں۔ شاعری، نقاشی اور دیگر فنون لطیفہ کا افتخار بنتی ہیں۔ داستانوں اور کہانیوں کاہیرو قرار پاتی ہیں۔ یہی تمام چیزیں ہیںجو علی علیہ السلام کے بارے میں بہ درجہئ اتم موجود ہیں۔ اس اعتبار سے ان کا کوئی رقیب ہی نہیں یا بہت کم ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد ابن شہر آشوب مازندرانی جو ساتویں صدی کے اکابر علمائے امامیہ میں سے ہیں، جب اپنی مشہور کتاب ''مناقب '' تالیف کر رہے تھے، اس وقت ان کے کتب خانے میں مناقب کے نام سے ایک ہزار کتابیں تھیں جو سب علی علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی تھیں۔
اس ایک مثال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولا علی(ع) کی بلند شخصیت نے تاریخ کے دھارے میں کتنے ذہنوں کو مشغول رکھا!
علی علیہ السلام اور ان تمام لوگوں کا جو حق کی روشنی میں منور ہیں، بنیادی امتیاز یہ ہے کہ وہ ذہنوں کو مشغول رکھنے اور افکار کو سرگرم کر نے کے علاوہ دلوں اور روحوں کو روشنی، حرارت، عشق و مستی اور ایمان و استحکام بخشتے ہیں۔
سقراط، افلاطون، ارسطو، بوعلی سینا، ڈیکارٹ جیسے فلسفی بھی افکار کو تسخیر کرنے اور ذہنوں کو سرگرم کرنے والے سپوت ہیں۔
علاوہ ازیں سماجی انقلابات کے رہنماؤں نے خاص کر آخری دو صدیوں میں اپنے پیروکاروں میں ایک طرح کا تعصب پیدا کیا ہے۔ مشائخ عرفان اپنے پیروکاروں کو غالباً '' تسلیم '' کے اس مرحلے تک پہنچا دیتے ہیں کہ اگر پیر مغاں اشارہ کر دے تووہ جائے نماز کو مے سے رنگیں کر دیں۔ لیکن ان میں سے کسی میں بھی گرمی و حرارت کے ساتھ ساتھ وہ نرمی لطافت اور خلوص و رقت نہیں دیکھتے جس کا نشان تاریخ میں علی(ع) کے پیروکاروں میں ملتا ہے۔ اگر صفویوں نے درویشوں کا ایک لشکرجرار منظم کرکے مؤثر جنگیں لڑیں تو ایسا علی(ع) کے نام پر کیا نہ کہ اپنے نام پر۔
معنوی حسن اور خوبصورتی جو خلوص و محبت پیدا کرتی ہے اور بات ہے اور رہنمائی، مفاد اور زندگی کی مصلحتیں جو سماجی رہنماؤں کا اثاثہ ہےں یا عقل و فلسفہ جو فلسفیوں کا اثاثہ ہیں یا اقتدار و تسلط کا اثبات جو عارف کا اثاثہ ہے، بالکل دوسری بات ہے۔
مشہور ہے کہ بوعلی سینا کے شاگردوں میں سے ایک اپنے استاد سے کہا کرتا تھا کہ اگر آپ اس غیر معمولی فہم و فراست کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھیں تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے اور بو علی سیناخاموش رہتے۔ یہاں تک کہ سردیوں کے موسم میں دونوں کسی سفر پر ساتھ تھے۔ صبح کے قریب بو علی سینا نیند سے بیدار ہوئے، شاگرد کو جگایا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے تھوڑا سا پانی لا دو۔ شاگرد نے سستی کی اور بہانے تراشنے لگا۔ ہر چند بو علی نے اصرار کیا لیکن شاگرد اس سردی میں گرم بستر چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اسی وقت گلدستہ اذان سے موذن کی صدا بلند ہوئی۔ اللّٰہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللّٰہ۔ اشہد ان محمدا رسول اللّٰہ۔ بو علی نے اپنے شاگرد کو جواب دینے کے لیے موقعہ غنیمت جانا۔ کہا کہ تو جو کہتا تھا کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھوں تولوگ میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔
اب دیکھ میری موجودگی میں میرا حکم تجھ پر نہیں چلتا جو سالہا سال تک میرا شاگرد رہا اور میرے درس سے فائدہ اٹھایا کہ تو ایک لحظہ کے لیے اپنا گرم بستر چھوڑے اورمجھے پانی پلائے، لےکن یہ مؤذن چار سو سال کے بعد بھی پیغمبر (ص) کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس بلندی پر جا کر خدا کی وحدانیت اور آپ (ص) کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔
ببین تفاوتِ رہ از کجا است تا بہ کجا
جی ہاں! فلسفی شاگرد پیدا کرتے ہیں نہ کہ پیروکار۔ سماجی رہنما متعصب پیروکار پیدا کرتے ہیں نہ کہ مہذب انسان۔ اقطاب و مشائخ عرفان ارباب تسلیم پیدا کرتے ہیں نہ کہ سرگرم مؤمن مجاہد۔
علی(ع) میں فلسفی، انقلابی رہنما، پیر طریقت اور پیغمبروں جیسی خصوصیات یکجا ہیں۔ علی(ع) کا مکتب، مکتبِ عقل و فکر بھی ہے اور مکتبِ انقلاب و ارتقاء بھی۔ مکتب تسیلم ہونے کے ساتھ نظم و ضبط بھی اور مکتب حسن و زیبائی اور جذبہ و حرکت بھی۔
علی علیہ السلام دوسروں کے لیے ایک امام عادل ہونے اور دوسروں کے بارے میں عدل و انصاف کا چلن رکھنے سے پہلے خود اپنی ذات میں ایک متعادل اور متوازن وجود تھے جن میں تمام انسانی کمالات یکجا تھے۔ وہ ایک گہری اور دور رس فکر بھی رکھتے تھے۔ ساتھ ہی انتہائی نرمی اور مہربانی کے جذبات بھی۔ یوں تمام روحانی اور جسمانی کمالات کے بہ یک وقت حامل تھے۔ راتوں کی عبادت کے دوران ماسوا اللہ دنیا سے ان کا رشتہ کٹ جاتا اور دن کو معاشرتی سرگرمیوں میں مصروف رہتے !
دن کو انسانی آنکھیں علی(ع) کی ہمدردیاں اورقربانیاں دیکھتیں اور انسانی کان ان (ع) کے وعظ و نصیحت اور حکیمانہ باتیں سنتے۔ رات کو چشم ستارگان ان کے ذوق بندگی میں بہنے والے آنسو دیکھتیں اور گوش فلک ان کی عشق میں ڈوبی ہوئی دعائیںاور مناجاتیں سنتا۔ وہ مفتی بھی تھے اور حکیم بھی۔ عارف بھی تھے اور اجتماعی رہبر بھی۔ زاہد بھی تھے اور سپاہی بھی۔ قاضی بھی تھے اور مزدور بھی۔ خطیب بھی تھے اور ادیب بھی۔ غرض ہر لحاظ سے تمام خوبیوں کے ساتھ ایک کامل انسان!
زیر نظر کتاب ایسی چار تقریروں کا مجموعہ ہے جو ۱۸ تا ۲۱ ماہ رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ حسینیہ ارشاد میں کی گئی تھیں۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور دو حصوں پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں عمومی طور پر جذب و دفع اور خصوصی طور پر انسانوں کے جاذبہ و دافعہ کے اصول کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ حصہ اول میں علی علیہ السلام کے اس ابدی جاذبہ جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے، کے فلسفہ، فائدہ اور اثر کو موضوع قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت(ع) کے اس طاقتور دافعہ کی کہ وہ کس قسم کے عناصر کو سختی سے رد کرتااور دور پھینکتا تھا توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ علی علیہ السلام دوہری طاقت رکھتے تھے اور جو بھی ان (ع) کے مکتب میں پروان چڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دوہری طاقت رکھتا ہو۔
چونکہ علی علیہ السلام کے مکتب کی پہچان صرف یہی نہیں ہے کہ دوہری طاقت ہو، اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ علی علیہ السلام کا جاذبہ کس قسم کے لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتا تھا اور ان کا دافعہ کس قماش کے لوگوں کو دور کرتا تھا۔ افسوس! ہم میں سے بعض جو ان (ع) کے مکتب کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جن کو علی (ع) جذب کرتے تھے انہیں دفع کرتے ہیں۔ اور جن کو وہ دفع کرتے تھے انہیں جذب کرتے ہیں۔ دافعہ علی (ع) کے باب میں خوارج کے بارے میں بحث پر اکتفاء کی گئی ہے۔ حالانکہ اور بھی گروہ ہیں جو دافعہئ علی علیہ السلام میں شامل ہےں۔ شاید کسی اور موقعہ پر اور کم از کم کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں کتاب کے دیگر نقائص کا بھی ازالہ کیا جائے.
تقریروں کی تکمیل اور اصلاح کی زحمت فاضل بلند و قدر جناب آقائے فتح اللہ امیدی نے برداشت کی ہے۔ نصف کتاب ان جناب کے قلم سے ہے جس کو ٹیپ شدہ کیسٹوں سے نقل کرکے از سرنو اپنے قلم سے تحریر کیا ہے اور کہیں اصلاح یا تکمیل کی ہے۔ دوسرا نصف دیگر میرے اپنے الفاظ ہیں یا ان جناب کی اصلاح کے بعدمیں نے خود بعض چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ امید ہے کہ مجموعی طور پر اس کا مفید اثر ہوگا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علی علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں قرار دے ۔
مرتضیٰ مطہری
تہران۔ ۱۱، اسفند ۱۳۴۹ شمسی
مطابق ۴،محرم الحرام ۱۳۹۱ قمری
مقدمہ
قانونِ جذب و دفع
''جذب و دفع'' کا قانون ایک عمومی قانون ہے جو پورے نظام آفرینش میں کار فرما ہے۔ تمام جدید انسانی علوم کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ کائنات ہستی کا کوئی ذرّہ کشش کے عمومی قانون کی عملداری سے خارج نہیں ہے بلکہ اس کا پابند ہے۔ عالم کے بڑے سے بڑے اجرام و اجسام سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ذرات تک میں کشش (جاذبہ) کی پوشیدہ قوت موجود ہے اور کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر بھی ہے۔
ذرّہ ذرّہ کاندرین ارض و سماست
جنسِ خود را ہمچو کاہ و کہرباست
اس زمین و آسمان کا ہر ذرّہ اپنی جنس کے لیے کاہ اور برق کی طرح ہے
اسے چھوڑیئے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ گو تمام جمادات کے سلسلے میں قوتِ جاذبہ کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ صرف اس بات پر بحث کرتے تھے کہ زمین کیونکر افلاک کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے۔ تاہم ان کا عقیدہ تھا کہ زمین آسمان کے وسط میں معلق ہے اور جاذبہ ہر طرف سے اس کو کھینچتا ہے اور چونکہ یہ کشش تمام اطراف سے ہے اس لیے قہراً درمیان میں کھڑی ہے اور کسی ایک طرف کو نہیں جھکتی۔ بعض کا عقیدہ تھا کہ آسمان زمین کو جذب نہیں کرتا بلکہ اس کو دفع کرتا ہے اور چونکہ زمین پریہ دباؤ تمام اطراف سے مساوی ہے نتیجتاً زمین ایک خاص نقطے پرٹھہری ہوئی ہے اور اپنی جگہ نہیں بدلتی۔
نباتات اور حیوانات میں بھی سب جاذبہ و دافعہ کی قوت کے قائل تھے بہ این معنی کہ ان کے لیے تین بنیادی قوتوں جاذبہ (طلب غذا کی قوت) نامیہ (بڑھنے کی قوت) اور مولدہ (پیدا کرنے کی قوت) کو مانتے تھے اور قوہئ غاذیہ کے لیے چند فرعی قوتوں جاذبہ،دافعہ، ہاضمہ اور ماسکہ (روکنے کی قوت) کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ معدہ کے اندر جذب کی ایک قوت ہے جو غذا کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جہاں غذا کو مناسب نہیں پاتی اس کو دفع(۱) کرتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ جگر میں جذب کی ایک قوت ہے جو پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔
معدہ نان را می کشد تا مستقر
می کشد مہ آب را تف جگر
معدہ کھانے کو اور جگر پانی کو ان کے ٹھکانوں تک کھینچ لے جاتا ہے۔
انسانی دنیا میں جاذبہ و دافعہ
جذب و دفع سے مراد یہاں جنسی جذب و دفع نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی جذب و دفع کی ایک خاص قسم ہے لیکن ہماری بحث سے مربوط نہیں ہے اور اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، بلکہ وہ جذب و دفع مراد ہے جو معاشرتی زندگی میں افراد انسانی کے درمیان موجود ہے۔ انسانی معاشرے میں مشترکہ مفاد کی بنیاد پر باہمی تعاون کی چند صورتیں ہیں، وہ بھی ہماری بحث سے خارج ہیں۔
زیادہ تر دوستی و رفاقت یادشمنی اور عداوت سب انسانی جذب و دفع کے مظاہر ہیں۔ یہ جذب و دفع مطابقت و مشابہت ی ضدیت و منافرت کی بنیاد(۲) پر ہیں۔ درحقیقت جذب و دفع کی بنیادی علت کو مطابقت اور تضاد میں تلاش کرنا چاہے۔ جیساکہ فلسفیوں کی بحث میں مسلم ہے کہالسنخیة علّة الانضمام یعنی مطابقت یکجہتی کا سبب ہے۔
____________________
(۱) آج کل انسان کی جسمانی ساخت کو ایک مشین کی مانند سمجھا جاتا ہے اور دفع کے عمل کو نکاسی کی مانند۔
(۲)اس کے برعکس جو برقی رو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دو ہمنام اجسام ( Positive ) میں داخل کی جائے تو وہ ایک دوسرے سے دفع کرتی اور ناہمنام اجسام Negetive Positive میں داخل کی جائے تو ایک دوسرے کو جذب کرتی ہے ۔
کبھی دو انسان ایک دوسرے کو جذب کرتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو دوست اور رفیق بنائیں۔ اس میں ایک راز ہے اور وہ راز مطابقت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ان دو افراد کے درمیان جب تک کوئی مشابہت نہ ہو ایک دوسرے کو جذب نہیں کرتے اور باہم دوستی کی طرف مائل نہیں ہوتے اور کلی طور پر ہر دو وجود کا ایک دوسرے کے قریب ہونا اس امری کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان کسی طرح کی مطابقت و مشابہت موجود ہے۔
مثنوی دفتر دوم میں ایک دلچسپ حکایت بیان کی گئی ہے:
کسی حکیم نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ لک لک کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا کر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور دونوں مل کر پرواز کرتے ہیں! دو مختلف نوع کے پرندے ۔ کوے اور لک لک کی شکل میں۔ کوا لک لک کے ساتھ کیونکر؟ وہ ان کے قریب گیا اور غور کیا۔ دیکھا کہ دونوں لنگڑے ہیں۔
آں حکیمی گفت دیدم ہم تکی
در بیابان زاغ را با لک لکی
در عجب ماندم بجستم حالشاں
تاچہ قدرِ مشترک یابم نشان
چون شدم نزدیک و من حیران و دنگ
خود بدیدم ہر دو آن بودند لنگ
لنگڑے پن نے دو اجنبی حیوانوں کو ایک دوسرے سے مانوس کر دیا۔ انسان بھی بلاوجہ ایک دوسرے کے دوست اور رفیق نہیں ہوتے جس طرح کہ کبھی بھی بلاوجہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔
بعض لوگوں کے نزدیک اس جذب و دفع کی اصل وجہ ضرورت اور اس کا پورا کیا جانا ہے۔ انسان ایک ضرورت مند ہستی ہے جو پیدائشی طور پر محتاج ہے۔ وہ مسلسل محنت سے اپنی محرومیوں کو دور اور ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ ایک گروہ کے ساتھ پیوستہ نہ ہو اور دوسرے گروہ سے رشتہ پیوند منقطع نہ کرے تاکہ ایک گروہ سے فائدہ اٹھائے اور دوسرے کے ضرر سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہم اس میں کوئی رجحان یا بغاوت نہیں دیکھتے مگر یہ کہ ذاتی تحفظ کے شعور نے اسے پختہ کیاہو۔ اس اعتبار سے زندگی کی مصلحتوں اور فطری ساخت نے انسان کو جاذب و دافع بنا دیا ہے کہ جہاں کوئی بہتری نظر آئے اس کے لیے تڑپے اور جہاں اپنے مقاصد کے منافی کوئی چیز دیکھے اسے اپنے سے دور کر دے اور ان کے علاوہ جو چیزیں نہ فائدے کی ہوں اور نہ نقصان دہ ہوں ان کے بارے میں کوئی احساس نہ ہو۔ درحقیقت جذب و دفع انسانی زندگی کے دو اساسی رکن ہیں۔ ان میں جتنی خامی ہوگی انسانی زندگی میں اتنا ہی خلل واقع ہوگا اور آخر میں جو خلاء کو پر کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ دوسروں کو اپنی طرف جذب کرتا ہے اور جو نہ صرف یہ کہ خلا کو پر نہیں کرتا بلکہ خلا میں مزید اضافہ کرتا ہے، وہ انسانو ںکو اپنے سے دور کر دیتا ہے اور جو ان دونوں میں نہ ہو وہ اس پتھر کی طرح ہے جو کنارے پر پڑا ہے۔
جذب و دفع کے سلسلے میں لوگو ں کے درمیان فرق
جاذبہ و دافعہ کے اعتبار سے لوگ یکساں نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف طبقات میں تقسیم کئے جا سکتے ہیں:
۱۔ وہ لوگ جو نہ جاذبہ رکھتے ہیں نہ دافعہ۔ نہ کوئی ان سے دوستی رکھتا ہے اور نہ ہی دشمنی ۔ نہ عشق و تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں نہ عداوت و حسد اور کینہ و نفرت۔ وہ بے پرواہ ہو کر لوگوں کے درمیان چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہے جو لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔
یہ ایک مہمل اور بے اثر وجود ہے۔ وہ انسان جو فضیلت یا رذالت کے اعتبار سے کوئی مثبت نقطہ نہ رکھتا ہو (مثبت سے مراد یہاں صرف فضیلت کا پہلو نہیں ہے بلکہ شقاوت بھی مرادہے) وہ ایک ایسا جانور ہے جو غذا کھاتا، سوتا اور انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ یہ اس گوسفند کی طرح ہے جو نہ کسی کا دوست ہے اور نہ کسی کا دشمن اور اگر لوگ اس کی خبر لیتے ہیں اور اسے پانی اور چارہ دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ کسی وقت اس کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ نہ دوستانہ جذبات پیدا کر سکتا ہے نہ مخالفانہ۔ یہ ایک گروہ ہے جو بے قیمت اور بیہودہ و محروم لوگوں کا ہے۔ کیونکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوست رکھتا ہو اور لوگ اس کو دوست رکھتے ہوں۔ بلکہ ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمن رکھتا ہو اور لوگ اسے دشمن رکھتے ہوں۔
۲۔وہ لوگ جو جاذبہ تو رکھتے ہیں لیکن دافعہ نہیں رکھتے بلکہ ہر ایک کے لیے گرم جوشی رکھتے ہیں اور تمام طبقات کے تمام لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ انہیں دوست رکھتے ہیں اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ جب مرتے ہیں تب بھی مسلمان ان کو آب زمزم سے غسل دیتے ہیں اور ہندو ان کے جسم کو جلاتے ہیں۔
چنان بانیک و بد خو کن کہ بعد از مردنت عرفی
مسلمانت بہ زمزم شوید و ہندو بسوزاند
عرفی! نیک و بد سب کے ساتھ اس طرح زندگی گزار کہ تیرے مرنے کے بعد مسلمان تجھے زمزم سے غسل دیں اور ہندو جلا دیں.
اس شاعر کے اصول کے مطابق ایسے معاشرے میں جہاں آدھے لوگ مسلمان ہیں اور جنازے کااحترام کرتے ہیں اور اسے غسل دیتے ہیں اور کبھی زیادہ احترام کرتے ہوئے مقدس آب زمزم سے غسل دیتے ہیں، اور آدھے ہندو ہیں جو مردے کو جلاتے ہیں اور اس کی رکھ اڑا دیتے ہیں،اس طرح زندگی گزار کہ مسلمان تجھے اپنا سمجھیں اور مرنے کے بعد تجھے آب زمزم سے غسل دینا چاہیں اور ہندو بھی تجھے اپنا جانیں اور مرنے کے بعد تجھے جلا دینا چاہیں۔
غالباً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حسن خلق، بہترین میل جول اور جدید اصطلاح میں سوشل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان سب کو دوست بنائے لیکن ایسا کرنا ایک ہدف اور مسلک رکھنے والے انسان کے لیے جو ذاتی مفاد کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ معاشرے میں ایک فکر اور نظریے کے لیے کام کرتا ہے، آسان نہیں ہے۔ ایسا انسان چار و ناچار یک رو، صاف گو اور کٹر ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ منافق اور دوغلا ہو۔ چونکہ تمام لوگ ایک طرح نہیں سوچتے، ایک طرح کا احساس نہیں رکھتے اور سب کی پسند ایک جیسی نہیں ہوتی لوگوں میں انصاف کرنے والے بھی ہیں اور ستم کرنے والے بھی۔ اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔
معاشرے میں انصاف پسند، ظلم کرنے والے، عادل اور فاسق سب لوگ ہیں۔ وہ سب کسی ایسے انسان کو دوست نہیں رکھ سکتے جو ایک ہدف کے لیے صحیح معنوں میں کام کرتا ہو اور خواہ مخواہ ان میں سے بعض کے مفاد سے متصادم ہو۔ مختلف طبقات اور مختلف نظریات کے لوگوں کو اپنی طرف جلب کرنے میں صرف وہی شخص کامیاب ہوسکتا ہے جو ریا کار اور جھوٹا ہو اور ہر کسی سے اس کی پسند کے مطابق بات کرے اور ریا سے کام لے۔ لیکن اگر انسان یک رو اور پختہ عقیدہ رکھتا ہو تو قہری طور پرکچھ لوگ اس کے دوست ہوں گے اور کچھ لوگ اس کے دسمن بھی۔ وہ لوگ جن کی راہ اس سے ملتی ہے اس کی طرف کھچے چلے آئیں گے اور جو لوگ اس کی راہ کے مخالف جا رہے ہیں وہ اسے اپنے سے دور پھینکیں گے اور اس کی مخالفت کریں گے۔
بعض مسیحی جو اپنے آپ اور اپنے وطیرے کو محبت کا پیامی سمجھتے ہیںان کا دعویٰ ہے کہ انسان کامل فقط محبت رکھتا ہے اور بس۔ یوں صرف جاذبہ رکھتا ہے اور شاید بعض ہندو بھی اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔
مسیحی اور ہندی فلسفوں میں زیادہ نمایاں تعلیم محبت ہی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے تعلق رکھنا چاہیے اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور جب ہم سب کو دوست رکھتے ہیں تو اس میں کوئی چیز مانع نہیں ہوسکتی کہ وہ بھی ہمیں دوست رکھیں۔ برے بھی ہم کو دوست رکھیں گے کیونکہ انہوں نے ہم سے صرف محبت ہی دیکھی ہے۔
لیکن ان حضرات کو جان لیناچاہیے کہ صرف اہل محبت ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اہل مسلک (عقیدہ) ہونا بھی ضروری ہے اور کتاب بنام ''یہ ہے میرا مذہب'' میں گاندھی کے بقول محبت کو حقیقت کاجڑواں ہونا چاہےے اور حقیقت کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلک بھی ہے اور مسلک خواہ مخواہ دشمن پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بعض کے ساتھ مقابلہ کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور بعض کو رد کردیتا ہے۔
اسلام بھی قانون محبت ہے۔ قرآن رسول اکرم(ص) کی پہچان رحمۃ للعالمین کی حیثیت سے کراتا ہے۔
( وَ مَآ اَرْسَلْنٰاکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ) ۔(۱)
ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔
یعنی اپنے سخت ترین دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنو اور ان سے بھی محبت کرو۔(۲) لیکن قرآن جس محبت کا حکم دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر شخص کی پسند
____________________
(۱) ۲۱ سورہئ انبیاء آیت نمبر ۱۰۷
(۲)بلکہ آپ (ص) ہر چیز سے محبت کرتے تھے یہاں تک کہ حیوانات اور جمادات کے ساتھ بھی ۔اسی لیے ہم آپ (ص)کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ (ص) کے تمام ہتھیاروں اور روزمرہ زندگی میں استعمال کی چیزوں کے خاص نام تھے۔ آپ (ص) کے گھوڑوں، تلواروں اور عماموں کے خاص نام تھے۔ ایسا صرف اس لیے تھا کہ تمام موجودات سے آپ (ص) کو محبت تھی۔ گویا آپ (ص) ہر چیز کے تشخص کے قائل تھے۔ ان کے علاوہ تاریخ میں اس طرح کا رویہ کسی اور انسان کے بارے میں نہیں ملتا۔ یہ روش بتاتی ہے کہ در حقیقت آپ (ص) انسانی عشق و محبت کی مثال تھے۔ جب کہ آپ (ص) احد کے دامن سے گزرتے تو چمکتی آنکھوں اور محبت سے لبریز نگاہوں سے احد کو مخاطب کرکے کہتے:جَبَلٌ یُحِبُّنَا وَ نحبه ۔ یعنی یہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ (ص) ایسے انسان تھے کہ پہاڑ اور پتھر بھی آپ (ص) کی محبت سے بہرہ مند تھے۔
اور خواہش کے مطابق عمل کریں اور اس کے ساتھ اس طرح کا چلن اختیار کریں کہ وہ ہم سے خوش ہو اور نتیجتاً وہ ہماری طرف کشاں کشاں چلا آئے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو اس کی خواہشات میں آزاد چھوڑ دیں یاان خواہشات کی تائید کریں۔ محبت وہ ہے جو حقیقت سے مربوط ہو۔ محبت خیر خواہی ہے اور خیر خواہی کرتے ہوئے غالباً ایسی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے فریق کی محبت جلب نہ کی جاسکے۔ اس راہ میں بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جن سے تعلق خاطر رکھتا ہے وہ چونکہ اس محبت کو اپنی خواہشات کے خلاف پاتے ہیں، وہ قدر دانی کی بجائے دشمنی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منطقی اور معقول محبت وہ ہے جس میں انسانی معاشرے کی بہتری اور مصلحت ہو، نہ کہ ایک خاص فرد یا گروہ کی۔ بسااوقات افراد کے ساتھ خیرخواہی اورمحبت کرنا معاشرے کے ساتھ سراسر بدخواہی اور دشمنی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔
بڑے بڑے مصلحین کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے تھے اور اپنے لیے تکلیفوں کا راستہ ہموار کرتے تھے لیکن لوگوں کی طرف سے دشمنی اور تکلیف کے علاوہ کوئی صلہ نہیں پاتے تھے۔ پس ایسا ہرگز نہی ہے کہ محبت ہر جگہ جاذبہ رکھتی ہو بلکہ کبھی کبھار محبت اس قدر شدید دافعہ کا جلوہ بھی دکھاتی ہے کہ انسان کی مخالفت میں جماعتیں تشکیل کی جاتی ہیں۔
عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، علی علیہ السلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ علی (ع) خوب جانتے تھے کہ یہ شخص ان کا ایک خطرناک دشمن ہے۔ دوسرے لوگ بھی کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس کی بیخ کنی کیجئے۔ مگر علی علیہ السلام کہتے: کیا ہے میں جرم سے پہلے قصاص لوں؟ اگر وہ میرا قاتل ہے تو میں اپنے قاتل کو نہیں مارسکتا۔ وہ میرا قاتل ہے، نہ کہ میں اس کاقاتل اور اسی کے بارے میں علی علیہ السلام نے کہا: ارید حیاتہ و یرید قتلی(۱) یعنی میں چاہتا ہوں وہ زندہ رہے اور اس کی سعادت چاہتا ہوں اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے۔ میں اس سے محبت و تعلق رکھتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ دشمنی اور کینہ رکھتا ہے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ محبت ہی تنہا انسانی امراض کاعلاج نہیں ہے بلکہ بعض طبقوں اورمزاجوں کے لیے سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور مقابلہ، دفع اور رد کر دینا لازم ہوجاتا ہے۔ اسلام جذب و محبت کا دین ہے۔ ساتھ ہی دفع اور غضب(۲) کا دین بھی۔
____________________
(۱) بحار الانوار جدید ایڈیشن۔ ج ۴۲، ص ۱۹۳ ۔ ۱۹۶
(۲) ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ نفرت بھی لطف و محبت کا ایک پہلو ہے۔ ہم دعا میں پڑھتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبہ۔ اے وہ ذات جس کی رحمت نے اس کے غضب سے پہل کی اور چونکہ رحمت کرنا چاہتا تھا اس لیے غضب نازل کیا اور تو ناراض ہوا اور اگر محبت اور رحمت نہ ہوتی تو غضب بھی نہ ہوتا۔
جس طرح ایک با پ اپنے بیٹے پر اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہے اور اس کے مستقبل کی فکر ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرے تو ناخوش ہوجاتا ہے اور کبھی اسے مارتا بھی ہے۔ حالانکہ دوسروں کی اس سے زیادہ نامعقول روش دیکھتا ہے لیکن وہ محسوس نہیں کرتا۔ مگر چونکہ اپنے بچے سے تعلق خاطر رکھتا تھا اس لیے ناراض ہوا اور دوسروں کے بچوں سے کوئی تعلق نہ تھا اس لیے ناراض بھی نہیں ہوا۔
اور دوسری طرف تعلق خاطر کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ یعنی محض ایک جذبہ ہے جو حکم عقل کے تابع نہیں ہے جیسا کہ قرآن کہتا ہے:( وَ لَا تَاْخُذْکُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ ) (۲۴نور : ۲)یعنی قانون الہی کے اجراء میں تمہاری محبت و نرمی مجرم کو ڈھیل نہ دے۔ کیونکہ اسلام جس طرح افراد کے ساتھ تعلق خاطررکھتا ہے اسی طرح معاشرے کے ساتھ بھی تعلق خاطر رکھتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو انسان کی نظر میں چھوٹا ہو اور وہ اسے حقیر سمجھے امیر المومنینؑ فرماتے ہیں: اشدّ الذنوب ما استھان صاحبہ۔(نہج البلاغہ حکمت : ۲۴۰) ''سب سے شدید گناہ وہ ہے جسے گناہگار آسان اور ناچیز سمجھے'' گناہ کی اشاعت ہی وہ چیز ہے جس سے گناہ کی شدت نظروں سے کم ہو جاتی ہے اور فرد کی نظر میں اسے حقیر ظاہر کرتی ہے۔اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ گناہ مکمل طور پر پردے میں نہ ہو اور لوگ اس سے باخبر ہوجائیں تو گناہ گار کو ہر صورت میں مورد سیاست قرار پانا چاہےے یا حد کی سزا کھائے یا تعزیر کی۔ اسلامی فقہ میں کلی طور پر کہا گیا ہے کہ ہر واجب کے ترک اور ہر حرام کی بجاآوری پر اگر حد کا تعین نہ کیا گیا ہو تو اس کے لیے تعزیر ہے۔ ''تعزیر'' ''حد'' سے کمتر سزا ہے جس کا حاکم (شرع) اپنی صوابدید کے مطابق تعین کرتا ہے۔ ایک فرد کے گناہ اور اس کی اشاعت پر معاشرہ ایک قدم گناہ کے نزدیک ہوا اور یہ اس (معاشرہ) کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ پس گناہگار کو اس کے گناہ کی اہمیت کے مناسب سزا دی جانی چاہیے تاکہ معاشرہ اپنی راہ پر واپس آجائے اور گناہ کی شدت نظروں سے کم نہ ہو۔
اس بناء پر سزا اور عذاب ایک ایسی ححبت ہے جو معاشرے کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔
۳۔وہ لوگ جو دافعہ رکھتے ہیں لیکن جاذبہ نہیں رکھتے۔جو صرف دشمن بناتے ہیں لیکن دوست نہیں بناتے۔ یہ بھی ناقص لوگ ہیںاوریہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں مثبت انسانی خصلتیں مفقود ہیں۔ کیونکہ اگر وہ انسانی خصائل کے حامل ہوتے تو ہر چند تھوڑی تعداد میں ہی سہی، ایک گروہ ایسا ضرور رکھتے جو ان کا طرفدار اور ان سے تعلق خاطر رکھنے والا ہو۔ کیونکہ لوگوں کے درمیان اچھے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہو، لیکن کبھی سب لوگ برے نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ کسی زمانے میں بھی سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ اس لیے لازمی طورپر کسی سے اگر سب کو دشمنی ہو توخرابی اس کی اپنی ہے۔ ورنہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک انسان کی روح میں خوبیاں ہوں اور وہ کوئی دوست نہ رکھتا ہو۔ اس قسم کے لوگ اپنے وجود میں کوئی مثبت پہلو نہیں رکھتے حتیٰ کہ شقاوت کا پہلو بھی۔ ان کا وجود سراسر تلخ ہے اور سب کے لیے تلخ ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کم از کم بعض کے لیے شیریں ہو۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:
اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، اعجز منه من ضیّع من ظفر به منهم ۔(۱)
لوگوں میں درماندہ وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھائی اپنے لیے حاصل نہ کر سکے اور اس سے بھی زیادہ درماندہ وہ ہے جو پا کر اسے کھو دے۔
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت : ۱۱
۴۔لوگ جو جاذبہ بھی رکھتے ہیں اور دافعہ بھی ۔ وہ باصول لوگ جو اپنے مسلک اور عقیدے کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، چند گروہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، دلوں میں محبوب اور مقصود کی حیثیت سے گھر کر جاتے ہیں اور چند گروہوں کو اپنے سے دفع اور رد بھی کرتے ہیں۔ دوست بھی بناتے ہیں اور دشمن بھی۔ موافق پرور بھی ہیں اور مخالف پرور بھی۔
ان کی بھی چند قسمیں ہیں کیونکہ کبھی جاذبہ و دافعہ دونوں قومی ہیں، کبھی دونوں ضعیف اور کبھی ایک قوی اور دوسرا ضعیف۔ باوقار لوگ وہ ہیں جو جاذبہ و دافعہ ہر دو قوی رکھتے ہوں اور اس کاتعلق اس بات سے ہے کہ ان کی روح میں مثبت یا منفی (اقدار) کی بنیادیں کس قدر مضبوط ہیں۔ البتہ قوت کے بھی مراتب ہیں، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ مجذوب دوست اپنی جان فدا کردیتے ہیں اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور دشمن بھی اس قدر سخت ہو جاتے ہیں کہ اس راہ (دشمنی) میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں اور یہ (صورت حال) اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی صدیوں تک ان کے جذب و دفع (کی شدت) انسانی روحوں میں کار فرما ہوتی ہے اور ایک وسیع حلقے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور یہ سہ پہلو جذب و دفع صرف اولیاء کے لیے مختص ہے، جس طرح کہ سہ پہلو دعوت (مشن) پیغمبروں کے لیے مختص ہے۔(۱)
____________________
(۱) مقدمہ جلد اول خاتم پیامبران، ص ۱۱ و ۱۲
دوسری جانب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن عناصر کو جذب اور کن عناصر کو دفع کرتے ہیں۔ مثلاً کبھی ایسا ہتا ہے کہ دانا عنصر کو جذب اور نادان عنصر کو دفع کرتے ہیں اور کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ کبھی شریف اور نجیب عناصر کو جذب اور پلید اور خبیث عناصر کو دفع کرتے ہیں اور کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لہذا دوست اور دشمن، جذب ہونے والے اور دور پھینکے جانے والے اس (جذب و دفع کرنے والے) کی ماہیت پر قطعی دلیلیں ہیں۔
کسی کی شخصیت کے قابل ستائش ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ جاذبہ و دافعہ رکھتی ہے یا یہ کہ قوی جاذبہ و دافعہ رکھتی ہے،بلکہ یہ تو اصل شخصیت کی دلیل ہے اور کسی کی محض شخصیت کسی کی خوبی کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کے تمام رہنما اور لیڈر حتیٰ کہ چنگیز خان، حجاج اور معاویہ جیسے جرائم پیشہ لوگ بھی جاذبہ اور دافعہ دونوں رکھتے تھے اور جب تک کسی کی روح میں مثبت نقطے موجود نہ ہوں، ممکن نہیں ہے کہ ہزاروں سپاہیوں کو وہ اپنامطیع اور اپنے ارادے کا تابع بنا لے۔ جب تک رہنمائی کی طاقت نہ رکھتا ہو، آدمی اتنے لوگوں کو اپنے گرد جمع نہیں کر سکتا۔
نادر شاہ ایسے ہی افراد میں سے ایک ہے۔ اس نے کتنے سرقلم کئے اور کتنی ہی آنکھیں حلقوں سے باہر نکال دیں لیکن اس کی شخصیت غیر معمولی طاقت کی حامل ہے۔ اس نے صفوی عہد کے آخری دنوں میں شکست خوردہ اور لٹے پٹے ایران سے ایک بھاری لشکر تیار کیا اور میدان جنگ کو اس طرح اپنے گرد اکٹھا کیا جس طرح مقناطیس فولادکے ذرّوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور یوں ایران کو نہ صرف غیروں کے تسلط سے نجات دلائی بلکہ ہندوستان کے آخری حصوں کو بھی فتح کرلیا اور نئی سرحدوں کو ایرانی سلطنت میں شامل کیا۔
بنابریں ہر شخصیت اپنے قبیل کے لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتی ہے اور اس کے مخالف لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ انصاف پرور اور شریف شخصیت نیکی پسند اور عدالت کے طلبگار عناصر کو اپنی طرف جذب کرتی ہے اور ہوس پرستوں، زرپرستوں اور منافقوں کو اپنے سے دور پھینکتی ہے۔ جرائم پیشہ شخصیت مجرموں کو اپنے گرد جمع کرتی ہے اور نیک لوگوں کو اپنے سے دور پھینکتی ہے۔
اور جس طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، ایک دوسرا فرق قوت کشش (جذب) کی مقدار کا ہے۔ جس طرح کہ نیوٹن کے ''نظریہ کشش '' کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی شئے کی جسامت اور کمتر فاصلے کی نسبت سے کشش اور جذب کی مقدار زیادہ ہوجاتی ہے۔ انسانوں میں جذب کرنے والی شخصیت کے اعتبار سے جذب اور دباؤ (دفع) کی مقدار میں فرق پیدا ہوتا ہے۔
علی علیہ السّلام۔ دوہری قوت والی شخصیت
علی(ع) ان لوگوں میں سے ہیں جو جاذبہ بھی رکھتے ہیں اور دافعہ بھی اور ان کا جاذبہ و دافعہ سخت قوی ہیں۔ شاید تمام صدیوں اور زمانوں میں علی (ع) کے جاذبہ و دافعہ کی طرح کا قوی جاذبہ و دافعہ ہم پیدا نہ کر سکیں۔ وہ ایسے عجیب تاریخی، فداکار اور درگزر کرنے والے دوست رکھتے ہیں جو ان کے عشق میںآتش خرمن کے شعلوں کی طرح بھڑکتے اور دمکتے ہیں۔ وہ اس کی راہ میں جان دینے کواپنی آرزو اور اپنا سرمایہئ افتخار سجھتے ہیں اور جنہوں نے ان کی محبت میں ہر شئے کو بھلا دیا ہے۔ علی(ع) کی موت کو سالہا سال بلکہ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن یہ جاذبہ و افعہ اسی طرح اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔
ان کی زندگی میں ایسے شریف و نجیب، خدا پرست، فداکار، بے لوث عناصر اور عفو و درگزر کرنے والے مہربان، عادل اور خدمت خلق کرنے والے لوگ ان کی ذات کے محور پر اس طرح گھومتے تھے کہ ان میں سے ہرایک، ایک سبق آموز تاریخ رکھتا ہے اور ان کی موت کے بعد معاویہ و دیگر اموی خلفاء کے دور میں بے شمار لوگ ان کی دوستی کی پاداش میں سخت ترین شکنجوں میں کسے گئے، لیکن علی (ع) کی دوستی اور عشق میں ان کے قدم نہ لڑکھڑائے اور آخری سانس تک وہ ثابت قدم رہے۔
دنیاوی شخصیتیں جب مرتی ہیں تو ان کے ساتھ ساری چیزیں مرجاتی ہیں اور ان کے جسم کے ساتھ زمین کے اندر پنہاں ہوجاتی ہیں۔ جبکہ حق والی شخصیتیں خود مر جاتی ہیںلیکن ان کا مکتب اور ان کے ساتھ لوگوں کا عشق صدیاںگزرنے کے باوجود تابندہ تر ہوجاتا ہے۔
ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ علی (ع) کی موت کے سالہا سال بلکہ صدیوں بعد بھی لوگ دل و جان سے ان کے دشمنوں کے تیروں کو سینے سے لگاتے ہیں۔
علی علیہ السّلام کے مجذوبین اور عاشقوں میں سے ایک میثم تمار کوہم دیکھتے ہیں کہ مولیٰ (ع)ٰؑ کی شہادت کے بیس برس بعد بھی سولی پر علی (ع) کے فضائل اور بلند انسانی اوصاف بیان کرتے ہیں۔ ان دنوں جبکہ تمام اسلامی دنیا گھٹن کا شکار ہے،تمام آزادیاں سلب ہیں، سانسیں سینوں میں بند ہیں، موت کا ساسکوت اس طرح طاری ہے جیسے چہروں پر موت کا غبار چھایا ہوا ہو، وہ تختہئ دار پر سے فریاد کرتا ہے کہ آجاؤ میں تمہیں علی (ع) کے بارے میں بتادوں! لوگ میثم کی باتیں سننے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔
بنی امیہ اپنی آہنی حکومت اوراپنے مفاد کو خطرہ میں دیکھ کر حکم دیتی ہے کہ میثم کا منہ بند کر دیا جائے اور اس طرح انہوں نے چند روز میں میثم کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔ تاریخ علی (ع) کے بہت سے ایسے عاشقوں کا پتہ دیتی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ یہ جذبے باقی زمانوں کو چھوڑ کر صرف کسی ایک عصر سے مختص ہوںٍ۔ ایسے طاقتور جذبوں کے جلوے ہم ہر دور میں دیکھتے ہیں کہ سخت مؤثر رہے ہیں۔
ابن سکیّت عربی ادب کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں اور آج بھی عربی ادب کے ماہرین ان کو سیبویہ جیسے لوگوں کا ہم رتبہ سجھتے ہیںٍ۔ یہ عباسی خلیفہ متوکل کے دور کاآدمی ہے۔ یعنی علی علیہ السّلام کی شہادت کے تقریباً دو سو سال بعد کا۔ متوکل کے دربار میں اس پر شیعہ ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا۔ مگر چونکہ بہت ممتاز عالم تھا اس لیے متوکّل نے اسے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے منتخب کیا۔ ایک دن جب متوکل کے بچے اس کے دربار میں آئے تو ابن سکیّت بھی ساتھ تھا۔ اس سے پہلے اسی دن ان کا امتحان بھی ہوا تھا جس میں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ متوکل نے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یاپہلے سے اس کے ذہن میں جوبات ڈالی گئی تھی کہ اس کا میلان شیعیت کی طرف ہے، اس کی تصدیق کے لیے،ابن سکیّتسے پوچھا کہ یہ دوبچے تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں یا علی کے فرزند حسن اور حسین علیہم السلام؟
اس جملے اور اس موازنہ سے ابن سکیت سخت برہم ہوا۔ اس کا خون کھولنے لگا اور اپنے آپ سے کہا کہ مغرور شحص کے کرتوت یہاں تک پہنچ گئے کہ اپنے بچوں کا حسن اور حسین علیہما السلام کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ یہ میرا قصور ہے کہ ان کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کر رکھی ہے، اس نے متوکل کو جواب دیتے ہوئے کہا:
خدا کی قسم علی(ع) کا غلام قنبر میرے نزدیک ان دونوں بچوں اور ان کے باپ سے زیادہ محبوب ہے۔
متوکل نے اسی جگہ حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان پشت گردن سے کھینچ لی جائے۔
تاریخ بہت سے ایسے دیوانوں کو جانتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو بے اختیار علی(ع) کی محبت کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ جاذبہ اور کہاں ملے گا؟ سوچا نہیں جا سکتا کہ دنیا میں اس کی کوئی اور نظیر ہو۔
علی (ع) کے دشمن بھی اتنے ہی شدید ہیں۔ ایسے دشمن جو ان کے نام سے پیچ و تاب کھاتے ہیں۔ علی (ع) ایک فرد کی شکل میں اب دنیا میں نہیں، لیکن ایک مکتب کی صورت میں موجود ہیں اور اسی وجہ سے ایک گروہ کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں اور ایک گروہ کواپنے سے دور پھینکتے ہیں۔
جی ہاں! علی (ع) کی شخصیت میں دوہری طاقت ہے۔
جاذبہئ علی علیہ السلام کی قوت
طاقت ور جاذبے
خاتم پیمبران (ص) کی پہلی جلد کے مقدمہ میں تعلیمات کے بارے میں ہم یوں پڑھتے ہیں:
انسانیت کے درمیان ظاہرہونے والی تعلیمات ساری یکساں نہ تھیں اور یہ کہ ان کی تاثیر کا دائرہ بھی ایک جیسا نہیں تھا۔
بعض تعلیمات اور فکری نظاموں کا صرف ایک ہی پہلو ہے اور انکی پیشرفت ایک ہی جانب ہے۔ اپنے زمانے میں ایک وسیع سطح کو اپنی لپیت میں لیا، لاکھوں کی تعداد میں پیروکاروں کی جماعت پیدا کی، لیکن ان کا زمانہ ختم ہونے کے بعد ان کی بساط ہستی لپیٹ دی گئی اور وہ طاقِ نسیان میں ڈال دی گئیں۔
بعض تعلیمات اور فکری نظاموںکے دو پہلوہیں، ان کی روشنی دو سمتوںمیں آگے بڑھی جس نے ایک وسیع سطح کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اسی طرح بعد کے زمانوں میںبھی پیش رفت کی یعنی صرف ''مکان '' کا ہی پہلو نہ تھا بلکہ ''زمان '' پربھی وہ حاوی تھیں۔
اور بعض (تعلیمات اور فکری نظاموں) نے مختلف پہلوؤں سے پیش رفت کی ہے۔ وسیع سطح پر انسانی گروہوں کو لپیٹ میں لے کر اپنے زیر اثر کیا ہے۔ چنانچہ ہم دنیا کے ہر براعظم میں ان کا اثر و نفوذ دیکھتے ہیں اور '' زمان،، کا پہلو بھی۔ یعنی ایک عصر یا ایک زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ صدیوں تک پورے اقتدار کے ساتھ ان کی حکمرانی رہی ہے۔ ان کی جڑیں انسانی روح کی گہرائیوں میں ہیں۔
انسانی ضمیر کے رازوں پر ان کا قبضہ ہے۔ قلب کی گہرائیوں پران کی حکمرانی ہے اور احساس کی نبض پران کا ہاتھ ہے۔ یہ سہ پہلو تعلیمات سلسلہئ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں۔
ایسا کون سا فکری یا فلسفی مکتب پیدا کیا جا سکتا ہے جس نے دنیا کے بڑے ادیان کی مانند، کروڑوں انسانوں پر تیس، بیس، یا کم از کم چودہ صدیاں حکومت کی ہو اور انسانی ضمیر کو جھنجھورا ہو؟؟!
جاذبے بھی اسی طرح ہیں۔ یعنی کبھی یک پہلو۔ کبھی دو پہلو اور کبھی سہ پہلو۔
علی (ع) کا جاذبہ آخری قسم (سہ پہلو) سے ہے۔ انسانی جمعیت کی ایک وسیع سطح کو اپنا دیوانہ بھی بنایا اور یہ بھی کہ ایسا صرف ایک یا دو صدیوں کے لیے نہیں، وہ وقت کے ساتھ باقی رہا بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو صدیوں اور عصروں سے درخشاں ہے اوراس طرح دل کی گہرائیوں اورباطن کو پنہائی میں پیوستہ ہے کہ صدیوں بعد بھی جب ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی بلندیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو اشک شوق بہاتے ہیں اور ان کے مصائب پر گریہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ دشمن بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور آنسو بہانے لگتے ہیں۔ یہ انتہائی طاقتور جاذبہ ہے۔
یہاں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ دین کے ساتھ انسان کا رشہ کمروز مادی رشتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ انسانی روح کے ساتھ اس طرح کا کوئی دوسرا رشتہ نہیں۔ علی(ع) اگر خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے اور مرد خدا نہ ہوتے تو فراموش ہوچکے ہوتے۔ انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے سپتوں کا سراغ ملتا ہے۔ میدان خطابت کے سپوت، مردان علم و فلسفہ، قدرت و سلطنت کے داتا، میدان جنگ کے ہیرو، لیکن یاان کو انسان نے بھلا دیا ہے یا سرے سے پہچانا ہی نہیں۔ مگر علی (ع) نہ صرف یہ کہ قتل ہونے کے باوجود نہیں مرے بلکہ آپ (ع) زندہ تر ہوگئے۔ خود فرماتے ہیں :
هلک خزان الاموال و هم احیاءٌ و العملاء باقون ما بقی الدهر اعیانهم مفقودة و امثالهم فی القلوب موجودة ۔(۱)
مال جمع کرنے والے زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں اور علماء باقی ہیں جب تک زمانہ باقی ہے۔ ان کے جسم نظروں سے اوجھل ہیں لیکن ان کے آثار دلوں میں موجود ہیں۔
____________________
(۱)نہج البلاغہ حکمت: ۱
اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں:
غدا ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری، و تعرفو ننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی ۔(۱)
کل تم میرے ایام دیکھو گے اور میری وہ خصوصیات تمہارے اوپر آشکار ہو جائیں گی جنہیں (آج) نہیں پہچانا گیا اور میری جگہ کے خالی ہونے اور میری جگہ پر میرے غیر کے بیٹھنے کے بعد تم مجھے پہچانو گے۔
____________________
(۱) نہج البلاغہ خطبہ: ۱۴۹
عصرِ من ، دانندہئ اسرار نیست
میرا زمانہ اسرار کو جاننے والا نہیں
یوسف من بہر این بازار نیست
میرا یوسف اس بازار کے لیے نہیں ہے
نامید استم ز یا ران قدیم
میں اپنے پرانے دوستوں سے مایوس ہوں
طور من سوزدکہ می آید کلیم
میرا طور کلیم کے انتظار میں جل رہا ہے
قلزم یاران چوشبنم بی خروش
دوستوں کاسمندرشبنم کی طرح خاموش ہے
شبنم من مثل یمّ طوفان بہ دوش
میری شبنم موجوں کی طرح طوفانی ہے
نغمہئ من ازجہان دیگر است
میرا نغمہ کسی اور ہی سے دنیا ہے
این جرس راکاروان دیگر است
یہ صدائے جرس کسی اور ہی کارواں کی ہے
ای بسا شاعر کہ بعد از مرگ زاد
بہت سے شاعر مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں
چشم خود بربست و چشم ماگشاد
وہ اپنی آنکھوں بند کر کے ہماری آنکھیں کھولتے ہیں
رخت ناز از نیستی بیرون کشید
ان کا حسن نیستی سے نکھرتا ہے
چون گل از خاک مزار خود دمید
اپنے مزار کی خاک سے پھولوں کی طرح کھلتے ہیں
درنمی گنجد بہ جو عمان من
میرا عمان ندی میں نہیں سماتا
بحرہا باید پی طوفان من
میرے طوفان کو سمندروں کی ضرورت ہے
برقہا خوابیدہ درجان من است
میرے دل میں بجلیاں سو رہی ہیں
کوہ و صحرا باب جولان من است
پہاڑاور بیابان میری دوڑ کےلئے دروازے ہیں
چشمہئِ حیوان کردہ اند
انہوں نے مجھے آب حیات بخشا ہے
محرم راز حیاتم کردہ اند
انہوں نے مجھے زندگی کا راز سمجھا دیا ہے
ہیچ کس رازی کہ من گفتم نہ گفت
جوراز میں نے بتایا وہ کسی نے نہ بتایا
ہم چو فکر من در معنی نہ سفت
میری فکر کی طرح کسی نے معنی کے موتی نہ پروئے
پیرگردون با من این اسرار گفت
بوڑھے آسمان نے مجھے یہ راز سمجھائے
از ندیمان راز ہا نتوان نہفت(۱)
دوستوںسے کوئی چیزپوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی
درحقیقت علی علیہ السّلام قوانین فطرت کی طرح ہیں جو جاودانی ہیں۔ وہ فیض کا ایسا سرچشمہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے اور بقول جبران خلیل جبران '' وہ ان شخصیتوں میں سے ہیں جو اپنے وقت سے پہلے ہی دنیا میں آگئیں۔''
بعض لوگ صرف اپنے زمانے کے رہنما ہیں۔ بعض اپنے بعد بھی تھوڑے سے عرصے کے لیے رہنما ہیں اور رفتہ رفتہ ان کی رہنمائی یاد سے محو ہوجاتی ہے۔ لیکن علی علیہ السّلام اور گنے چنے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہادی اور رہنما ہیں۔
____________________
(۱)کلیات اشعار فارسی علامہ اقبال ص ۶۔ ۷
تشیّع ۔ مکتب عشق و محبت
تمام مذاہب میں مذہب شیعہ کوجو سب سے بڑا امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اساس اور بنیاد محبت پر ہے۔ خود نبی اکرم(ص) کے زمانے سے، جب سے اس مذہب کی بنیاد پڑی ہے، یہ محبت اور دوستی کا سرچشمہ رہا ہے ۔جہاں ہم رسول اکرم (ص) کی زبان سےعلی و شیعته هم الفائزون (۱) '' علی (ع) اور ان کے شیعہ کامیاب ہیں '' سنتے ہیں وہاں ایک ایسے گروہ کو ان کا گروہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا عاشق، ان کے ساتھ گرم جوشی رکھنے والا اور ان کا دیوانہ ہے۔ اس لحاظ سے تشیع عشق و شیفتگی کا مذہب ہے، ان حضرت (ع) کے ساتھ تو لا، عشق و محبت کا مکتب ہے۔ محبت کے عنصر کو تشیع میں مکمل دخل ہے۔ تشیع کی تاریخ عاشقوں، شیدائیوں، جانبازوں اور دیوانوں کے ایک سلسلے کا دوسرا نام ہے۔
____________________
(۱)جلال الدین سیوطی درمنشور میں سورہئ مبینہ کی آیت ۷ کے ذیل میں ابن عساکر سے اور وہ جابر عبد اللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ہم پیغمبر (ص)کے دربار میں حاضر تھے کہ علی(ع) بھی حضور (ص) کی خدمت میں پہنچے ۔ حضور (ص) نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ ان ھذا و شیعتہ ھم الفائزون یوم القیٰمۃ یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضہئ قدرت میں میری جان ہے یہ شخص اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے ۔ مناوی کنوز الحقائق میں اسے دو روایتوں سے نقل کرتے ہیں اور ہیثمی مجمع الزوائد میں اور ابن حجر صواعق محرقہ میں اسی مضمون کو دوسرے طریقے سے نقل کرتے ہیں۔
علی(ع) وہ ہستی ہیں جو لوگوںپر خدائی حدود جاری کرتے، انہیں تازیانہ مارتے اور یقینی شرعی حد کے مطابق کسی کا ہاتھ کاٹتے لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے منہ نہ پھیرتے اور ان کی محبت میں کوئی کمی نہ آتی۔ آپ (ع) خود فرماتے ہیں:
لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علیٰ ان یبغضنی ما ابغضنی، و
اگر تو دیکھے کہ میں اپنی اس تلوار سے مومن کو ماروں کہ وہ میرا دشمن ہو جائے تب بھی وہ میرے ساتھ دشمنی نہیں کرے
لو صببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبّنی ما احبنی، و ذٰلک انه قضی فانقضی علی لسان النبی الا می انه قال: یا علی لا یبعضک مؤمن و لا یحبک منافق ۔(۱)
گا اور اگر ساری دنیا کسی منافق کو دے دوں کہ وہ مجھے دوست رکھے تب بھی ہرگز میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا کیونکہ یہ بات گزر چکی اور پیغمبر امی (ص) کی زبان پر جاری ہو چکی ہے۔ فرمایا: اے علی( ع ) مومن تجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا اور منافق دوستی نہیں رکھے گا ۔
علی(ع) فطرتوں اور طینتوں کی پرکھ کے لیے ایک معیار اور میزان ہیں۔ جس کی فطرت صحیح اور طینت پاکیزہ ہو وہ ان سے ناراض نہیں ہوتا خواہ ان کی شمشیر اس پر ٹوٹے اور جو آلودہ فطرت رکھتا ہے ا سے ان سے محبت نہیں ہوتی اگرچہ وہ اس پر احسان بھی کریں۔ کیونکہ وہ مجسم حقیقت کے علاوہ کچھ اور نہیں۔
امیر المؤ منین (ع) کے دوستداروں میں ایک شریف اور ایماندار شخص تھا بدقسمتی سے ایک لغزش اس سے سرزد ہوگئی اور اس پر حد جاری کرنا ضروری ہوگیا۔ امیرالمؤمنین(ع) نے اس کا داہنا ہاتھ قطع کیا۔ اس نے اس (قطع شدہ ہاتھ) کو بائیں ہاتھ سے پکڑا۔ خون بہ رہا تھا اور وہ جارہا تھا۔ ابن الکواء باغی خارجی نے اس موقعہ سے اپنے گروہ کے حق میں اور علی (ع) کے خلاف فائدہ اٹھانا چاہا، ہمدردانہ قیافہ بنا کر نزدیک گیااور کہا: تیرا ہاتھ کس نے قطع کیا؟ اس نے کہا:
قطع الیمینی سیّد الوصین و قائد الغر المحجلین و اولی الناس بالمؤمنین علی ابن ابی طالب، امام الهدیٰ، السابق الی جنات النعیم ،مصادم الابطال، المنتقم من الجهال معطی الزکاة،
میرا ہاتھ پیغمبروں کے جانشینوں کے سردار، قیامت کے دن سرخرو ہونے والوں کے پیشوا، مؤمنوں پر سب سے زیادہ حق رکھنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السّلام، ہدایت کے امام، نعمت والی جنتوں کی طرف پہل کرنے والے، بہادروں کا مقابلہ کرنے والے، جاہلوں
الهادی الی الرشاد، و الناطق بالسّداد، شجاع مکی، جتحجاج و فی (۱)
سے انتقام لینے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، رشد و کمال کا راستہ دکھانے والے، سچ بات کہنے والے، مکہ کے شجاع اور بزرگوار وفا نے قطع کیا ہے۔
ابن الکواء نے کہا:افسوس ہے تجھ پر!اس نے تیرا ہاتھ قطع کیا اور تو اس کی اس طرح تعریفیں کرتا ہے؟
کہا: میں کیونکر اس کی تعریف نہ کروں۔ اس کی محبت میرے گوشت اور خون میں سرایت کرچکی ہے۔ خدا کی قسم اس نے میرا ہاتھ قطع نہیں کیا ہے مگر یہ کہ خدا کے مقرر کردہ قانون کے تحت۔
____________________
(۱)بحار الانوار ج۔۴۰، ص ۲۸۱۔۲۸۲، جدید ایڈیشن و تفسیر کبیر فخر رازی ذیل آیت ۹، سورہئ کہف ام حسبت...
اس قسم کے عشق اور اس طرح کی محبتیں جو علی(ع) اور ان کے دوستوں کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں عشق و محبت کے مسئلہ اور اس کے آثار کی طرف متوجہ کرتی ہیں ۔
اکسیرِ محبت
فارسی زبان کے شعراء نے عشق کو اکسیر کا نام دیا ہے۔ کیمیا گروں کا اعتقاد تھا کہ دنیا میں ایک ایسا مادہ اکسیر(۱) یا کیمیاکے نام سے موجود ہے جو ایک مادہ کو دوسرے مادہ میں تبدیل کر سکتا ہے۔ صدیوں وہ اس کے پیچھے پھرتے رہے۔شعراء نے اس اصطلاح کو مستعاراور کہا ہے کہ حقیقت میں وہ اکسیر جو
____________________
(۱) برہان قاطع میں اکسیر کے بارے میں کہا گیا ہے: ''ا یک جوہر ہے جو پگھلانے، آمیزش اور کامل کرنے والا ہے '' یعنی تانبے کو سونا بناتا ہے اور فائدہ مند دواؤں اور مرشد کامل کی نظر کو بھی مجازاً اکسیر کہتے ہیں۔ اتفاق سے عشق میں بھی یہ تینوں خصوصیات موجود ہیں۔ پگھلانے والا بھی ہے، آمیزش بھی ہوتی ہے اور کامل کنندہ بھی ہے لیکن مشہور و معروف وجہ شبہ تیسری ہی ہے۔ یعنی مکمل بدل دینا اور اسی لیے شعراء نے کبھی عشق کو طبیب، دوا، افلاطون اور جالینوس بھی کہا ہے۔ مولانا روم مثنوی کے دیباچے میں کہتے ہیں:
شادباش ای عشق خوش سودای ما
اے ہمارے عشق خوش سودا تو خوش رہ
ای طبیب جملہ علتہای ما
اے ہماری تمام بیماریوں کے طبیب
ای دوای نخوت و ناموس ما
اے ہمارے فحر اور وقار کی دوا
ای تو افلاطون و جالینوس ما
اے ہمارے افلاطون اور جالینوس
(ایک مادہ کو دوسرے مادہ میں) تبدیل کرسکتا ہے وہ عشق و محبت ہے۔ جو (کسی شئے کی) ماہیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ عشق مطلقاً اکسیر ہے اور اس میں کیمیا کی خاصیت ہے۔ یعنی ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان بھی مختلف دھات ہیں:
الناس کمعدن الذھب و الفضۃ ۔
انسان سونے اور چاندی کے معدن کی طرح ہیں۔
عشق ہی دل کو دل بناتا ہے۔ اگر عشق نہیں تو دل ہی نہیں آب و گل ہے۔
ہرآںدل را سوزی نیست دل نیست
جس دل میں درد نہیں وہ دل ہی نہیں
دل افسردہ غیر از مشت گل نیست
افسردہ دل مٹھی بھر مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں
لہٰی! سینہئِ دہ آتش افروز
خدایا! ایک بھڑکتا ہوا سینہ دے
در آں سینہ دلی و ان دل ہمہ سوز(۱)
اور اس سینے میں سلگتا ہوا دل دے
____________________
(۱) وحشی کرمانی
طاقت و قدرت عشق کی پیداوار ہیں۔ محبت طاقت پیدا کرتی ہے اور بزدلوں کو بہادر بنا دیتی ہے۔ ایک پالتو مرغی جب تک تنہا ہے اپنے بال و پر اپنی پشت پر جمع کرلیتی ہے۔ آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ اپنی گردن موڑ کر کوئی مکوڑا تلاش کرتی ہے تاکہ اسے کھائے۔ ذرا سی آواز سن کر بھاگ جاتی ہے۔ ایک کمزور بچے سے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی اپنے اندر نہیں پاتی۔ لیکن یہی مرغی جب چوزے نکالتی ہے اور عشق و محبت اس کے پیکر وجود میں گھر کرتی ہے تو اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ پشت پر جمع شدہ بال و پر دفاع کے لیے اپنی آمادگی کی علامت کے طور پر نیچے گرا دیتی ہے، اپنے اوپر جنگ کی سی حالت طاری کردیتی ہے، یہاں تک کہ ا س کی آواز کا آہنگ بھی پہلے سے طاقت وراور دلیرانہ ہو جاتا ہے۔ پہلے کسی خطرے کے خیال سے ہی بھاگ جاتی تھی لیکن اب خطرے کے احتمال سے ہی حملہ کر دیتی ہے، دلیرانہ حملہ کرتی ہے۔ یہ محبت اور عش ہے جو ڈرپوک مرغی کو ایک دلیر جانور کا روپ دیتا ہے۔
عشق و محبت کاہل اور سست کو چالاک اور ذہین بنا دیتی ہے حتیٰ کہ کاہل کو تیز فہم بنا دیتی ہے۔
وہ لڑکا اور لڑکی جو شادی سے پہلے کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے تھے سوائے ان چیزوں کے جو براہ راست ان کی اپنی ذات سے مربوط ہوں، وہی جونہی ایک دوسرے سے دل وابستگی پیدا ہوئی اور انہوں نے خاندان کا ادارہ تشکیل دیا، پہلی بار کسی اور کی قسمت کے بارے میں دلچسپی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی دلچسپیوں کا دائرہ وسیع تر ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ان کے ہاں بچے نے جنم لیا ان کی فطرت بالکل بدل جاتی ہے۔ اب وہی سست اور کاہل لڑکا چالاک اور فعال ہوگیاہے اور وہی لڑکی جوبزور بھی اپنے بستر سے نہیں جاگتی تھی اب اپنے گہوارہ نشین بچے کی آواز سنتے ہی بجلی کی طرح لپکتی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے سستی ا ور کاہلی کو ختم کیا اور اس جوان کو اس قدر حساس بنا دیا؟ وہ عشق و محبت کے علاوہ کچھ نہیں۔
عشق ہی ہے جو بخیل کو سخی اور کمزور اور بے صبرے کو متحمل (مزاج) اور صابر بناتا ہے۔ یہ عشق کا ہی اثر ہے کہ ایک خود غرض مرغی جو صر ف اپنے لیے سوچتی تھی کہ کوئی دانہ جمع کرے اور اپنی حفاظت کرے، اب ایک سخی وجود بن گئی ہے کہ جب کوئی دانہ پیدا کیا اپنے چوزوں کو آواز دیتی ہے یا ایک ماں کو جو کل تک ایک بے نام صرف کھانے اور سونے والی زود رنج اور کمزور لڑکی تھی، بھوک، بے خوابی اور جسمانی تھکاوت کے مقابلے میں صبر اور تحمل کی عظیم قوت دی اور ممتا کی تمام زحمتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا۔
روح کی سختی و تندخوئی ختم کرکے نرمی و رقت کا پیدا ہونااور دوسرے لفظوں میں (دوسروں سے) مہربانی و نرم خوئی سے پیش آنا اور اسی طرح صلاحیتوںکے انتشار و افتراق کو ختم کرے انہیں یکجا کرنااور اس یکجہتی کے نتیجے میں قدرت و طاقت کا حصول سب عشق و محبت کے آثار ہیں۔
شعر و ادب کی زبان میں عشق کے جس اثر کا بیشتر ذکر ہم دیکھتے ہیں وہ وجدان اور عشق کی فیاضی ہے۔
بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنہ نہ بود
این ہمہ قول و غزل تعبیہ در منقارش(۱)
بلبل نے نغمہ سنجی گل کے فیض سے سیکھی ورنہ یہ فصاحت و نغمگی اس کی منقار میں نہ ہوتی
فیض گل اگرچہ ظاہری لفظ کے اعتبار سے بلبل کی ذات سے خارج ایک امر ہے لیکن در حقیقت خود عشق کی قوت کے علاوہ کچھ نہیں۔
تو مپندار کہ مجنون سر خود مجنون شد
از سمک تابہ سماکش کشش لیلیٰ بود(۲)
یہ خیال نہ کرنا کہ مجنوں خود بہ خود مجنون بن گیا بلکہ لیلیٰ کی کشش نے سمک (مچھلی) سے سماء (آسمان) تک پہنچایا
____________________
(۱) لسان الغیب حافظ
(۲) علامہ طباطبائی
عشق خوابیدہ صلاحیتوں کوبیدار اور بند جکڑی ہوئی قوتوں کو آزاد کر دیتا ہے جس طرح ایٹم کے پھٹنے پر ایٹمی توانائیاں آزاد ہوجاتی ہےں۔
عشق وجدان عطا کرتااور ہیرو پیدا کرتا ہے۔ کتنے ہی شاعر، فلسفی اور ہنرمند ایک طاقت ور عشق و محبت کی پیداوار ہیں۔
عشق روح کی تکمیل کرتااور حیرت انگیز باطنی صلاحیتوں کو آشکار کرتا ہے۔ ادارک کی قوتوں کے نقطہئ نگاہ سے یہ وجدان عطا کرتااور احساس کی قوتوں کے نقطہئ نظر سے ارادہ اور ہمت کو تقویت دیتا ہے اور جب یہ عروج کی طرف بڑھتا ہے تو کرامت اور معجزہ ظاہر کرنے لگتا ہے۔ روح کو بیماریوں اور آلودگیوں سے پاک کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عشق صفائی (باطن) کرنے والا ہے۔ خود غرضی سے پیدا ہونے والی پست صفات یا بخل، کنجوسی، بزدلی، کاہلی، تکبر و خود پسندی جیسے ٹھنڈے جذبات کو ختم کر دیتا ہے۔ آپس کی نفرتوں اور کینوں کو زائل کرتا ہے۔اگرچہ عشق میں محرومیت اور ناکامی کابھی امکان ہے۔ تب یہ مشکلات اور عداوتیں پیدا کرتا ہے۔
از محبت تلخہا شیرین شود
از محبت مسہا زرین شود(۱)
محبت تلخیوں کو شیرینی میں بدل دیتی ہے۔ محبت تانبے کو سونے میں بدلتی ہے۔
____________________
(۱) مثنوی معنوی
عشق کا اثر روح کے لیے اس کی آبادی اور شادابی ہے اور جسم کے لیے زوال اور خرابی ہے۔ جسم کے لیے عشق ویرانی کا باعث اور چہرے کی زردی، جسم کی کمزوری، ہاضمے کی خرابی اور اعصاب کے لےے تناؤ کا موجب ہے۔ شاید جسم کے لےے تمام آثار تخریبی ہوں، لیکن روح کے لےے ایسا نہیں ہے۔
پھر عشق کا موضوع کیا ہو؟ اور کس طرح ایک شخص اس سے فائدہ اٹھائے؟
اس کے اجتماعی آثار سے قطع نظر، روح اور فرد کے نقطہئ نظر سے یہ تکمیلی ہے کیونکہ یہ قوت، نرمی، صفا، یکجہتی اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ کمزوری، زبونی، کدورت، افتراق اور کاہلی کو ختم کر دیتا ہے۔ آلودگیوں جنہیں قرآن دسَّ کا نام دیتا ہے، ختم کرتا، آمیزشوں کو زائل کرتااور فریب کو خلوص سے بدل دیتا ہے۔
شاہ جان مرجسم را ویران کند
دل کا بادشاہ جسم ویران کرتا ہے
بعد ویرانش آبادان کند
اور اس کے بعد اسے آباد کرتا ہے
ای خنک جانی کہ بھر عشق و حال
نیک دل وہ ہے جو عشق اور خوشی کی خاطر
بذل کرد او خان و مان و ملک و مال
اپنا گھر بار جائداد اور مال صرف کرے
کرد ویران خانہ بہر گنج زر
اس نے اپنا گھر خزانہ کے لیے ویران کیا
و ز ہمان گنجش کند معمور تر
اور اسے مزید زر سے بھر دیا
آب را ببرید و جو را پاک کرد
وہ پانی لے گیا اور نہر کو خالی کیا
بعد ازاں در جو رواں کرد آب خورد
پھرپانی کو نہر میں جاری کر دیا اور پانی پیا
پوست را بشگافت پیکان را کشید
اس نے پوست کو شگافتہ کیا اور پیکان کھینچا
پوست تازہ بعد از آتش برومید
اس کے بعد اس پر تازہ پوست اسے پہنچایا
کاملان کز سرّ تحقیق آ گھند
کامل لوگ جو تحقیق کے رازکو جانتے ہیں
بی خود حیران و مست و والہ اند
وہ بے خود، حیران اور مست ہیں
نہ چنین حیران کن پشتش سوی اوست
بل چنان حیران کہ غرق و مست دوست(۱)
اس طرح حیران نہ ہو کہ اس کی پشت تیری طرف ہوبلکہ اس طرح حیران کردہ محبوب کی محبت میں غرق ہو۔
____________________
(۱) مثنوی معنوی
حصار شکنی
قطع نظر اس سے کہ اس کی نوعیت جنسی ہے، نسلی ہے یا انسانی، نیز قطع نظر اس سے کہ محبوب کس طرح کی صفات اور خصوصیات کا حامل ہے۔ دلیر اور بہادر ہے، ہنر مند ہے، عالم ہے، یا مخصوص اخلاق و آداب اور خوبیوں کامالک ہے، عشق و محبت انسان کو خودی اور خود پرستی (کے خول) سے باہر نکالتی ہے۔ خود پرستی محدودیت اور حصار ہے۔ کسی دوسرے کے ساتھ عشق مطلقاً اس حصار کو توڑ دیتا ہے۔ جب تک انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتا وہ کمزور، ڈرپوک، چمک دمک نہیں ہوتی، جوش اور ولولہ نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت سرد اور خاموش ہوتا ہے۔ مگر جونہی انسان اپنی ذات کے خول سے باہر قدم رکھتا اور خودی کے حصار کو توڑ دیتا ہے، یہ ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہےں۔
ہر کرا جامہ زعشقی چاک شد
او ز حرص و عیب کلی پاک شد
جس کا جامہ کسی عشق میں چاک ہوا۔ وہ لالچ اور دیگر عیوب سے بالکل پاک ہوا ۔
خود پرستی کے حصار کو توڑ دینے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ دلچسپی کو یکسر نظر ختم کر دے اور یوں خود پرستی سے آزاد ہو۔ یہ بات بے معنی ہے کہ کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ اپنی ذات کو دوست نہ رکھے۔ اپنی ذات سے دلچسپی جسے حُبّ ذات سے تعبیر کیا جاتا ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے کہ جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ انسان کی اصلاح اور تکمیل اس طرح نہیں ہوتی کہ اس مفروضے پر کہ انسان کے وجود میں چند غیر ضروری امور ہیں اور یہ کہ ان غیر ضروری اور مضر امور کو معدوم کر دیا جاناچاہیے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کی اصلاح اس کے وجود سے کسی شئے کو کم کرنے میں نہیں بلکہ اس (وجود) کی تکمیل اور اس میں اضافہ کرنے میں ہے۔ فطرت نے انسان پر جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ خلقت کا تکامل اور اس میں اضافہ کرنا ہے، نہ کہ اس میں کمی کرنا۔
خود پرستی کامقابلہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی '' ذات '' کو محدودیت سے بچایا جائے۔ اس ''خود '' کو وسعت پانا چاہیے اور ''خود '' کے گرد جو حصار کھینچا گیا ہے اسے توڑ دیا جانا چاہےے جس کی وجہ سے اس سے مربوط شخص یا فرد کے علاوہ ہر چیزبیگانہ اور ''خود '' سے خارج نظر آتی ہے۔ شخصیت کو اس قدر وسعت پا جانا چاہےے کہ تمام انسانوں بلکہ پوری کائنات کا احاطہ کرے۔ پس خود پرستی سے مقابلہ کرنے کا مطلب اپنی ذات کی محدودیت کا مقابلہ کرناہے، کیونکہ خود پرستی افکار اور میلانات کو محدود کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عشق، انسان کی دلچسپی اور اس کے میلانات کو اس کی ذات سے باہر لے جاتا، اس کے وجود کو وسعت بخشتا اوراس کے پیکر ہستی کو بدل دیتا ہے اوراسی لیے عشق و محبت ایک عظیم اخلاقی اور تربیتی عنصر ہے بشرطیکہ صحیح ہدایت ہواور صحیح طریقے سے اس سے استفادہ کیا جائے۔
عشق۔ تعمیر ہے یا تخریب
کسی شے یا شخص کی محبت جب شدت کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے ا س طرح کہ انسان کے وجود کو مسخر کرکے اس کے وجود پر اس کی مکمل حکمرانی ہو، تو اس کانام عشق ہے۔ عشق محبت اور جذبات کی انتہا ہے۔
لےکن یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جسے یہ (عشق) نام دیا جاتا ہے اس کی صرف ایک قسم ہے۔ اس کی مکمل طور پر دو مختلف قسمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کے نتائج کو اچھا کہا جائے لیکن اس (عشق) کی دوسری قسم کے نتائج مکمل تخریبی اور منفی ہیں۔
انسانی جذبات کی قسمیں اور مراتب ہیں۔ ان میں سے ایک شہوت، خاص طور پر جنسی شہوت کی قسم ہے جو کئی اعتبار سے انسان اور تمام حیوانات میں مشترک ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ انسان میں یہ جذبہ ایک خاص اور ناگفتہ علت کی بناء پر انتہائی شدت اختیا رکرتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس کا ناعشق رکھ لیتے ہیں اور حیوان میں (یہ جذبہ) اس طرح نہیں ہوتا لیکن بہرحال اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے یہ شہوت کے جوش، شدت اور طوفان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ (جذبہ) جنسی ذرائع سے پیدا ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے۔
اس میں افزائش اور کمی کا تعلق آلہئ تناسل کی طبعی کارکردگی اور قہراً سن جوانی سے ہے۔ ایک طرف عمر میں اضافے اور دوسری طرف رُجھ جانے اور طاقت میں کمی کے ساتھ یہ کم ہوتا اور بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔
اس جوان کو جو کسی حسین چہرے اور زلف پیمان کودیکھتے ہی لرزنے اور کسی نرم و نازک ہاتھ کے لمس سے ہی بل کھانے لگتا ہے، یہ جان لینا چاہیے کہ معاملہ مادی اور حیوانی اثر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کے عشق جلد آتے ہیں اور جلد جاتے ہیں۔ یہ قابل اعتماد ہے نہ قابل تعریف بلکہ خطرناک اور فضیلت کش ہے۔ صرف وہی شخص فائدے میں رہتا ہے جو پاکدامنی اور تقویٰ کی مدد سے اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے۔ یعنی یہ قوت بذات خود انسان کو کسی فضیلت کی طرف آمادہ نہیں کرتی لیکن اگر یہ آدمی کے وجود میں رخنہ ڈالے اور پاکدامنی اور تقویٰ کی قوت سے اس کی کشمکش ہو اور روح اس کے دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے اس کے سامنے سپر نہ ڈالے تو روح کو قوت و کمال بخشتی ہے۔
انسان جذبات کی ایک دوسری قسم رکھتا ہے جو اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے شہوت سے مختلف ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اسے محبت (عاطفہ) یا قرآن کی تعبیر میں ''مؤدت '' اور ''رحمت '' کا نام دیں۔
انسان جب تک اپنی شہوتوں کے زیر اثر ہے وہ (گویا) اپنی ذات سے باہر نہیں نکلا ہے۔ وہ اپنی پسند کی چیز یا شخص کو اپنے لیے طلب کرتااور شدت سے چاہتا ہے۔ اگر وہ معشوق اور محبوب کے بارے میں سوچتا ہے تو اس طرح سوچتا ہے کہ کس طرح اس کے وصال سے بہرہ مند ہو اور زیادہ سے زیادہ لطف اٹھائے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال انسان کی روح کی تکمیل، تربیت اور اسے پاکیزہ نہیں کر سکتی۔
لیکن جب انسان اپنے اعلیٰ انسانی عواطف کے زیر اثر قرار پاتا ہے تو محبوب و معشوق اس کی نظر میں احترام و عظمت پیدا کرتا ہے اور وہ اس (محبوب و معشوق) کی نیک بختی چاہتا ہے۔ وہ محبوب کی خواہشات پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوجاتا ہے۔ اس طرح کے عواطف خلوص، راستی، فیاضی، نرم خوئی اور ایثار پیدا کرتے ہیں۔ برخلاف پہلی قسم کے جس سے تند خوئی، درندگی اور جنایت ابھرتی ہےں۔ بچے لےے ماں کی مہرو محبت اسی قسم سے ہے۔ اولیاء اور مردان خدا سے محبت، اسی طرح وطن سے محبت بھی اسی قسم سے ہے۔ یہ جذبات کی وہ قسم ہے کہ اگر انتہائے کمال کو پہنچ جائے تو وہ تمام اچھے نتائج جن کی ہم نے پہلے تشریح کی ہے، مرتب ہوتے ہیں اور یہی قسم ہے جو روح کو بلندی، انفرادیت اور عظمت عطا کرتی ہے۔ جبکہ پہلی قسم روح کو زبوں کرنے والی ہے اور عشق کی یہی قسم ہے جو پائدار ہے اور وصال سے یہ اورتیز و تند ہوجاتا ہے۔ ا س کے برعکس پہلی قسم ناپائدار ہے اور وصال اس کا مدفن شمارہوتا ہے۔
قرآن کریم میاں بیوی کے رابطہ کو ''مودت '' اور ''رحمت'' کے کلمات سے تعبیر(۱) کرتا ہے اور یہ بہت اہم نکتہ ہے اور ازدواجی زندگی میں حیوانی سطح سے بلند جو انسانی پہلو ہے اس کی طرف اشارہ ہے نیز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف شہوت کا عنصر ہی ازدواجی طبعی زندگی سے مربوط نہیں ہے بلکہ اصلی رابطہ خلوص، سچائی اور دو روحوں کے درمیان اتحاد ہے۔ دوسرے لفظوں میں میاں بیوی کو یگانگت کے رشتے میں منسلک کرنے والی چیز محبت و مودت اور خلوص و سچائی ہے نہ کہ شہوت جو حیوانوں میں بھی ہے۔
مولوی(۲) اپنے خوبصورت انداز میں شہوت اور مودت میں فرق بیان کرتے ہوئے اُس (شہوت) کو حیوانی اور اس (مودت) کو انسانی قرار دیتا ہے۔ کہتا ہے:
____________________
(۱)وَ مِنْ اٰیٰتِه اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوْآ اِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمََةَ ۔(۳۰روم:۲۱) اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی ۔
(۲)مولانا رومی
خشم و شہوت وصف حیوانی بود
مہر و رقت وصف انسانی بود
غصّہ اور شہوت حیوانی صفات ہیں
محبت و مہربانی انسانی اوصاف ہیں
این چنین خاصیتی در آدمی است
مہر حیوان را کم است آن از کمی است
ایسی خوبیاں انسان میں ہیں
حیوان میں محبت کی کمی ہے، اور یہ اس کا نقص ہے۔
مادیت کے فلسفے کا پرچار کرنے والے بھی انسان کی اس معنوی حالت سے انکار نہیں کرسکے ہیں جو کئی جہات سے غیر مادی ( Metaphysical ) پہلو رکھتی ہے اور انسان اور مافوق انسان کے مادی ہونے (کے فلسفے) سے سازگار نہیں ہے۔ برٹرینڈرسل اپنی کتاب ''شادی اور اخلاق '' میں کہتا ہے:
ایسا کام جس کا واحد مقصد کمانا ہو مفید نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے نتیجے کے لیے اس کام کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں ایک فرد یا ایک مقصد یا غایت پر یقین پوشیدہ ہو۔ عشق کا مقصد بھی اگر محبوب کا وصال ہو تو وہ ہماری شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتا اور مکمل طورپر ایسے کام کی طرح ہے جو ہم پیسے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اس کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ محبوب کے وجود کو اپنے وجود کی طرح جانیںاور اس کے جذبات و احساسات کو اپنا سمجھیں۔
دوسرا نکتہ جس کا ذکر کرنااور جس کی طرف توجہ دینا چاہیے یہ ہے کہ شہوانی عشق بھی ممکن ہے فائدہ مند واقع ہو اور ایسااس وقت ہو سکتا ہے جب وہ تقویٰ اور پاک دامنی کے ساتھ مربوط ہو۔ یعنی ایک طرف فراق و نارسائی اور دوسری طرف پاکیزگی و عفت کی وجہ سے روح پرجو سوز و گداز اور دباؤ اور سختی وارد ہوتی ہے اس کے مفید نتائج نکل سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں عرفاء کہتے ہی ںکہ عشق مجازی، عشق حقیقی یعنی ذات احدیت کے ساتھ عشق میں تبدیل ہوجاتا ہے اوراسی سلسلے میں روایت کرتے ہیں:
من عشق و کتم و عف و مات مات شهیدا
جو عشق کرے اوراسے پوشیدہ رکھے اور پاک دامنی کی حالت میں مرجائے تو وہ شہید مرا ہے۔
لیکن اس نکتے کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے کہ عشق کی یہ قسم ان تمام فوائد کے باوجود جو یقیناً مخصوص حالات میں حاصل ہوتے ہیں، قابل تعریف نہیں ہے اور بہت خطرناک ہے۔ اس لحاظ سے یہ مصیبت کی مانند ہے جو اگر کسی پر آپڑے اور وہ صبر و رضا کی قوت سے اس کا مقابلہ کرے تو نفس کو پاک اور مکمل کرنے والی ہے، خام کو پختہ اور آلودہ کو صاف کرتی ہے۔ لیکن مصیبت قابل تعریف نہیں ہے۔ کوئی شخص اس تربیتی عنصر سے فائدہ اٹھانے کی خاطر اپنے لیے مصیبت پیدا کرے۔
رسل یہاں بھی ایک قیمتی بات کہتا ہے:
قوت ( Energy ) رکھنے والے شخص کے لیے مصیبت ایک گرانبہا محرک ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو مکمل طور پر خوش بخت سمجھتا ہے، وہ مزید خوش بختی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس بات کا جواز ہو کہ ہم دوسروں کو اس لیے رنج پہنچائیں تاکہ وہ کسی مفید راہ میں طرف قدم بڑھائیں۔ کیونکہ عموماً اس کا نتیجہ اس کے برعکس ہوتا ہے اور انسان کو درہم برہم کر دیتا ہے۔
اس طرح تو یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ان حادثات کے حوالے کر دیں جو ہمارے راستے میں پیش آتے ہیں۔(۱)
چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں مصائب اور آزمائشوں کے نتائج اور فوائد کی طرف بہت اشارہ کیا گیا ہے اور خدا کے لطف کی علامت کے طور پر انہیں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن کسی لحاظ سے بھی کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ اس بہانے سے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کوئی مصیبت پیدا کرے۔
اس کے علاوہ عشق اور مصیبت کے درمیان ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ عشق کسی اور عنصر کے مقابلہ میں زیادہ '' عقل کی ضد '' ہے۔ یہ جہاں بھی قدم رکھتا ہے عقل کو اس کی مسند حکومت سے معزول کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفانی ادب میں عقل و عشق کو دو رقیب کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ فلسفیوں اور عرفاء کے درمیان رقابت کا سرچشمہ بھی یہی ہے۔ فلسفی عقل کی قوت پر اور عرفاء عشق کی قوت پر تکیہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ رقابت کے اس میدان میں عرفانی ادبیات میں عقل کی پہچان محکوم و مغلوب کی حیثیت سے کرائی گئی ہے۔ سعدی کہتا ہے:
نیک خواہانم نصیحت می کند
میرے خیر خواہ نصیحت کرتے ہیں
خشت بردیا زدن بے حاصل است
سمندر میں اینٹ پھینکنا (کسی شئے کی بنیاد رکھنا) بے نتیجہ ہے۔
شوق را برصبر قوت غالب است
صبر پر شوق غالب ہے
____________________
(۱)''شادی اور اخلاق،، ص ۱۳۴
عقل را بر عشق دعویٰ باطل است
عشق پر عقل کا دعویٰ باطل ہے
ایک دوسرا (شاعر) کہتا ہے:
قیاس کردم تدبیر عقل در رہ عشق
چوشبنمی است کہ بربحرمی زند رقمی
میرا خیال ہے کہ عشق کی راہ میں عقل کی تدبیرایسی ہے کہ شبنم سمندر (کی سطح) پر کچھ لکھنے کی کوشش کرے۔
ایک ایسی قدرت والی طاقت جو زمام اختیار (دوسروں کے ہاتھ سے) چھین لیتی ہے اور بقول مولوی ''یہ (عشق) آدمی کو ادھر سے ادھر کھینچ لے جاتا ہے جس طرح سخت طوفان تنکے کو ''اور رسل کے بقول '' ایک ایسی چیز جو انارکی کی طرف مائل ہے '' کس طرح ممکن ہے کہ اس کی سفارش کی جائے۔
بہرحال کبھی کبھار مفید نتائج کا حامل ہونااور بات ہے اور قابل تجویز و سفارش ہونا دوسری بات۔
یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فقہاء کی طرف سے ان اسلامی فلاسفروں(۱) پر جنہوں نے الہٰیات کے ضمن میں اس پر بحث کی ہے اور اس کے نتائج و فوائد کو بیان کیا ہے، اعتراض اور تنقید صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس طبقہ (فقہائ) نے یہ خیال کیا ہے کہ حکماء کے اس دستہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ (عشق) قابل تجویز و سفارش بھی ہے حالانکہ ان کی نظر صرف ان مفید نتائج پر ہے جو تقویٰ اور پاک دامنی کی حالت میں برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے قابل تجویز و سفارش سمجھتے ہوں۔ یعنی بعینہ مصائب اور آزمائشوں کی طرح۔
____________________
(۱)بوعلی سینا۔ رسالہئ عشق اورصدر المتألهین سفر سوم اسفار
اولیاء سے محبت و ارادت
جیسا کہ ہم نے کہا ہے عشق و محبت، عشق حیوانی جنسی اور حیوانی نسلی میں منحصر نہیں ہے بلکہ عشق و جاذبہ کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کی سطح بلند تر ہے اور اساسی طور پر مادہ اور مادیات کی حدود سے باہر ہے اور اس کا سرچشمہ بقائے نسل کے جذبے سے ماوراء ہے اور حقیقت میں انسان اور حیوان کے درمیان فصل ممیز ہے اور وہ عشق معنوی اور انسانی ہے۔ بلند انسانی فضائل ، خوبیوں اور جمال حقیقت کے ساتھ عشق۔
عشقہای کز پی رنگی بود
کسی رنگ کے ساتھ عشق کرنا
عشق نہ بود عاقبت ننگی بود
درحقیقت عشق نہیں، عاقبت کی رسوائی ہے
زانکہ عشق مردگان پایندہ نیست
مردوں کے ساتھ عشق پائدار نہیں
چوںکہ مردہ سوی ماآیندہ نیست
کیونکہ مردہ پھر ہمارے پاس نہیں آتا
عشق زندہ در روان و دربصر
جسم و نظر میں زندہ کا عشق
ہر دو می باشد ز غنچہ تازہ تر
دونوں کو غنچے سے زیادہ ترو تازہ رکھتا ہے
عشق آں زندہ گزین کز باقی است
اس زندہ سے عشق کرو جو ہمیشہ باقی ہے
و ز شراب جانفزایت ساقی است
جو تجھے زندگی کی شراب پلانے والا ہے
عشق آن بگزین کہ جملہ انبیائ
اس سے عشق کرو کہ سب پیغمبروں نے
یافتند از عشق او کار و کیا
اسکے عشق سے مقصد اور عظمت کو پا لیا(۱)
اور یہی عشق ہے جسے قرآن کی بہت سی آیات میں محبت، وُدّ یا مودت کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ ان آیات کی چند قسمیں ہیں:
۱۔ وہ آیتیں جو مؤمنین کے وصف میں ہیں اور خدا یا مؤمنوں سے ان کی گہری دوستی و محبت کے بارے میں ہیں:
____________________
(۱) مثنوی معنوی
( وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْآ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ) (۱)
وہ لوگ جوایمان لاچکے ہیں خدا کی محبت میں سخت تر ہیں۔
( وَ الَّذِیْنَ تَبَوَّءُ و الدَّارَ وَ الْاِیْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَیْهِمْ وَ لَا یَجِدُوْنَ فِیْ صَُدُوْرِ هِمْ حَاجَةً مِِّمَّآ اُوْتُوْا وَ یُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ وَ لَو کَانَ بِهِمْ خَصَاصِةٌ ) ۔(۲)
جو لوگ مہاجروں سے پہلے مسلمانوں کے گھر (مدینہ) میں مقیم اور ایمان ( مسلمانوں کے روحانی اور معنوی گھر) میں رہے، ان مہاجروں سے محبت کرتے ہیںجو ان کی طرف آئے اور جو کچھ انہیں ملا اس سے اپنے دلوں میں کوئی ملال نہیںپاتے اور دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خودحاجت مند کیوں نہ ہوں۔
۲۔ وہ آیتیں جو خدا کی مؤمنوں سے محبت کے بارے میں ہیں:
( اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ ) (۳)
خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔
( وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ) ۔(۴)
خدا نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے ۔
( اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ ) ۔(۵)
خدا تقویٰ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
( وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمَطَّهِّرِیْنَ ) (۶)
خدا پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے ۔
( اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ ) ۔(۷)
خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
____________________
(۱) ۲ بقرہ :۱۶۵ ---(۲) ۵۹ حشر : ۹ ---(۳) ۲ بقرہ : ۲۲۲---(۴) ۳ آل عمران :۱۴۸ و ۵ مائدہ : ۱۳ ---(۵) ۹ توبہ : ۴ و۷
(۶) ۹ توبہ :۱۰۸---(۷) ۴۹ حجرات :۹۔ ۶۰ممتحنہ:۸
۳۔ وہ آیتیں جو دو طرفہ دوستیوں اور دو آتشہ محبتوں کے بارے میں ہیں۔ خدا کی مومنوں سے محبت، مؤمنوں کی خدا سے محبت اور مؤمنوں کی ایک دوسرے سے محبت:
( قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْلَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ .) (۱)
کہ دو اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا تم سے محبت کرے اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے ۔
( فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه ) (۵:۵۴)
خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا جس کو (خدا) دوست رکھتا ہو گا اور وہ (قوم) اس (خدا) کو دوست رکھتی ہو گی۔
مؤمنین کی آپس میں محبت
( اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ) ۔(۲)
جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل بجا لائے ہیںان کے لیے رحمن عنقریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔
( وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ) .(۳)
اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی۔
اور یہی وہ محبت اور تعلق ہے جسے ابراہیم(ع) نے اپنی ذریت کے لیے طلب کیا(۴) اور خدا کے حکم سے پیغمبر ختمی مرتبت(ص) نے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے طلب فرمایا۔(۵)
اور جس طرح کہ روایات سے پتہ چلتا ہے دین کی روح اور اس کا جوہر محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ برید عجلی کہتا ہے:
میںامام باقر علیہ السّلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک مسافر، جو خراسان سے اس طویل مسافت کو پیدل طے کر کے آیا تھا،امام (ع)کے حضور شرفیاب ہوا اس نے اپنے
____________________
(۱) ۳ آل عمران: ۳۱ -----(۲) ۱۹طہ:۹۶-----(۳) ۳۰ روم :۲۱ ---(۴) ابراہیم: ۳۷ ---(۵) شوریٰ : ۲۳
پیر جب جوتوں سے باہر نکالے، تو وہ شگافتہ ہو کر خراب ہوچکے تھے۔ اس نے کہا خدا کی قسم! مجھے وہاں سے سوائے اہل بیت (ع) کی محبت کے اور کوئی چیز یہاں کھینچ نہ لائی امام (ع) نے فرمایا: خدا کی قسم! اگر کوئی پتھر بھی ہم سے محبت کرتا ہو توخدا اسے(قیامت کے دن) ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا اور ہمارے قریب کر دے گا،وهل الدین الا الحب ۔ (یعنی) کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے؟(۱)
کسی نے امام جعفر صادق علیہ السّلام سے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے نام آپ اور آپ (ع) کے آباء کے ناموں پر رکھتے ہیں کیا ہمیں اس کام کا کوئی فائدہ ہے؟ حضرت (ع) نے فرمایا:
کیوں نہیں خدا کی قسمو هل الدین الا الحبّ کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے؟'' اس کے بعد (اس کی تائید میں) آیہئ شریفہ( اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ ) (۲) کی تلاوت فرمائی۔(۳)
بنیادی طور پر محبت ہی ہے جو پیروی کراتی ہے۔ عاشق کی مجال نہیں ہے کہ وہ معشوق کی خواہش سے سرتابی کرے۔ ہم اس (صورت حال) کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک جوان عاشق اپنی معشوقہ اور محبوبہ کے لیے ہر شئے سے دستبردار ہوتا ہے اور ہر چیز اس پر قربان کر دیتا ہے۔
____________________
(۱) سفینۃ البحار، ج ۱ ص ۲۰۱ مادہ حُبّ
(۲) ۳ آل عمران : ۳۱
(۳)سفینۃ البحار، ج ۱، ص ۲۰۱ مادہ ''سما ''
خدا کی اطاعت اور اس کی پرستش اس محبت اور عشق کی نسبت سے ہے جو انسان خدا سے رکھتا ہے۔ جس طرح کہ امام صادق علیہ السّلام فرماتے ہیں:
تعصی الاله و انت تظهر حبّه
هذا لعمری فی الفعال بدیع
لو کان حبک صدقا لا طعته
ان المحب لمن یحب مطیع
خدا کے حکم کی نافرمانی کرو اور پھر بھی اس کی محبت کا دم بھرو۔ میری جان کی قسم! یہ عجیب رویہ ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو یقیناً اس کی اطاعت کرتا۔ کیونکہ محبت کرنے والا محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے۔
معاشرے میں محبت کی قوت
اجتماعی نقطہئ نظر سے محبت کی قوت ایک عظیم اور مؤثر قوت ہے۔ بہترین معاشرہ وہ ہے جو محبت کی قوت سے چلایا جائے۔ حاکم اور منتظم لوگوں سے اور لوگ حاکم اور منتظم سے محبت کرتے ہوں۔
حکمران کی محبت حکومت کی زندگی کے ثبات اور اس کی پائداری کا ایک عظیم عامل ہے اور جب تک محبت کا عنصر نہ ہو کوئی رہنما کسی معاشرے کی رہبری اور لوگوں کی قانونی نظم و ضبط کے تحت تربیت نہیں کر سکتا یا بہت مشکل سے کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اس معاشرے میں عدل و مساوات کو جاری و ساری بھی کرے۔ لوگ صرف اس وقت تک قانون کی پابندی کرتے ہیں جب تک وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حکمران کو ان سے محبت ہے اور یہی محبت ہے جو لوگوں کو پیروی اور اطاعت پر آمادہ کرتی ہے۔ قرآن پیغمبر (ص) سے خطاب کرتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان نفوذ حاصل کرنے اورمعاشرے کو چلانے کے لیے ایک عظیم قوت رکھتے ہو:
( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرٍ ) (۱)
آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے اور اگر آپ تند خو اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، پس ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے طلب مغفرت کرو اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔
____________________
(۱) ۳ آل عمران : ۱۵۹
یہاں پر پیغمبر (ص) کی طرف لوگوں کی رغبت کی وجہ اس مہر و محبت کو قرار دیا گیا ہے جو لوگوں کی نسبت پیغمبر اکرم (ص) عام فرماتے تھے۔ پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی بخشش کے لیے استغفارکی جائے اور ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے۔ یہ سب محبت اور دوستی کی علامتیں ہیں۔ جس طرح کہ نرمی، برداشت اور تحمل سب محبت اور احسان کے پہلو ہیں۔
اوبہ تیغ حل چندین خلق را
اسنے حلم کی تلوار سے اتنے لوگوں کو سدھارا
وا خرید از تیغ ، چندین حلق را
جبکہ لوہے کی تلوار اتنے ہی گلے کاٹتی
تیغ حلم از تیغ آہن تیز تر
حلم کی تلوار لوہے کی تلوارسے زیادہ تیزہے
بل ز صد لشکر، ظفر انگیز تر(۱)
بلکہ سو لشکر سے زیادہ فتح کرنے والی ہے
____________________
(۱) مثنوی معنوی
اور پھر قرآن فرماتا ہے:
( وَ لَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَه، عَدَاوَةٌ کَاَنَّه، وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ) .(۱)
اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتیں۔ آپ (بدی ) کو بہترین طریقے سے دفع کریں تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ گویا نہایت قریبی دوست بن گیا ہے
بہ بخش ای پسر کاد میزادہ مید
اے میرے بیٹے معاف کر دے
بہ احسان تو ان کرد، وحشی بہ قید
کہ آدمی کو احسان سے اور درندے کو جال سے شکار کیا جا سکتا ہے
عدو را بہ الطاف گردن بہ بند
دشمن کو مہربانی کے ذریعے جھکا دے
کہ نتوان بریدن بہ تیغ این کمند(۲)
کہ یہ کمند تلوار سے نہیں کاٹی جا سکتی
____________________
(۱) ۴۱ فصلت: ۳۴
(۲) سعدی، بوستان
امیر المومنین علیہ السلام مالک اشتر کو مصر کی گورنری پر مقرر کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ روش کے ضمن میں یوں ہدایت فرماتے ہیں:
و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفح ہ(۱)
اپنے دل میں لوگوں کے لیے محبت و ہمدردی اور مہربانی کا جذبہ بیدار کر... اپنے عفو و درگزر سے انہیں اس طرح فائدہ پہنچا جس طرح تو چاہتا ہے کہ خداوند عالم اپنے عفو و درگزر سے تجھے فائدہ پہنچائے۔
حکمران کے دل کو ملت کے ساتھ محبت و ہمدردی کا گھر ہونا چاہیے۔ صرف طاقت اور زور کافی نہیں ہے۔ طاقت اور زور کے ساتھ لوگوں کو بھیڑوں کی طرح ہنکانا تو ممکن ہے لیکن ان کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ان سے کام لینا ممکن نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ قدرت و زور کافی نہیں ہے بلکہ انصاف کا اجراء بھی اگر روکھے طریقے سے ہو توکافی نہیں ہے۔ حکمران کا ایک مہربان باپ کی طرح دل سے لوگوں کو دوست رکھنا اور ان سے ہمدردی جتانا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ (حکمران) ایک جاذب اور دل موہ لینے والی شخصیت کا مالک ہو تاکہ لوگوں کی محبت، ہمت اور ان کی عظیم انسانی صلاحیتوں کو آگے بڑھا سکے اور ان سے اپنے ہدف کی خدمت کاکام لے سکے۔
____________________
(۱)نہج البلاغہ، نامہ ۵۳
تہذیبِ نفس کا بہترین وسیلہ
عشق و محبت کے باب میں گزشتہ مباحث صرف مقدمہ تھیں اور اب ہم آہستہ آہستہ نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہماری اہم ترین بحث جو در حقیقت ہماری اصل بحث ہے، یہ ہے کہ اولیاء کے ساتھ عشق و محبت اور نیکو کاروں کے ساتھ دوستی رکھنا بذاتِ خود ہدف ہے یا تہذیب نفس، اصلاحِ اخلاق اور انسانی فضائل اور رفعتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔
عشق حیوانی میں، عاشق کی تمام تر نظر اور توجہ معشوق کی صورت، اعضاء کے تناسب اور اس کی جلد کے رنگ اور رعنائی پر ہوتی ہے۔ یہ ایک کشش ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی اور مجذوب بناتی ہے۔ لیکن اس کشش سے جی بھر جانے کے بعد یہ آگ پھر نہیں بھڑکتی، بلکہ سرد پڑ جاتی اور (بالآخر) بجھ جاتی ہے۔ لیکن عشق انسانی، جیساکہ ہم نے پہلے کہا ہے، حیات اور زندگی ہے، اطاعت کرانے اور پیروکار بنانے والا اور یہ عشق ہے جو عاشق کو معشوق کے ہمرنگ بناتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ معشوق کا ایک جلوہ ہو اور اس (معشوق) کی روش کا ایک عکس ہو۔ جس طرح کہ خواجہ نصیر الدین طوسی شرح اشارات بو علی میں کہتے ہیں:
و النفسانی هوالذی یکون مبدئه مشاکلة نفس العاشق لنفس المعشوق فی الجوهر و یکون ا کثر عجابه بشمائل المعشوق لانها آثار صادرة عن نفس... و هو یجعل النفس لینة شیقة ذات و جد و رقة منقطعة عن الشواغل الدنیویه (۱)
روحانی عشق وہ ہے جس کی بنیاد عاشق اور معشوق کی ذات میں ہمرنگی پر ہو۔ عاشق کی زیادہ تر توجہ معشوق کی روش اور اس کے (دل) سے ظاہر ہونے والے تاثرات پر رہتی ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو روح کو نرم، پر شوق اور سرشار بنا دیتا ہے۔ (یہ روح میں) ایسی رِقت پیدا کر دیتا ہے جو عاشق کو دنیوی آلودگیوں سے بیزار کردیتی ہے۔
محبت مشابہت اور ہمرنگی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی طاقت چاہنے والے کے اپنے محبوب کے ہمرنگ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ محبت ایک ایسے برقی تار کی مانند ہے جو محبوب کے وجود سے چاہنے والے کو متصل کر دیتا ہے اور محبوب کی صفات کو اس میں منتقل کر دیتا ہے اور یہی مقام ہے جہاں محبوب کا انتخاب بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے دوست تلاش کرنے اور دوست بنانے کے موضوع میں سخت اہتمام کیا ہے اور اس ضمن میں بہت سی آیات اور روایات وارد ہوئی ہےں۔ کیونکہ دوستی ہمرنگ بنانے والی،(محبوب کو)خوبصورت جتانے والی اور (اس کے عیوب سے) غافل کر دینے والی ہوتی ہے۔ جہاں (محبت) اپنا پرتو ڈالتی ہے (عاشق) کو عیب ہنر اور خار، گل و یاسمن نظر آتا(۲) ہے۔ بعض آیات و روایات میں ناپاک اور آلودہ لوگوں کی ہم
____________________
(۱) شرح اشارات، ج ۳، ص ۳۸۳ طبع جدید
(۲) عشق کی چند خامیاں بھی ہیں۔ ان خامیوں میں سے ایک یہ ہے کہ عاشق، معشوق کے حسن میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اس کی خامیوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ حب الشئی یعمی و یصم یعنی کسی شئی کی محبت (آدمی کو) اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔و من عشق شیأا اعشی بصره و امرض قلبه ۔ (نہج البلاغہ)
یعنی جو کسی چیز سے عشق کرتا ہے تو اس کی آنکھیں ناقص ہو جاتی ہیں اور دل مریض ہوتا ہے۔
سعدی گلستان میں کہتا ہے: ''ہر شخص کو اپنی عقل کامل اور اپنا بچہ خوبصورت نظر آتا ہے۔،،اس منفی اثر سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی جو ہم نے متن میں پڑھی ہے کہ عشق کا نتیجہ ہوش و ادراک کا حساس ہوجانا ہے۔ ہوش کی حساسیت اس اعتبار سے ہے کہ (عشق)انسان کو کاہلی سے نکالتا اور ' 'امکان '' کو ''عمل '' تک پہنچاتا ہے۔ لیکن عشق کا منفی اثر یہ نہیں ہے کہ آدمی کو کاہل بناتاہے، بلکہ (یہ ہے کہ) آدمی کو غافل بنا دیتا ہے ۔ کاہلی کا مسئلہ غفلت سے الگ ہے۔ اکثر اوقات کم عقل لوگ متوازن جذبات کے نتیجے میں کم غافل ہوتے ہیں۔ عشق، فہم کو تیز تر کرتا ہے لیکن توجہ کو یک جہت اور یکسو کر دیتا ہے اور اسی لیے متن میں کہا گیا ہے کہ عشق کی خاصیت یکسو کر دینا ہے اور یہی یکسوئی اور ارتکاز ہے جس کی وجہ سے خامی پیدا ہوجاتی ہے اور دوسرے امور کی طرف توجہ میں کمی آجاتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر، عشق نہ صرف عیب کو چھپاتا ہے بلکہ عیب کو حسن کا جلوہ بھی دیتا ہے۔ کیونکہ عشق کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جہاں اس کا پرتو پڑ جائے اس جگہ کو خوبصورت بنا دے۔ حسن کے ایک ذرے کو آفتاب، بلکہ سیاہ کو سفید اور ظلمت کو نور کا جلوہ دیتا ہے اور بقول وحشی:
اگر در کاسہئِ چشمم نشینی!
اگر تم میری آنکھوں میں بیٹھ جاؤ
بجز از خوبیئ لیلیٰ نہ بینی
تو لیلیٰ کے حسن کے علاوہ اور کچھ نہ دیکھو گے
اور اس کی وجہ ظاہراً یہ ہے کہ عشق علم کی طرح نہیں ہے جو سو فیصد معلوم کے تابع ہو۔ عشق کا داخلی اور نفسیاتی پہلو اس کے خارجی اور ظاہری پہلو سے زیادہ (شدید) ہے یعنی عشق کا میزان حسن کے میزان کے تابع نہیں ہے بلکہ زیادہ تر عاشق کی استعداد اور اس کی صلاحیت کے میزان کے تابع ہے۔ در حقیقت عاشق ایسی صلاحیت اور مادے کا حامل اور راکھ کے اندر (پوشیدہ) ایسی آگ (آتش زیر خاکستر) ہے جو بہانہ اور موقعہ کی تلاش میں پھرے اور جوں ہی کوئی موقعہ ملے اور اتفاق ہاتھ آئے۔ (اگرچہ) ابھی اس اتفاق کا راز معلوم نہ ہوا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عشق کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ داخلی قوت اپنا اثر دکھانے لگتی ہے اور اپنی توانائی کے حساب سے (محبوب کے لیے) حسن بناتا (مقرر کرتا) ہے نہ کہ اس حساب سے جتنا محبوب کے اندر حُسن ہے۔ یہی بات ہے جسے ہم متن میں پڑھتے ہیں کہ عاشق کی نظر میں معشوق کا عیب، ہنر اور خار، گُل و یاسمن ہے۔
نشینی اور دوستی سے سخت منع کیا گیا ہے اور بعض آیات و روایات میں نیک دل لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی دعوت دی گئی ہے ۔ ابن عباس نے کہا کہ ہم پیغمبر اکرم (ص) کی خدمت میں حاضر تھے ۔ لوگوں نے پوچھا کہ بہترین ہمنشین کون ہے؟حضور(ص) نے فرمایا:
من ذکرکم باللّٰہ رؤیتہ، و زادکم فی علمکم منطقہ، و ذکرکم بالآخرۃ عملہ۔(۱)
وہ جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے، جس کی گفتار تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا کردار تمہیں آخرت اور قیامت کی یاد دلائے ۔
انسان، نیکو کار اور پاک طینت لوگوں کی محبت کی اکسیر کا محتاج ہے کہ محبت کرے اور پاک طینت لوگوں کی محبت اسے اپنا ہمرنگ و ہم شکل قرار دے۔
____________________
(۱)بحار الانوار جلد ۱۵، کتاب العشرہ ص ۵۱ طبع قدیم
اصلاح اخلاق اور تہذیب نفس کے لیے مختلف طریقے تجویز کئے گئے ہیں اور گوناگوں مشرب (نظریات) پیدا ہو گئے ہیں۔ جن میں سے ایک سقراطی مشرب ہے۔ اس مشرب کے مطابق انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کے لیے عقل اور تدبیر کا راستہ اختیار کرے۔ انسان پہلے پاکیزگی کے فوائد اور پراگندہ اخلاق کے نقصانات پر مکمل یقین (ایمان) پیدا کرے، اس کے بعد عقل و منطق کے سہارے ایک ایک مذموم صفت کو تلاش کرے۔ اس شخص کی طرح جو اپنی ناک کے بال ایک ایک کر کے اکھیڑتا ہے یا اس کسان کی طرح جو اپنے کھیت سے غیر ضروری گھاس ایک ایک کرکے نکالتا ہے یا اس شخص کی طرح جو اپنی گندم سے ریت اور مٹی صاف کرنا چاہتا ہے اور یوں اپنے خرمن وجود کو پاک کرے۔ اس طریقے کے مطابق آدمی کو صبر، دقت اور سوچ سمجھ کر اخلاقی برائیوں کو تدریجاً زائل کرنا چاہےے اور یوں آلودگیوں سے اپنے وجود کا سونا پاک کرنا چاہےے اور شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ عقل کے لیے اس کام سے عہدہ برآ ہونا ممکن نہیں ہے ۔
فلسفی چاہتے ہیں کہ منطق اور طریق کار ( Methodology ) کے زور سے اخلاق کی اصلاح کی جائے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں: عفت و قناعت لوگوں کے درمیان انسان کی عزت و وقار بڑھانے کا سبب ہیں اور حرص و لالچ ذلت اور پستی کا موجب ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ علم قدرت اور طاقت کا موجب ہے۔ علم ایسا ہے علم ویسا ہے..۔ خاتم ملکِ سلیمان است علم۔ علم ایک ایسا چراغ ہے انسان کی راہ میں کہ جو راہ کو چاہ (کنویں) سے روشن کر دیتا ہے اور یا وہ کہتے ہیں کہ حسد اور بدخواہی روحانی بیمایاں ہیں۔ اجتماعی نقطہئ نظر سے ان کے برے نتائج نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
شک نہیں ہے کہ یہ راستہ صحیح راستہ ہے اور یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ لیکن سوال کسی دوسرے ذریعے کے مقابلے میں اس ذریعے کی قدر و قیمت کا ہے۔ مثلاً جس طرح ایک گاڑی اچھا ذریعہ ہے لیکن اسے ہوائی جہاز کے مقابلے میں دیکھنا چاہیے کہ اس وسیلے کی قدر و قیمت کیا ہے۔
ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ رہنمائی کے نقطہئ نظر سے عقل کی قدر و قیمت کیا ہے یعنی اس نقطہئ نظر سے کہ اخلاقی مسائل کی واقعیت میں، عقلی اصطلاح میں استدلال (منطق) کس حد تک صحیح اور مطابق ہے اور یہ کہ (کس حد تک) خطا اور اشتباہ نہیں ہے۔ ہم اس قدر کہتے ہیں کہ اخلاقی اور اصلاحی فلسفے کے بے حد و بے شمار مکاتبِ فکر ہیں اور منطقی نقطہئ نگاہ سے یہ مسائل ابھی بحث اور اختلاف کی حد سے آگے نہیں بڑھے ہیں اور یہ پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ اہل عرفان کلی طور پر کہتے ہیں:
پای استدلالیان چوبین بود
پای چوبین سخت بی تمکین بود
منطقیوںکے پاؤں لکڑی کے ہیںاور لکڑی کے پاؤں سخت بے اعتبار ہوتے ہیں۔
ہماری بحث فعلاً اس پہلو سے نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ ان وسائل کے نتیجے کا وزن کیا ہے؟
اہل عرفان اور ارباب سیروسلوک عقل و منطق کی بجائے محبت و ارادت کا راستہ اختیار کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: '' ایک انسان کامل کو تلاش کرو اور اس کی محبت و عقیدت کو دل کی گہرائیوں میں بٹھا لو کہ یہ عقل و منطق کی راہ کے مقابلے میں زیادہ بے خطر ہے اور سریع تر بھی۔ '' موازنے کے مقام پر دو ذریعے قدیم دستی اور جدید مشینی اوزار کی مانند ہیں۔ دل سے اخلاقی برائیوں کو زائل کرنے میں محبت و عقیدت کی تاثیر ویسی ہے، جس طرح دھات پر کیمیائی مواد کا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک نقاش حروف کے کناروں کو تیزاب کے سہارے دور کرتا ہے۔ ناخن، چاقو کی نوک یا اس طرح کی کسی اور چیز سے نہیں۔ لیکن اخلاقی برائیوں کی اصلاح کے لیے عقل کی قوت کا اثر بالکل اس طرح ہے کہ ایک شخص فولاد کے ریزے، مٹی میں سے اپنے ہاتھوں سے الگ کرنا چاہتا ہو۔ یہ کس قدر تکلیف اور زحمت کا کام ہے؟ اگر اس کے ہاتھ میں ایک طاقتور مقناطیس ہو تو ممکن ہے کہ ایک ہی گردش میں وہ ان تمام ریزوں کو الگ کر لے۔ محبت و عقیدت کی قوت مقناطیس کی طرح تمام صفات رذیلہ کو یکجا کرکے دور پھینک دیتی ہے۔ اہل عرفان کے عقیدے میں پاک طینت اور کامل لوگوں کی محبت و عقیدت ایک خود کار آلے کی طرح خود بہ خود برائیوں کو یکجا کرتی اور پھر باہر گرا دیتی ہے۔ مجذوبیت کی حالت اگر اس مقام تک پہنچ جائے تو یہ بہترین حالت ہے اور یہی ہے جو روح کو صاف کرتی اور عظمت بخشتی ہے۔
جی ہاں! جو اس راہ پر چلے ہیں وہ محبت کی قوت سے اخلاق کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ عشق و ارادت کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تجربہ نشاندہی کرتا ہے کہ روح پر جتنا اثر نیک طینت لوگوں کی صحبت اور ان کی عقیدت و محبت سے پڑتا ہے اتنا اثر اخلاقیات کی سینکڑوں کتابیں پڑھ کر بھی نہیں ہو سکتا۔ مولوی نے محبت کے پیغام کو نالہئ نے (بانسری کی آواز) سے تعبیر کیا ہے وہ کہتا ہے:
ہمچونی زہری و تریاقی کہ دید؟
نے کی طرح کس نے زہر اور تریاق کو چکھا؟
ہمچونی دمساز و مشتاقی کہ دید؟
نے کی طرح کون دمساز اور مشتاق ہے ؟
ہرکرا جامہ ز عشقی چاک شد
شادباش ای عشق خوش سودایئ ما
او زِ حرص و عیب کلی پاک شد
ای طبیب جملہ علّتہائی ما(۱)
____________________
(۱) ترجمہ گزر چکا ہے۔ مثنوی معنوی
کبھی ہم ایسے بزرگوں کو دیکھتے ہیں جن کے عقیدت مند ان کے راستہ چلنے، لباس پہننے، رویئے اور طرز گفتگو تک میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ اختیاری تقلید نہیں بلکہ خود بخود اور فطری ہے۔ محبت و عقیدت کی قوت ہے جو عاشق کی تمام رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے اورہر لحاظ سے اسے محبوب کا ہمرنگ بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کسی مرد حق کے پیچھے پھرنااور اس سے عشق کرناچاہیے تاکہ صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کر سکے۔
گر در سرت ہوای وصال است حافظا
باید کہ خاک در گہِ اہل ہُنر شوی
حافظ اگر تجھے وصال (محبوب حقیقی) کی تمنا ہے تو کسی اہل ہنر کی درگاہ کی خاک بننا چاہیے۔
عشق سے پہلے کوئی شخص عبادت یا اچھا عمل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر بھی سستی اس کے ارکان ہمت میں راستہ پا جاتی ہے لیکن جب محبت و ارادت اس کے وجود میں آ گئی تو وہ سستی اور آرام طلبی رخصت ہو جاتی ہے اور اس کا ارادہ پختہ اور ہمت بلند ہو جاتی ہے ۔
مہرخوباں دل و دین از ہمہ بی پروا برد
رخ شطرنج نبرد آنچہ رخ زیبا برد
محبوب کی محبت نے دل اور دین سب سے بے پرواہ کر دیا۔ شطرنج نے نہیں بلکہ خوبصورت چہرہ یہ چیزیں لے اڑا۔
تومپندار کہ مجنون سرِ خود مجنون شد
از سمک تا بہ سماکش کشش لیلیٰ برد(۱)
من بہ سرچشمہئ خورشید نہ خود بردم راہ
ذرّہئ ای بودم و عشق تو مرا بالا برد
میں خود سے آسمان پہ نہیں پہنچا ہوں۔میں تو ایک ذرہ تھا لیکن تیرے عشق نے مجھے اونچا کیا۔
خم ابروی تو بود و کف مینوی توبود
کہ درین بزم بگردید و دل شیدا برد(۲)
یہ تیرے ابرو کا خم اور تیرا نرم ہاتھ ہی تو ہے جو اس محفل میں آیا اور دل لے گیا۔
____________________
(۱) ترجمہ گزر چکا ہے
(۲)علّامہ طباطبائی
تاریخ ایسے بزرگوں کا پتہ دیتی ہے کہ کامل لوگوں کے ساتھ عشق و عقیدت نے، کم از کم عقیدتمندوں کے خیال میں، ان کے جسم و جان میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ مولانا رومی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ابتداء میں وہ اس قدر پرسوز اور پرجوش نہیںتھے۔ ایک عالم تھے لیکن سرد مہری اور خاموشی کے ساتھ اپنے شہر کے ایک گوشے میں تدریس میں مشغول تھے۔ جس دن شمس تبریزی سے واسطہ پڑا اور ان کی عقیدت نے دل و جان میںجگہ بنائی،ان کو دگر گوں کر دیا۔ ان کے وجود میں ایک آگ بھڑک اٹھی، گویا ایک گولہ تھا جو بارود کے ذخیرے پر جا پڑا اور شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ خود اشعری مسلک رکھنے والے ایک شخص ہیں لیکن ان کی مثنوی بے شک دنیا کی بزرگ ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کے تمام اشعار ایک طوفان اور ایک تحریک ہیں۔ انہوں نے ''دیوان شمس '' اپنے محبوب کی یاد میں لکھا ہے۔ مثنوی میںبھی کثرت سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ مثنوی مولانا رومی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب بیان کرتے کرتے جونہی ''شمس '' کی یاد آتی ہے تو ان کی روح میں ایک سخت طوفان اٹھتا ہے اور ان کے وجود میں طوفانی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں:
این نفس جان دامنسم برتافتہ است
بوی پیراہان یوسف یافتہ است
اس جان نے میری روح کوجلا ڈالا ہے (جس طرح) اس نے پیرہن یوسف کی خوشبو پائی ہے
کز برائی حق صحبت سالہا
باز گو رمزی ازان خوش حالہا
سالہا سال کی صحبت کی خاطران خوش کن لمحات کا راز دھرا دے
تا زمین و آسمان خندان شود
عقل و روح و دیدہ صد چندان شود
تاکہ زمین اور آسمان خوش ہوجائے ۔عقل، روح اور آنکھیں سو گنا بڑھ جائیں
گفتم ای دور اوفتادہ از حبیب
ہمچو بیماری کہ دور است از طبیب
میں نے کہا اے وہ جو دوست سے دور ہے ۔اس بیمار کی طرح جو طبیب سے دور ہے۔
من چہ گویم یک رگم ہشیار نیست
شرح آن یاری کہ او را یار نیست
میں کیا کہوں میری کوئی رگ ہوش میں نہیں ہے۔ اس دوست کی باتیں جو اپنے دوست کو کھوچکا ہے۔
شرح این ہجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر
اس فراق اور اس خون جگر کی باتیں۔ اس وقت بھول جا کسی اور وقت تک۔
فتنہ و آشوب و خونریزی مجو
بیش ازین از شمس تبریزی مگو(۱)
فتنہ، مصیبت اور خونریزی مت چاہو۔ اس سے زیادہ شمس تبریزی کے بارے میں مت بولو۔
اور یہ (صورت حال)حافظ کے اس قول کا مکمل مصداق ہے:
بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنہ نبود
این ہمہ قول و غزل تعبیہ در منقارش(۲)
یہاں سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کوشش اور کشش یا فعّالیت اور انجذاب کو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، جذبے کے بغیر کوشش سے کوئی کام نہیں بنتا۔ جس طرح کوشش کے بغیر صرف کشش کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
____________________
(۱) مثنوی معنوی
(۲) ترجمہ گزر چکا ہے
تاریخ اسلام سے مثالیں
تاریخ اسلام میں رسول اکرم(ص )کی ذات کے ساتھ مسلمانوں کی شدید محبت اور شیدائی کی واضح اور بے نظیر مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر انبیاء (ع) اور فلسفیوںکے مکتب کے درمیان فرق یہی ہے کہ فلسفیوں کے شاگرد صرف متعلم ہیں اورفلسفی ایک معلم سے بڑھ کر کوئی نفوذ نہیں رکھتے۔ لیکن انبیاء (ع) کا نفوذایک محبوب کے نفوذ کی قبیل سے ہے۔ ایسا محبوب جس نے محب کی روح کی گہرائیوں تک راہ پائی اور اس پر قبضہ کر رکھاہے اور اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کی گرفت ہے۔ رسول اکرم(ص) کے عاشقوں میں سے ایک ابوذر غفاری ہےں۔ پیغمبر(ص) نے تبوک (مدینہ کے شمال میں سو فرسخ اور شام کی سرحدوں کے قریب) کی طرف کوچ کرنے کاحکم دیا۔ بعض لوگوں نے حیلہ تراشی کی اور منافقین کام خراب کرنے لگے۔ (مسلمان) فوجی ساز و سامان سے خالی اور راشن کی ایسی تنگی اور قحط کا بھی شکار ہیں کہ کبھی کئی آدمی ایک خرما پر گزارہ کرتے تھے، لیکن سب خوش اور زندہ دل ہیں۔ عشق نے انہیںطاقتور بنا رکھا اور رسول اکرم(ص) کے جذبے نے انہیں قدرت عطا کر رکھی ہے۔ ابوذر نے بھی اس لشکر کے ساتھ تبوک کی جانب کوچ کیا ہے۔ راستے میں سے تین آدمی یکے بعد دیگرے واپس چلے گئے۔ جو بھی واپس چلا جاتا، پیغمبر اکرم(ص) کو اس کی اطلاع دی جاتی اور ہر بار پیغمبر(ص) فرماتے:
اگر اس میں کوئی نیکی ہے تو خدا اسے واپس بھیجے گااور اگر ا س میں کوئی نیکی نہیںہے تواچھا ہوا چلا گیا۔
ابوذر کا کمزور اور لاغر اونٹ مزید چل نہ سکا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابوذر بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ یا رسول اللہ(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم)! ابوذر بھی چلاگیا۔آپ (ص)نے پھر وہی جملہ دہرایا:
اگر اس میں کوئی نیکی ہے تو خدا اسے واپس بھیجے گااور اگر ا س میں کوئی نیکی نہیںہے تواچھا ہوا چلا گیا۔
فوج اپنا راستہ چلتی رہی اور ابوذر پیچھے رہ گیاتھا، لیکن بغاوت نہیں بلکہ اس کا جانور چلنے سے رہ گیا۔ اس نے جتنی کوشش کی اس نے حرکت نہیں کی۔ وہ چند میل پیچھے رہ گیا ہے۔ اس نے اپنا اونٹ چھوڑ دیا، اپنا سامان کاندھے پر اٹھایا اوراس گرم ہوا میں پگھلا دینے والی ریت پر چلنا شروع کر دیا۔ پیاس ایسی تھی کہ اسے مارے ڈالتی تھی۔ اس نے ایک ٹیلے پر پہاڑ کی اوٹ میں دیکھا کہ درمیان میں بارش کاپانی جمع ہے۔ اس نے چکھا اور اسے بہت ٹھنڈا اور میٹھا پایا۔ اپنے آپ سے کہا: میں اسے اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک میرے محبوب اور اللہ کے رسول(ص) اسے نہ پی لیں۔ اس نے اپنی مشک بھرلی، اسے بھی کاندھے پر اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف دوڑا۔
لوگوں نے دور سے ایک سایہ دیکھا اور کہا: اے اللہ کے رسول(ص)! ہم ایک سائے کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری طرف آرہا ہے۔ فرمایا یقیناً ابوذر ہوگا۔ وہ اور قریب آیا۔ جی ہاں ابوذر ہی تھے۔ لیکن تھکاوٹ اور پیاس سے ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ پہنچے اور پہنچتے ہی گر پڑے۔ پیغمبر(ص) نے فرمایاا: اسے جلد پانی دو۔ اس نے ایک دھیمی آواز میں کہا: پانی میرے ساتھ ہے۔ پیغمبر (ص) نے فرمایاا: پانی ہے اور تو پیاس سے ہلاک ہونے والا ہے؟جی ہاں اے اللہ کے رسول (ص)! میں نے پانی چکھا تو مجھے شرم آئی کہ اپنے محبوب اور اللہ کے رسول (ص) سے پہلے میں اسے پی لوں !(۱) ۔ سچ ہے۔کیا دنیا کے کس مکتب میں ایسی شیفتگی،بے قراری اور قربانی ہم دیکھتے ہیں؟!
____________________
۱) بحار الانور جلد ۲۱، ص ۲۱۵۔۲۱۶ طبع جدید
دوسری مثال
ایسے بیقرار عاشقوں میں سے ایک بلال حبشی بھی ہےں۔ قریش مکہ انہیں ناقابل برداشت شکنجوں میں ڈالتے اور چلچلاتی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر انہیں ایذا پہنچاتے اور انہیں بتوں کانام لینے اور بتوں پر ایمان اور محمد (ص) سے بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے کہتے۔ مولانارومی نے مثنوی کی جلد ششم میں اس کی داستان تعذیب بیان کی ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ مولانارومی کا یہ بھی شاہکار ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر انہیں مشورہ دیتے تھے کہ اپنی عقیدت کو پوشیدہ رکھیں لیکن ان میں پوشیدہ رکھنے کی تاب نہ تھی کہ عشق سرے سے سرکش اور خونی ہوتا ہے:
تن فدائی خار می کرد آن بلال
خواجہ اش می زد برائی گوشمال
بلال اپنے جسم کو کانٹوں پر قربان کرتا تھا اس کا مالک اس کو سزاکے طور پر مارتا تھا
کہ شرا تو یاد احمد می کنی
بندہئ بد مکر دین منی
تو کیوں احمد کو یاد کرتا ہے (اور کہتا) میرا غلام ہو کر میرے دین سے انکار کرتا ہے
می زد اندر آفتابش اور بہ خار
اور ''احد،، می گفت بھرافتخار
وہ اسکو دھوپ میں کھڑا کرکے کانٹوں سے مارتا
لیکن وہ فخر کے ساتھ ''احد،، پکارتا
تاکہ صدیق آن طرف برمی گذشت!
آن ''احد،، گفتن بہ گوش اور برفت
یہاں تک کہ صدیق (حضرت ابوبکر) اس طرف گذرا اور ''احد،، کہنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی
بعد از آن خلوت بدیدش پندداد
کز جہو دان خفیہ می دار اعتقاد!
پھر تنہائی میں (صدیق نے) اس کو مشورہ دیا کہ ان یہودیوں سے اپنا ایمان پوشیدہ رکھو
عالم السّر است پنہاں دار کام
گفت کردم تو بہ پیشت ای ہمام
وہ (خدا ) رازوں کاجاننے والا ہے اپنا مقصد پوشیدہ رکھ اس نے کہا اے حضرت میںنےآپ کی نصیحت سے پہلے توبہ کی ہے
توبہ کردن زین نمط بسیار شد
عاقبت از توبہ او بیزار شد
اس طری میری توبہ بہت ہوگئی ہے اورآخرکار وہ پشیمانی سے بیزار ہوا
فاش کردا، اسپردتن را در بلا
کای محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) ای عدوّ توبہ ہا
اپنے ک فاش کردیا اورجسم کو مصیبت کےسپرد کہاے محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) اے پشیمانیوں کے دشمن
ای تن من وی رگ من پر ز تو
توبہ را گنجا کجا باشد در او
میرا یہ جسم اور اسکے ہر رگ میں تو ہی تو ہے اس میں پشیمانی کی گنجائش کہا ہے؟
توبہ رازین پس زردل بیرون کنم
ازحیات خلد توبہ چون کنم؟
میں نے پشیمانی کو اس کے بعد اپنے دل سے باہر نکال پھینکا ہے میں ابدی زندگی سے کیوں پشیمان ہو جاؤں؟
عشق قہا راست و من مقہور عشق
چون قمر روشن شدم از نور عشق
عشق قہار ہے اورمیںعشق کا مقہور میں عشق کے نور سے چاند کی طرح روشن ہوا ہوں
برگ کاہم در گفت ای تند باد
من چہ دانم تا کجا خواہم فتاد
اے ہوائے تند میں تیرے ہاتھ میں ایک تنکے کی طرح ہوں مجھے کیا خبر کہ (بالآخر) میں کہاں گر پڑوں گا
گر ہلالم ور بلا لم می دوم
مقتدی بر آفتابت می شوم
میں ہلال ہوں یا بلال تیرے آفتاب کی اقتدا میں دوڑتا ہوں
ماہ را باز فتی و زاری چہ کار
در پی خورشید پوید سایہ وار
چاند کو غم وزاری سے کیا کام (وہ تو) سایہ کی طرح سورج کی پیچھے دوڑتا ہے
عاشقان در سیل تند افتادہ اند
برقضای عشق دل بنہادہ اند
عاشق طوفانوں میں کود پڑے ہیں اور اپنے آپ کو عشق کے رحم و کرم پر چِھوڑ دیا ہے
ہمچو سنگ آسیا اندر مدار
روز و شب گردان و نالان بی قرار
وہ چکی کے پاٹ کی طرح گھومتے ہیں دن رات نالہ کرتے اور بے قرار ہیں
ایک اور مثال:
اسلامی مورخین صدر اسلام کے ایک مشہور تاریخی حادثے کو ''غزوۃ الرّجیع،، اور جس دن یہ حادثہ ہوا اس کو ''یوم الرّجیع،، کا نام دیتے ہیں وہ ایک سننے والی اور دلکش داستان ہے قبیلہئ ''عضل،، اور ''قارۃ،، جن کی ظاہراً قریش کے ساتھ رشتہ داری تھی اور مکّہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے ان کے کچھ لوگوں نے ہجرت کے تیسرے سا ل رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا! ''ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوگئے ہیں، آپ مسلمانو ںکی ایک جماعت کو ہمارے درمیان بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں دن کے معنی سمجھائیں۔ ہمیں قرآن کی تعلیم دیں اور اسلام کے اصول و قوانین ہمیں یادکرائیں۔،،
رسول اکرم نے اپنے اصحاب سے چھ اشخاص کو اس مقصد کے لیے ان کے ہمراہ بھیجا اور جماعت کی سرداری مرثد ابن ابی مرثد کو یا کسی ارو شخص کو جس کا نام عاصم بن ثابت تھا، سونپی۔ رسول خد کے بھیجے ہوئے لوگ اس گروہ کے ساتھ جو مدینہ آیا تھا، روانہ ہوگئے، یہاں تک وہ ایک مقام پر جو قبیلہئ ہذیل کی جائے سکونت تھا، پہنچے اور وہاں اتر گئے۔ رسول خد کے صحابی ہر طرف سے بے خبر آرام کر رہے تھے کہ اچانک قبیلہئ ہذیل کے ایک گروہ نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ان پر ننگی تلواروں کے ساتھ حملہ کردیا۔ معلوم ہوا کہوہ گروہجو مدینہ آیا تھا یا تو شروع سے ہی دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا یا جب وہ اس مقام پر پہچنے تو لالچ میں پڑ گئے اور اپنی بدل ڈالا۔ بہرحال یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے قبیلہ ہذیل کے ساتھ مل کر سازش کی اور ان کا مقصد ان چھ مسلمانوں کو گرفتار کرنا تھا۔ رسول کے صحابی جوں ہی معاملے سے آگاہ ہوئے تیزی سے اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکے اور اپنے دفاع کے لیے تیار ہوگئے۔ لیکن ہذیلیوں نے قسم کھائی کہ ہمارا مقصد تمہیں قتل کرنا نہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں قریش مکہ کے حوالہ کریں اور ان سے کچھ پیسے لے لیں، ہم اب بھی تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ عاصم ابن ثابت سمیت ان میں سے تین افراد نے یہ کہہ کر کہ ہم مشرک کے ساتھ معاہدے کی رسوائی قبول نہیں کریں گے۔
ان سے جنگ کی اور مارے گئے لیکن دوسرے تین افراد زید بن دئنہ ،خبیب بن عدی اور عبد اللہ ابن طارقنے کمزوری دکھائی اور ہتھیار ڈال دیئے۔ ہذیلیوں نے ان تین افراد کو مضبوط رسی سے باندھا اور مکہ کی طرف چل دیئے۔ مکہ کے نزدیک پہنچ کر عبداللہ بن طارق نے اپنے ہاتھ کی رسی سے چھڑا لیے اور تلوار کی طرف بڑھائے۔ لیکن دشمن نے موقعہ نہ دیا ارو اس کو پتھر مار کر ہلاک کردیا۔ زیداور خبیب مکہ لے جائے گئے اور ہذیل کے دو قیدیوں کے بدے میں جو اہل مکہ کے پاس تھے ان کو فروخت کردیا اور چل دیئے۔ صفوانابن امیہ قرشی نے زید کو اس شخص سے خرید لیا جس کے قبضے میں وہ تھا تاکہ بعد یا احد میں مارے جانے والے اپنے باپ کے خون کا انتقال لیتے ہوئے اسے قتل کرے۔ لوگ اس کو قتل کرنے کے لےے مکہ سے باہر لے گئے قریش کے لوگ جمع ہوگئے تاکہ ماجرا دیکھ لیں۔ زید کو لوگ قتل گاہ لے گئے۔ وہ مردانہ وار آگے بڑھا اور ذرا بھی نہ گھبرایا۔ ابو سفیان بھی تماشہ دیکھنے والوں میں شامل تھا اس نے سوچا کہ ان حالات میں زید کی زندگی کے آخری لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہےے شاید وہ اس (زید) سے کوئی اظہار ندامت و پشیمانی یا رسول اکرم کی نسبت کسی نفرت کا اظہار کراسکے۔ وہ آگے بڑھا اور زید سے کہا:
''تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تو یہ پسندنہیں کرتا کہ اس وقت تیری جگہ محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) ہوتا اور ہم اس کی گردن اڑا دیتے اور تو آرام سے اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا؟،،
زید نے کہا ''خدا کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھا رہوں۔،،
حیرت سے ابو سفیان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دوسرے قریشیوں کی طرف منہ کرکے کہا:
''خدا کی قسم میں نے کسی کے دوستوں کو اس سے اس قدر محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) کے دوست اس سے محبت کرتے ہیں۔،،
تھوڑی دیر کے بعد خبیب ابن عدی کی باری آئی اس کو بھی لوگ پھانسی دینے کے لیے مکہ سے باہر لے گئے وہاں اس نے لوگوں سے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی لوگوں نے اجازت دے دی اس نے انتہائی خصوع و خشوع کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا:
''خدا کی قسم اگر یہ تہت نہ آتی کہ تم کہو گے کہ موت سے ڈرتا ہے، تو زیادہ نماز پڑھتا۔،،
لوگوں نے خبیب کو تختہ دار کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ عین اسی لمحے خبیب بن عدی کی مکمل روحانیت میں ڈوبی ہوئی دلنواز صدا، جس نے سب کو متاثر کیا اور ایک گروہ نے تو خوف خدا سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، سنی گئی۔کہ وہ اپنے خدا سے مناجات کر رہا تھا:
اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولک فبلغه الغداة ها یصنع بنا، اللهم احصهم عدوا وا قلتهم بدرا و لا تغادر منهم احدا ۔
''خدا ہم نے تیرے رسول کی طرف سے عائد ذمہ داری پوری کردی ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج صبح انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سے اس (رسول) کو آگاہ کردے خدایا ان تمام ظالموں کو اپنی نظر میں رکھ اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کردے اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھ۔،،
____________________
۱) سیرۃ ابن ہشام جلد دوم، ص ۱۷۹۔۱۷۳
ایک مثال اور:
جیسا کہ ہم جانتے ہیں احد کے واقعات مسلمانوں کے لیے غم انگیز صورت میں انجام کو پہنچے ستر مسلمان جن میں پیغمر کے چچاجناب حمزہ بھی شامل ہیں، شہید ہوگئے۔ ابتداء میں مسلمان فتحیاب ہوئے بعد میں ایک گروہ کی بد نظمی سے، جو رسول خد کی طرف سے ایک ٹیلے کے اوپر متعین تھا، مسلمان دشمن کے شکنجوں کا نشانہ بنے۔ ایک گروہ مارا گیا اور ایک گروہ منتشر ہوگیا اور تھوڑے سے ہی لوگ رسول اکرم کے گرد باقی رہ گئے۔ آخرکار اسی چھوٹے سے گروہ نے دوبارہ فوج کو جمع کیا اور دشمن کو مزید پیش قدمی سے روکا۔ خاص طور پر یہ افواہ کہ رسول اکرم شہید کردیئے گئے، مسلمانوں کے زیادہ تر پراگندہ ہونے کا سبب بنی مگر جوں ہی انہوں نے سمجھا کہ رسول اکرم زندہ ہیں ان ک روحانی قوت لوٹ آئی۔
کچھ زخمی عاقبت سے بالکل بے خبر زمین پر پڑے تھے۔ زخمیوں میں سے ایک سعد ابن ربیع تھا جس کو بارہ گہرے زخم لگے تھے۔ اسی اثنا میں بھاگ جانے والے مسلمانوں میں سے ایک سعد کے پاس پہنچا جبکہ سعد زمین پر پڑا ہوا تھا ارو اس سے کہاکہ میں نے سنا ہے پیغمبر مارے گئے ہیں۔ سعد نے کہا کہ:
''اگر محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) مارے گئے ہیں تو محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) کا خدا تونہیں مارا گیا، محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) کا دین بھی باقی ہے تو کیوں بیکاربیٹھا اور اپنے دین کا دفاع نہیں کررہا۔،،
ادھر رسول اکرم اپنے اصحاب کو جمع کرکے ایک ایک صحابی کو پکار رہے تھے کہ یہ دیکھیں کون زندہ ہے اور کون مارا گیا ہے؟ سعد ابن ربیع کو نہ پایا پوچھا کون ہے جو جائے اور مجھِے سعد ابن ربیع کے بارے میں کوئی صحیح اطلاع پہنچائے؟ انصر میں سے ایک نے کا میں حاضرہوں۔ جب انصاری پہنچا تو سعد کی زندگی کی مختصر رمق باقی تھی انصاری نے کہا کہ اے سعد مجھے پیغمبر نے بھیجا ہے کہ میں ان کو اطلاع دوں کہ تو زندہ ہے یا مرگیا؟ سعد نے کہا پیغمبر کو میرا سلام پہنچا دو اور کہہ دو کہ سعد مرنے والوں میں ہے کیونکہ اس کی زندگی کے چند لمحات سے زیادہ باقی نہیں ہیں پیغمبر سے کہہ دو کہ سعد نے کہا ہے:
''خدا تمہیں وہ بہترین جزا دے جو ایک پیغمبر کے لیے سزاوار ہے۔،،
اس کے بعد انصاری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری طرف سے تمام برادران انصار اصحاب پیغمبر کو بھی ایک پیغام پہنچا دو۔ کہہ دو کہ سعد کہتا ہے:
''خدا کے نزریک تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا کہ تہمارے پیغمبر صلعم کو کوئی گزند پہنچے اور تمہارے جسموں میں جان باقی ہو۔،،(۱)
____________________
۱) شرح ابن ابی الحدید۔ چاپ بیروت ج سوم، ص ۵۷۴ و سیرۃ ابن ہشام جلد دوم، ص ۹۴
صدر اسلام کی تاریخ کے صفحات اس قسم کی شیفتگی ، عشق اور حسین واقعات سے پر ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں پایا جاتا جو رسول اکرم کی طرح اپنے دوستوں، ہمعصروںاور اپنے بیوی بچوں کا محبوب و مراد ہو اور اس قدر وجدان کی گہرائیوںسے اسے چاہا ہو۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں کہتا ہے:
''کوئی بھی رسول اکرم کی باتیں نہیں سنتا مگر یہ کہ ان کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی اور اس کا دل ان کی طرف مائل ہوجاتا اسی لیے قریش مسلمانوں کو مکہ میں قیام کے دور میں ''صباۃ،، (دیوانے) کہا کرتے تھے اور کہتے تھے:
نخاف ان یصبوا لو لید بن المغیرةالی دین محمد
ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ولید ابن مغیرہ محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) کے دین کو دل نہ دے بیٹھے
ولئن صبا الولید و هو ریحانة قریش لیصبون قریش باجمعها
اگر ولید جو قریش کا گل سرسبد ہے دل دے بیٹھا تو تمام قریش دل دے بیٹھیں گے۔ وہ کہا کرتے : اس کی باتوں میں جادو ہے اور شراب سے زیادہ مست کرنے والی ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کے پاس بیٹھنے سے منع کرتے تھے کہ مبادا ان کی باتیں اور ان کی پرکشش شخصیت ان کواپنی طرف جذب کرلے۔ جب بھی پیغمبر کعبہ کے گرد حجر اسماعیل میں بیٹھ کر بلند آواز میں قرآن پڑھتے یا خدا کا ذکر کرتے تو وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ سن نہ سکیں اور کہیں ان کی باتوں کے جادو میں نہ آئیں اوران کی طرف جذب نہ ہوں۔ وہ اپنے سروں کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور چہروں کو چھپا لیتے کہ کہیں ان کی پرکشش جبین ان کو اپنی گرفت میںنہ لے۔ اسی لیے اکثر لوگ ان کی باتین سنتے ہی اور ان کی جھلک دیکھتے ہی اور ان کے الفاظ کی حلاوت چکھتے ہی اسلام لے آئے۔،،(۱)
____________________
۱) شرح نہج البلاغہ جلد دوم، چاپ بیروت، ص ۲۲۰
اسلام کے تاریخی حقائق میں سے ایک جوہر، جو صاحب نظر، انسان شناس محقق، اور ماہر عمرانیات کو حیرت میں ڈالتا ہے وہ انقلاب ہے جو اسلام نے جاہل عربوں میں برپا کیا۔
معمول کے مطابق اور معمول کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ایسے معاشرے کی اصلاح کے لیے طویل عرصے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تک کہ رذائل میں پختہ پرانی نسل ختم ہو جائے اور ایک نئی نسل کی بنیاد رکھی جائے لیکن جذب و کشش کے اثر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے کہا ہے، (عشق) آگ کے شعلوں کی طرح مفاسد کی جڑوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔
رسول خد کے اکثر صحابی آنحضرت سے عشق کرتے تھے اور یہ ہوائے عشق ہی ہے کہ طویل راستے ایک مختصر عرصے میں طے کئے اور ایک تھوڑی سی مدت میں اپنے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔
پر و بال ماکمند عشق اوست موکشا نش می کشد تا کوی دوست
اس کے عشق کی کمند ہمارے پر و بال ہیں یہ ہمیں کوئے دوست کی طرف کھینچتا ہے
من چگو نہ نور دارم پیش و پس چون نباشد نور یارم پیش و پس
میں کس طرح اپنا گردو پیش روشن کرسکتا ہوں جب تک گردو پیش میرے دوست کی روشنی نہ ہو
نور او دریمن و یسر و تحت و فوق برسرو برگردنم چون تاج و طوق
اس کی روشنی ہی دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہے وہی میرے سرکا تاج اور گلے کا طوق ہے
علی علیہ سلام کی محبت قرآن و سنت میں
گذشتہ بحثوں میںمحبت کی تاثیر اور اس کی قدر و قیمت واضح ہوگئی اور ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ پاک طینت لوگوں کے ساتھ ارادت خود منزل نہیں بلکہ اصلاح اور تہذیب نفس کا ایک ذ ریعہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام اور قرآن نے ہمارے لےے کسی محبوب کا انتخاب کیا ہے یا نہیں؟
قرآن سابقہ پیغمبروں کی بات نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں (انبیائ) نے ہمیشہ یہ کہا ''ہم لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے ہمارا اجر صرف خدا پر ہے۔،، لیکن پیغمبر خاتم سے خطاب کرتا ہے:
( قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربیٰ ) (۴۲:۲۳)
''کہدو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے اقرباء سے محبت۔،،
یہ ایک سوال کا مقام ہے کہ کیوں سارے پیغمبروں نے کسی اجر کا مطالبہ نہ کیا اور نبی اکرم نے اپنی رسالت کا اجر طلب کیا اور لوگوں سے اپنے اقرباء کی محبت بطور اجر رسالت چاہی؟ قرآن خود اس سوال کا جواب دیتا ہے:
( قل ماسئلتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله ) (۳۴:۴۷)
''کہہ دو جو اجر میں نے مانگا ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، میرا اجر سوائے خدا کے کسی پر نہیں ہے۔،،
یعنی جو کچھ میں نے بہ عنوان اجر رسالت چاہا ہے اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا نہ کہ مجِھے، یہ دوستی خود تمہاری اصلاح اور تکامل کے لےے ایک کمند ہے اس کا نام ''اجر،، ہے لیکن در حقیقت ایسی بھلائی ہے جو میں تمہارے لیے تجویز کررہا ہوں۔ اس اعتبار سے کہ اہلبیت اور اقرباء پیغمبر وہ لوگ ہیں جو آلودگی کے قریب نہیں پھٹکتے اور ان کا دامن پاک و پاکیزہ ہے۔
طہارت و پاکیزگی کا خزینہ:
ان کے ساتھ عشق و محبت کا نتیجہ حق کی اطاعت اور فضائل کی پیروی کے علاوہ اور کچھ نہیں اور ان کی محبت ہی ہے ج واکسیر کی طرح ماہیت تبدیل کرتی اور کامل بناتی ہے۔ ''قُربیٰ،، سے مراد جو بھی ہو یہ بات مسلم ہے کہ علی علیہ سلام اس کا واضح ترین مصداق ہےں، فخرالدین رازی کہتا ہے:
زمخشری نے کشاف میں روایت کی ہے ''جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ قرابت دار جن کی محبت ہم پر واجب ہے، کون ہیں؟ فرمایا علی علیہ سلام و فاطمہ اور ان کے بچے۔،،
اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چار نفر ''اقربائ،، پیغمبر ہیں اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ محبت ارو ان کا احترام کیا کریں اور اس مطلب پر چند پہلوؤں سے استدلال کیا جاسکتا ہے:
۱ آیت''الا المودة فی القربیٰ،،
۲ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر فاطمہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور فرماتے تھے ''فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے وہ مجھے آزار پہنچاتا ہے جو اسے آزار پہنچائے،، اور علی علیہ سلام و حسنین کوبھی دوست رکھتے تھے، جیسا کہ اس سلسلے میں بہت سی متواتر روایات پہنچی ہیں،
پس ان کی محبت ساری امّت پر فرض(۱) ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے:
( واتبعوه لعلکم تهتدون ) ۔ (اعراف نمبر ۱۵۸)
یعنی ''پیغمبر کی پیروی کرو تاکہ تم راہ ہدایت پا جاؤ۔،،
اور پھر فرماتا ہے:
( ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة )
(سورہئ احزاب آیت نمبر ۲۱)
''تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔،،
یہ سب (آیات) دلیل ہے کہ آل محمد(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) ___ جو علی علیہ سلام و فاطمہ اور حسنین ہیں، کی محبت تمام مسلمانوں پر واجب(۲) ہے۔ علی علیہ سلام کی محبت اور دوستی کے سلسلے میں پیغمبر سے اور بھی بہت سی روایات ہم تک پہنچی ہیں:
۱ ابن اثیر نقل کرتا ہے پیغمبر نے علی علیہ سلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایاا:
''اے علی علیہ سلام خدا نے تم کو ایسی چیزوں سے زینت دی ہے کہ اس کے بندوں کے نزدیک ان سے زیادہ محبوب اور کوئی زینت نہیں ہے
____________________
۱) پیغمبر کی ان سے محبت شخصی پہلو نہیں رکھتی یعنی صرف اس لیے نہیں ہے کہ مثلاً آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد ہے اور یہ کہ ان کی جگہ اگر اور لوگ ہوتے توپیغمبر ان کو چاہتے بلکہ پیغمبر اس لیے ان کو دوست رکھتے تھے کہ وہ مثالی افراد تھے اور خدا ان کو دوست رکھتا تھا ورنہ پیغمبر کی اور بھی اولاد تھی جن سے نہ خود ان کو اس طرح کی محبت تھی اور نہ امّت پر اس طرح فرض ہے۔
۲) التفسیر الکبیر فخر الدین رازی۔ ج ۲۷، ص ۱۶۶، چاپ مصر
دنیا سے کنارہ کشی نے تجھے اتنا سکون دیا کہ نہ تو دنیا کی کسی چیز سے بہرہ مند ہوتا ہے اور نہ وہ تجھ سے، تجھے مساکین کی محبت بخشدی، وہ تیری امامت پر خوش ہیں اور تو ان کی اطاعت و پیروی پر خوشحال ہے وہ شخص جو تجھ کو دوست رکھتا ہے اور تیری دوستی میں سچا ہے اور افسوس ہے اس پر جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے اور تیرے خلاف جھوٹ بولتا ہے۔،،(۱)
۲ سیوطی روایت کرتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایاا:
''علی علیہ سلام کی دوستی ایمان ہے اور اس کی دشمنی نفاق،،(۲)
۳ ابو نعیم روایت کرتا ہے کہ پیغمبر نے انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایاا:
''کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ دکھاؤں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو میرے بعد ہر گز گمراہ نہیں ہوگے؟ انہوں نے کہا: کیو ںنہیں اے اللہ کے رسول!
فرمایا! یہ علی علیہ سلام ہیں ان سے محبت کرو جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہوئے اوراس کا احترام کرو جس طرح میرا احترام کرتے ہو کیونکہ خدا نے جبرئیل کے ذریعہ مجئے حکم دیا ہے کہ یہ بات تمہیں بتادوں۔،،(۳)
____________________
۱) ساد الغابہ، ج ۴، ص ۲۳
۲) کنز العمال جمع الجوامع سیوطی، ج ۲، ص ۱۵۶
۳) حلتہ الاولیائ، ج ۱،ص ۶۳۔ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں اور ہم نے اہلسنت کی کتابوں میں نوے سے زیادہ ایسی روایات دیکھی ہیں جن کا موضوع علی علیہ سلام کی محبت اور دوستی ہے اور کتب شیعہ میں یہی بہت زیادہ روایات آئی ہیں اور مجلسی مرحوم نے بحار الانوار ج ۳۹، چاپ جدید میں ''حبّ و بغض امیر المومنین،، کے بارے میں ایک باب رکھا ہے اور اس باب میں ۱۲۳ روایات نقل کی گئی ہیں۔
نیز اہل سنت نے پیغمبر اکرم سے کئی روایتیں نقل کی ہیں کہ ان روایتوں میں علی علیہ سلام کے چہرے کی طرف دیکھنا اور علی علیہ سلام کی فضیلت بیان کرنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔
۱ محب طبری حصرت عائشہ سے روایت کرتا ہے انہوں نے کہا:
''میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ علی علیہ سلام کی چہرے کی طرف بہت زیادہ دیکھتے میں نے کہا بابا جان! میں دیکھتی ہوں کہ آپ علی علیہ سلام کے چہرے کی طرف بہت زیادہ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کا اے میری بیٹی! میں نے پیغمبر خاد سے سنا ہے کہ فرمایاا ''علی علیہ سلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔،،(۱)
۲ ابن حجر حضرت عائشہ سے روایت کرتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایاا:
''میرا بہترین بھائی علی علیہ سلام ہے اور بہترین چچا حمزہ ہے اور علی علیہ سلام کا ذکر اور اس کی فضیلت بیان کرنا عبادت ہے۔،،(۲)
علی علیہ سلام لوگوں میں خدا و رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور لازمی طور پر بہترین محبوب ہیں۔
انس ابن مالک کہتا ہے:
ہر روز انصار کے بچوں میں سے ایک پیغمبر کے کاموں کو انجام دیا کرتا تھا، ایک روز میری باری تھی امّ ایمن نے ایک بھنا ہوا پرندہ پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اس پرندے کو میں نے خود پکڑا ہے اور آپ کی خاطرپکایا
____________________
۱) الریاص النصرۃ ج ۲، ص ۲۱۹ اور تقریبا ۲۰ روایات اسی موضوع پر ہم نے دیکھیں جو کتب اہل سنت س نقل کی گئی ہیں۔
۲) الصواعق المحرقہ ص ۷۴ اور اس موضوع پر پانچ اور روایات اہل سنت کی مختلف کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔
ہے۔ حضرت نے فرمایاا خدایا! اپنے محبوب ترین بندے کو بھیج دے کہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ مرغ کھائے۔ اسی اثناء میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا پیغمبر نے فرمایاا انس دروازہ کھول! میں نے اپنے دل میں کہا خدا کرے یہ کوئی انصاری ہو لیکن میں نے دروازے کے پیچھے علی علیہ سلام کو دیکھا، میں نے کہا کہ پیغمبر ایک کام میں مشغول ہیں اور واپس آکر اپنی جگہ کھڑا ہوگیا۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا پیغمبر نے فرمایاا دورازہ کھول دو۔ میں پھر دعا کرتا تھا کہ کوئی انصاری ہو۔ میں نے دورازہ کھولا دوبارہ علی علیہ سلام تھے۔ میں یہ کہہ کر کہ پیغمبر کام میں مشغول ہیں واپس آگیا اور اپنی جگہ کھڑا ہوگیا۔ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا پیغمبر نے فرمایاا: جاؤ او ردروازہ کھول دو اور اس کو گھر میں لے آؤ تو پہلا شخص نہیں ہے جو اپنی قوم سے محبت کرتا ہے وہ انصاری نہیں ہے۔ میں گیا اور علی علیہ سلام کو گھر لے آیا اور انہوں نے پیغمبر کے ساتھ بھنا ہوا پرندہ کھالیا۔ میں گیا۔ (مستدرک الصحیحین ج ۳، ص ۱۳۱۔ یہ واقعہ مختلف انداز میں اٹھارہ سے زیادہ طریقوں سے اہلسنت کی معتبر کتابوں میں نقل کیا گیا ہے)
جاذبہئ علی علیہ سلام کا راز
دلوں میں علی علیہ سلام کی دوستی اور محبت کی رمز کیا ہے؟ محبت کا راز آج تک کوئی کشف نہیں کرسکا ہے یعنی اس کا کوئی فارمولا نہیںبنایا گیا اور کہا جاسکتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا اور ایسا ہوا تو ایسا، لیکن ایک راز ہے ضرور۔ مےحبوب میں ایسی کوئی چیز ضرور ہے جس کا حسن چاہنے والے کی نظر کو خیرہ کردیتا ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے جاذبہ ارو محبت کو بلند سطح پر عشق کہا جاتا ہے علی علیہ سلام دلوں کے محبوب اور انسانوں کے معشوق ہیں۔ کیوں؟ کس لحاظ سے؟ علی علیہ سلام میں کونسی غیرمعمولی چیز ہے کہ عشق کے جذبات کو ابھارتی اور دلوں کو اپنا شیدا بناتی ہے۔ علی علیہ سلام کیونکر ابدی زندگی کا انداز لیے ہوئے ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں؟ دل کیوں علی علیہ سلام کی طرف کھینچتے ہیں اور ان کو اصلاً مردہ نہیں محسوس کرتے بلکہ زندہ پاتے ہیں؟
یہ بات مسلم ہے کہ ان کی محبت کا اثاثہ ان کا جسم نہیں ہے کیوں کہ ان کا جسم اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے ار ہم ان کو محسوس نہیں کرتے اور پھر علی علیہ سلام کی محبت ہیرو پرستی کی قسم سے نہیں ہے جو ہر قوم میں موجود ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ علی علیہ سلام کی محبت اخلاقی اور انسانی خوبیوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے اور علی علیہ سلام سے محبت انسانیت سے محبت ہے۔
یہ درست ہے کہ علی علیہ سلام انسان کامل کا مظہر ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ انسان انسانیت کی اعلیٰ مثالوں کو دوست رکھتاہے لیکن اگر علی علیہ سلام ان تمام انسانی فضائل کے حامل ہوتے جوکہ وہ تھے وہ حکمت، وہ علم، وہ فدا کاریاں، وہ ایثار، وہ تواضع و انکساری، وہ ادب، وہ ادب، وہ لطف و محبت، وہ ضعیف پروری، وہ عدالت، وہ حریت پسندی، وہ احترام انسانیت، وہ شجاعت، وہ مروت و مرادنگی جو دشمن کی نسبت تھی اور بقول مولوی:
در شجاعت شیرِ ربّا نسیتی
در مروت خود کہ داند کیستی؟
تم شجاعت میں شیر خدا ہو
لیکن نہ معلوم مروت میں کیا ہو؟
وہ سخاوت اور جود و کرم ۔۔۔ اگر علی علیہ سلام یہ تمام (صفات) رکھتے جیسا کہ رکھنے تھے اور رنگ الہی نہ رکھتے، تو مسلماً اس قدر مہر و محبت پیدا کرنے والے نہ ہوتے جیسے کہ آج ہیں۔ علی علیہ سلام اس اعتبار سے محبوب ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دل غیر شعوری طور پر پوری گہرائی کے ساتھ حق کے ساتھ پیوستہ ہیں اور چونکہ علی علیہ سلام کو حق کی عظیم نشانی اور صفات حق کا مظہر سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ عشق کرتے ہیں۔ در حقیقت عشق علی علیہ سلام کے پیچھے حق کے ساتھ روح کا وہ رشتہ ہے جو ہمیشہ فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اور چونکہ فطرت جاودانی ہے، علیج کی محبت بھی جاوداں ہےٍ۔
علی علیہ سلام کے وجود میں روشن پہلو بہت زیادہ ہیں لیکن جس چیز نے علی علیہ سلام کو ہمیشہ درخشندہ اور تاباں قرار دے رکھا ہے وہ ان کا ایمان اور اخلاص ہے اور یہی ہے جس نے ان کو جذبہئ الہیٰ دے دیا ہے۔
علی علیہ سلام کی فداکار اور دلدادہ خاتون سودئ ہمدانی نے معاویہ کے سامنے علی علیہ سلام پر درود بھیجا اور ان کی شان میں کہا:
صلے الالہ علی روح تضمنہا
قبرفا صبح فیہ العدل مدفونا
قد حالف الحق لا یبغی بہ بدلا
فصار بالحق و الایمان مقرونا
''اس وجود پر خدا کی رحمت ہو جس کو مٹی نے لے لیا اور اس کے ساتھ عدل بھی دفن ہوگیا اس نے حق کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس کا کوئی نعم البدل نہ ہو پس حق اور ایمان کے قریب ہوا۔،،
''صعصعہ بن صوحان عبدی،، بھی علی علیہ سلام کے عاشقوں میں سے ایک تھا وہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اس رات علی علیہ سلام کی تدفین میں شرکت کی تھی۔ حضرت کو دفن کرنے اوران کے جسم مبارک کو خاک کے اندر چھپانے کے بعد صعصعہ نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سینے پر مارا اور دوسرے ہاتھ سے سر میں مٹی ڈالتے ہوئے کہا:
''تجھے موت مبارک ہو! تیری جائے پیدائش پاک تھی۔ تیرا صبر طاقتور اور تیراجہاد عظیم۔ تو نے اپنی فکر پر غلبہ پالیا اور تیری تجارت منافع بخش رہی۔،،
تو اپنے پیدا کرنے والے کا مہمان ہوا اور اس نے تجِھے خوشی سے قبول کیا اور اس کے فرشتے تیرے گرد جمع ہوگئے۔ پیغمبر کی ہمسائیگی میں جاگزیں ہوا اور خدا نے تجھے اپنے قریب جگہ دی اور تو اپنے بھائی مصطفیٰ کے درجہ کو جا پہنچا اور اس نے جام لبریز سے تجھے سیراب کیا۔
ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری پیروی کریں اور تیری روش پر عمل کریں تیرے دوستوں کو دوست اور تیرے دشمنوں کو دشمن رکھیں اور تیرے دوستوں کے ساتھ محشور ہوں۔
تو نےوہ پالیا جو دوسرے نہ پاسکے اور وہاں پہنچا جہاں دوسرے نہ پہنچ سکے تو نے اپنے بھائی کے سامنے جہاد کیا اور دین حدا کے لیے شایان طریقے سے قیام کیا یہاں تک کہ تو نے سنتوں کو برپا کیا اور خرابیوں کی اصلاح کی اور ایمان و اسلام منظم ہوگیا تجھ پر بہترین رحمتیں ہوں۔
تیرے وسیلے سے مؤمنوں کی پیٹھ مضبوط ہوئی اور راہیں روشن ہوگئیں اور سنتیں قائم ہوگئیں کسی نے بھی اپنے اندر تیری رفعتوں اور فضیلتوں کو جمع نہ کیا۔ تونے پیغمبر کی نداپر لبیک کہی اور ایسا کرنے میں اوروں پر سبقت حاصل کی تو اس کی مدد کےلئے لپکا اور اپنی جان سے اس کی حفاظت کی۔ خوف و خطر کے موقعوں پر اپنی شمشیر ذوالفقار کے ساتھ تو نے حملے کئے اور ظالموں کی کمر توڑ دی۔ کفر اور شرک کی بنیادوں کو مسمار کردیا اور گمراہوں کو خاک و خون میں لٹا دیا پس مبارک ہو اے مؤمنوں کے سردار۔
تو سب لوگوں سے زیادہ پیغمبر کے قریب تھا، تو ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا، تو یقین سے سرشار، دل محکم اور سب سے زیادہ فدا کاری کرنے والا تیرا حصہ نیکی میں سب سے زیادہ تھا، خدا ہمیں تیری مصیبت کے اجر سے محروم نہ کرے اور تیرے بعد ہمیں رسوا نہ کرے۔
''خدا کی قسم تیری زندگی نیکیوں کی کنجی تھی اور شر کے یے قفل اور تیری موت ہر شر کے لےے کنجی اور ہر خیر کے لیے قفل ہے۔ اگر لوگ تجھے قبول کر بیٹھے ہوتے تو زمین اور آسمان سے ان پر نعمتوںکی بارش ہوتی لیکن انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو منتخب کیا۔،،(۱)
جی ہاں! لوگوں نے دنیا کو منتخب کیا اور وہ علی علیہ سلام کے عدل اور عز م کی تاب نہ لا سکے اور آخر کار ایسے ہی لوگوں کی آستین سے جمود اور عصبیت کے ہاتھ باہر نکل آئے اور علی علیہ سلام کو شہید کردیا۔
علی علیہ السّلام دوست اور چاہنے والے ایسے دیوانوں کے سلسلے میں جنہوں نے ان کی محبت کی راہ میں سردیا ہے اور جو سولی پر لٹکائے گئے، اپنا کوئی نظیر نہیں رکھتے تاریخ اسلام کے صفحات کو ان شگفتہ، خوبصورت اور حیرت انگیز کارناموں پر فخر ہے زیاد ابن ربیہ اس کا بیٹا عبداللہ، حجاج ابن یوسف متوکل عباسی اور ان سب سے بڑھ کر معاویہ ابن ابی سفیان جیسے لوگوں کے مجرم اور ناپاک ہاتھ کہنیوں تک انسانیت کے ان سپوتوں کے خون سے آلود ہیں۔
____________________
۱) بحار الانوار جلد ۴۲، ص ۲۹۵۔۲۹۶ چاپ جدید
دافعہئ علی علیہ سلام کی قُوّت
علی علیہ سلام کی دشمن سازی
ہم اپنی بحث کو ان کے چار سال اور چند ماہ کی دور خلافت تک محدود رکھیں گے علی علیہ سلام ہمیشہ سے دوہری شخصیت رکھتے تھے، علی علیہ سلام ہمیشہ جاذبہ بھی رکھتے تھے اور دافعہ بھی خاص طور پر عصر اسلام کی ابتداء سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ علی علیہ سلام کے گرد گھومتا ہے اور دوسرا ان سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتا اور غالباً ان کے وجود سے ہی ناخوش ہے۔
لیکن خلافت علی علیہ سلام اور ان کی وفات کے بعد کے ادوار یعنی علی علیہ سلام کے ظہور تاریخی کا دور، ان کے جاذبہ و دافعہ کے بیشتر ظہور کا دور ہے۔ خلافت سے قبل معاشرے سے ان کا رابطہ جتنا کم تھا اسی نسبت سے ان کے جاذبہ و دافعہ کا ظہور بھی کم تر تھا۔
علی علیہ سلام لوگوں کو اپنا دشمن بنانے اور ان کو ناراض کرنے والے شخص تھے اور یہ ان کا دوسرا بڑا افتخار ہے۔ ہر مسلک اور ہدف رکھنے والا مجاہد انسان خاص کر انقلابی جو اپنے مقدس مقاصد کو عملی شکل دینے کی کوشش کرتا ہو اور جو خدا کے اس قول کا مصداق ہو کہ:
( یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومة لائم ) ( مائدہ آیت نمبر۵۴)
''وہ خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔،،
وہ لوگوں کو اپنا دشمن بنانے اور ان کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا ان کے دشمن خاص کر ان کے اپنے زمانے میں اگر ان کے دوستوں سے زیادہ نہیں تھے تو کم بھی نہ تھے اور نہیں ہیں۔ اگر آج علی علیہ سلام کی شخصیت میں تحریف نہ کی جاے اور جس طرح وہ ہے اسی طرح پیش کی جائے تو ان کی دوستی کے بہت سے دعویدار ان کے دشمنوں کے مترادف قرار پائیں گے۔
پیغمبر نے علی علیہ سلام کو ایک لشکر کا سپہ سالار بناکر یمن کی طرف بھیجا۔ واپسی میں انہوں نے پیغمبر سے ملاقات کے لےے مکّہ کاعزم کیا۔ مکّہ کے قریب پہنچ کر سپاہیوں میں سے کسی کو اپنی جگہ مقرر کرکے وہ پہلے ہی سفر کی روداد سنانے کے لیے رسول اللہ(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) کی طرف چل دیئے۔ اس شخص نے وہ تمام کپڑے جو علی علیہ سلام اپنے ہمراہ لائے تھے۔ سپاہیوں میں تقسیم کردیئے تاکہ وہ نئے کپڑے پہن کر وارد مکہ ہو جائیں علی علیہ سلام جب واپس آئے تو اس عمل پر اعتراض کیا اور اس کو نظم و ضبط کے خلاف ہوجاتا کیونکہ پیغمبر سے حکم حاصل کئے بغیر ان کپڑوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور در حقیقت علی علیہ سلام کی نظر میں یہ مسلمانوں کے پیشوا کی اطلاع اور اجازت کے بغیر بیت المال میں تصرف تھا اسی لیے علی علیہ سلام نے حکم دیا کہ وہ لوگ کپڑوں کو ا پنے جسم سے اتار دیں اور ان کو مخصوص جگہ پر رکھا تاکہ پیغمبر کی تحویل میں دے دیا جائے اور آنحضرت خود ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ علی علیہ سلام کے لشکری اس عمل سے ناخوش ہوئے جوں ہی وہ پیغمبر اکرم کے حضور پہنچے اور پیغمبر اکرم نے ان کا حال پوچھا تو کپڑوں کے سلسلے میں علی علیہ سلام کی سخت گیری کی شکایت کی۔ پیغمبر نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
یٰایها الناس لا تشکو علیّاً فو اللهانه کا خشن فی ذات الله من ان یشکی (۱)
''اے لوگو! علی علیہ سلام کی شکایت نہ کرو خدا کی قسم وہ خدا کی راہ میں اس سے زیادہ سخت ہیں کہ کوئی اس کے خلاف شکایت کرے۔،،
____________________
۱) سیرۃ ابن ہشام ج ۴، ص ۲۵۰
خدا کی راہ میں علی علیہ سلام کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے بلکہ اگر کسی پر مہربانی کرتے اور کسی کا لحاظ کرتے تو وہ خدا کے لیے ہوتا۔ یہ صورت حال یقیناً لوگوں کو اپنا دشمن بنانے والی ہے اورلالچ اور آرزو سے پردلوں کو رنجیدہ کرنے اور تکلیف پہنچانے والی ہے۔
پیغمبر کے اصحاب میں کوئی شخص علی علیہ سلام کی طرح فداکار دوست نہیں رکھتا جس طرح ان کی مانند کوئی شخص ایسے گستاخ اور خطرناک دشمن نہیں رکھتا۔ وہ ایسے شخص تھے کہ جس کی موت کے بعد اس کا جنازہ بھی دشمنوں کے حملے کا نشانہ بنا۔ وہ حود اس معاملے سے آگاہ تھے اور اس کی پیش بینی کیا کرتے تھے اسی لیے انہوں نے وصیت کی کہ ان کی قبر مخفی رکھی جائے اور ان کے فرزندوں کے علاوہ کوئی اسےنہ جانتا ہو، یہاں تک کہ تقریباً ایک صدی گزرگئی اور اموی سلطنت ختم ہوگئی، خوارج بھی ختم یا سخت کمزور ہوگئے، کینے اور کینہ توزیاں کم ہوگئیں اور امام جعفر صادق کے ہاتھوں ان کا مزار مقدّس کو ظاہر کیا گیا۔
ناکثین و قاسطین و مارقین
علی علیہ السّلام نے اپنی خلافت کے دوران تین گروہوں کواپنے سے دور پھینکا اور ان کے ساتھ برسرپیکار رہے۔ اصحاب جمل جن کو آپ نے ناکثین کانام دیا۔ اصحاب صفیّن جن کو قاسطین کہا اوراصحاب نہروان یعنی خوراج جن کو آپ نے مارقین کے نام سے پکارا:(۱)
''فلما نھضت بالامر نکثت طائفۃ و مرقت احری وقسط آخرون،، (نہج البلاغہ، خطبہ شقشقیہ)
''پس جب میں نے امر خلافت کا فیصلہ کیا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی، ایک گروہ دین سے نکل گیا ایک گروہ نے سرکشی اور بغاوت کر ڈالی۔،،
ناکثین ذہنی طور پر زبردست لوگ تھے جو لالچی اور طبقاتی نظام کے طرفدار
____________________
۱) اور آپ سے پہلے پیغمبر نے ان کو انہیں ناموں سے پکارا کہ ان سے فرمایا ستقاتل بعدی الناکثین والقاسطین و المارقین،، یعنی میرے بعد (اے علی علیہ سلام) ناکثین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ کروگے۔ اس روایت کو ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ ج ۱، ص ۲۰۱۔ میں نقل کرتا ہے او رکہتا ہے کہ یہ روایت حضرت ختمی مرتبت کی نبوت کے دلائل میں سے ایک ہے کیونکہ یہ مستقبل اور غیب کے بارے میں ایسی صریح خبر ہے جس میں کوئی تاویل یا اجمال کی گنجائش نہیں ہے۔
تھے عدالت و مساوات کے بارے میں ان کی بیشتر گفتگو انہی لوگوں کے بارے میں ہے۔
لیکن قاسطین کی ذہنیت و سیاست، دورنگی اور منافقت تھی۔ وہ زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے علی علیہ سلام کی حکومت اوران کے اختیارات کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں سے بعض نے تجویز پیش کی ان کے قریب آجائیں اور کسی حد تک ان کے مفادات کی ضمانت دیں لیکن انہوں (علی علیہ سلام) اس لیے آئے تھے کہ ظلم کا مقابلہ کیا جائے نہ اس لیے کہ ظلم کی تائید کریں اور دوسری جانب معاویہ اور اسی قماش کے لوگ سرے سے علی علیہ سلام کی حکومت کے ہی مخالف تھے وہ چاہتے تھے کہ خلافت اسلامی کی مسند پر خود قبضہ کریں اور ان کے ساتھ علی علیہ سلام کی جنگ درحقیت نفاق اور دورنگی سے جنگ تھی۔
تیسرا گروہ جو مارقین کا ہے ان کی ذہنیت ناروا عصبیت، خشک تقدس اور خطرناک جہالت تھی۔ علی علیہ سلام ان تمام کی نسبت ایک طاقتور دافعہ اور غیر مصالحانہ رویّہ رکھتے تھے۔
علی علیہ سلام کی ہمہ گیری اور ان انسان کامل ہونے کا ایک مظہر یہ ہے کہ اپنے اختیار و عمل کی بناء پر ان کو گونا گوں فرقوں اور مختلف انحرافات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ان سب سے جنگ کی۔ ہم کبھی ان کو زر پرستوں اور شتر سوار دنیا پرستوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کبھی رو و صد روسیاست پیشہ لوگوں کے ساتھ اورکبھی جاہل اور منحرف مقدس نما لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
ہم اپنی بحث کو آخری گروہ یعنی خوارج کی طرف منعطف کریں گے۔ یہ اگرچہ اب ختم ہوچکے ہیں لیکن یہ ایک سبق آموز اور عبرت انگیز تاریخ رکھتے ہیں ان کے خیالات تمام مسلمانوں میں پھیل چکے ہیں۔ جس کے نتیجے میں چودہ سو سال کی طویل تاریخ میں اگرچہ وہ لوگ اور حتیّٰ کہ ان کے نام بھی ختم ہوچکے ہیں لیکن ان کی روح ''مقدس نما،، لوگوں کی شکل میں ہمیشہ باقی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے۔
خوارج کا ظہور
خوارج یعنی شورشی، یہ لفظ ''خروج،،(۱) سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں سرکشی اور بغاوت۔ ان کاظہور ''حکمیت،، کے معاملے سے ہوا ہے۔ جنگ صفین میں آخری روز جبکہ
____________________
۱) کلمہئ ''خروج،، اگر متعدّی بہ ''علیٰ،، ہو تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ایک جنگ اور لڑائی سے نکل آنا اور دوسرے سرکشی، نافرمانی اور شورش۔خرج فلان علیٰ فلان: برز لقتاله، و خرجت الرعیة علی الملک : تمردت (المنجد) لفظ ''خوارج،، جس کے لےے فارسی میں ''شورشیاں،، کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ ''خروج،، سے دوسرے معنی میں لیا گیا ہے۔ اس گروہ کو خوارج اس لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے علی علیہ سلام کے حکم سے سرتابی کی اور ان کے خلاف شورش برپا کی اور چونکہ اپنی سرکشی کی بنیاد ایک عقیدہ اور مسلک پر رکھی لہذا اسی طرح نامزد ہوگئے اور یہ نام ان کے لیے مختص ہوگیا۔ اسی لیے وہ تمام لوگ جنہوں نے قیام کیا اور حاکم وقت سے بغاوت کی خارجی نہیں کہلائے۔ اگر یہ کوئی مذہب عقیدہ نہ رکھتے تو بعد کے بغاوت کرنے والوں کی طرح ہوتے لیکن یہ کچھ عقائد رکھتے تھے جن کو بعد میں مستقل حیثیت مل گئی۔ اگرچہ یہ کسی وقت بھی کوئی حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے لیکن اپنے لیے ایک فقہ اور ادب تخلیق کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ (صخی الاسلام ج ۳، ص ۲۷۰،۲۴۷ طبع ششم کی طرف رجوع کیاجائے)
یہ ایسے لوگ بھی تھے جن کو خروج کرنے کا موقعہ کبھی نہ ملا لیکن وہ خوارج کے عقیدہ پرایمان رکھتے تھے جیسا کہ عمرو بن عبید اور بعض اور معتزلیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ معتزلہ کے کچھ لوگ امر بالمعروف نہی از منکر اور یا گناہ کبیرہ کا اتکاب کرنے والے کے لیے عذاب مخلّد (ہمیشہ کا عذاب) کے مسئلہ میں خوارج کے ہم فکر تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ''و کا یری برأی الخوارج ،، یعنی ''خوارج کی طرح سوچتے ہیں۔،، حتی کہ چند عورتیں بھی تھیں۔ کامل مبّرد ج ۲، ص ۵۴ میں ایک ایسی عورت کی داستان نقل کی گئی ہے جس کا عقیدہ خارجیوں کا سا تھا۔ اس اعتبار سے اس لفظ کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں ''عام خاص من وجہ،، کی نبست ہے۔
جنگ علی علیہ سلام کی فتح کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی، معاویہ نے عمر وابن عاص کے مشورے سے ایک ماہرانہ چا چلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی تمام کوششیں اور زحمتیں بے کار گئیں اور یہ کہ شکست اور اس کے درمیان ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں رہا اس نے سوچا کہ فریب کے علاوہ نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس نے حکم دیا کہ لوگ نیزوں پر قرآن کو بلند کریں اور کہیں کہ لوگو! ہم قبلہئ و قرآن کو ماننے واے ہیں آؤ ہم اس کو اپنے درمیان حکم قرار دیتے ہیں۔ یہ کوئی نئی باتنہ تھی جو انہوں نے نکالی ہو، یہی بات اس سے پہلے علی علیہ سلام نے کہی تھی اور جس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اور اب بھی وہ اس کو (دل سے) تسلیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک بہانہ تھی کہ نجات کا راستہ اور یقینی شکست سے چھٹکارا پائیں۔ علی علیہ سلام نے پکارا، مارو ان کو، یہ قرآن کے صفحہ اور کاغذ کو بہانہ بنا کر قرآن کے لفظ اور کتابت کی پنا میں اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں قرآن کے خلاف اپنی روش پر باقی رہےں گے۔ قرآن کا کاغذ اور اس کی جلد کی حقیقت قرآن کے مقابلے میں کوئی قیمت و عزت نہیں رکھتی۔ قرآن حقیقت اور اس کا صحیح جلوہ ''میں،، ہوں۔ انہوں نے کاغذ اور خط کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے تاکہ حقیقت اور معنی کو نابود کریں۔
بعض جاہل اوربے معرفت مقدس نما لوتوں نے جن کی ایک بڑی تعداد تھی، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ علی علیہ سلام کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے شور مچایا کہ ہم قرآن کے ساتھ جنگ کریں؟ ہماری جنگ تو قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے ہے جب وہ بھی قرآن کو تسلیم کررہے ہیں تو پھر جنگ کس لیے؟ علی علیہ سلام نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں کہ تم قرآن کی خاطر جنگ کرو۔ ان لوگوں کو قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے قرآن کے الفاظ اور اس کی تحریر کو اپنی جان بچانے کا وسیلہ قرار دے رکھا ہے۔
اسلامی فقہ میں ''جہاد،، کے بار میں ''کفّار کا مسلمانوں کو ڈھال بنانا،، کے عنوان سے ایک مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر دشمنان اسلام مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں چند مسلمان قیدیوں کو اگلے محاذ پر اپنے لیے ڈھال قرار دیں اور خود محاذ کے پیچھے کارروائی اور پیش قدمی میں مشغول ہوں اور صورت حال ایسی ہو کہ اسلامی فوج کے لیے اپنا دفاع کرنے یا ان پرحملہ کرکے ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو کہ ان مسلمان بھائیوں کو جو ڈھال بنا دیئے گئے ہیں حکم ضررت کے تحت ختم کردیا جائے، یعنی حملہ آور دشمن پر قابو پانا مسلمانوں کوقتل کئے بغیر ممکن نہ ہو تو یہاں اسلام کے بلند مقاصد اور باقی مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے مسلمان کا قتل، اسلامی قانون کے تحت جائز قرار دیا گیا ہے۔ وہ بھی اسلام کے سپیاہی ہیں اور راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں۔ منتہا یہ ہے کہ ان کے پسماندگان کو مسلمانوں کے سرمایہ (بیت المال) سے ان کا خون بہا ادا کردیا جائے(۱) اور یہ صرف فقہ اسلامی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے فوجی اور جنگی قوانین
____________________
۱) لمعہ ج ۱، کتاب الجہاد فصل اول۔ و شرائع الاسلام کتاب الجہاد
میں ایک مسلم قانون ہے کہ اگر دشمن داخلی قوتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے، تو ان قوتوں کو ختم کرتے ہیں تاکہ دشمن پر قابو پاسکیں اور اس کو پسپا کردیں۔
ایسی صورت میں جبکہ ایک زندہ مسلمان کے بارے میں اسلام کتا ہے کہ اس کو قتل کردو تاکہ اسلام کو فتح ملے تو کاغذ اور جلد کے بارے میں تو بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کاغذ اور تحریر کا احترام معنی اور مضمون کی وجہ سے ہوتا ہے، آج جنگ قرآن کے مضمون کی خاطر ہے انہوں نے کاغذ کو وسیلہ قرار دے دیا ہے تاکہ قرآن کے معنی اور مضمون کو مٹا دیں۔
لیکن نادانی اور جہالت نے سیاہ پردے کی طرح ان کی عقل کی آنکھوں پر قبضہ کر لیا اور ان کوحقیقت سے دور رکھنا۔ کہنے لگے کہ ہم نہ صرف یہ کہ قرآن کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے بلکہ چونکہ قرآن کے ساتھ جنگ خود ایک منکر (برائی) ہے اس لیے اس سے نہی (روکنے) کی بھی کوشش کریں گے اور جو لوگ قرآن کے ساتھ جنگ کریں ان کے استھ جنگ کریں گے۔ آخری فتح میں لمحے سے زیادہ کی دیر نہ تھی کہ مالک اشتر جو ایک منجھا ہوا فدا کار اور اپنا سب کچھ قربان کردینے والا افسر تھا اسی طرح آگے بڑھتا جارہا تھا کہ تاکہ معاویہ کے خیمہ کو سرنگوں کیا جائے جہاں سے اس کی فوج کی کمان کی جارہی تھی اور اسلام کے راستے کو کانٹے سے پاک کرے اسی وقت اس گروہ نے علی علیہ سلام پر دباؤ ڈالا کہ پیچھے سے حملہ کردیں گے۔ علی علیہ سلام جتنا اصرار کرتے اتنا ہی ان کے انکار میں اضافہ ہوتا اور وہ پہلے سے زیادہ ضد کرتے۔ علی علیہ سلام نے مالک اشتر کو پیغام بھیجا کہ جنگ بند کردے اور خود میدان سے واپس آجائے۔
اس نے علی علیہ سلام کے پیغام کو جواب دیا کہ آپ مجھے چند لمحوں کی اجازت دیں تو جنت ختم ہے اور دشمن بھی نیست و نابود ہو نے والا ہے۔
انہوں (خارجیوں) نے تلواریں نکالیں اور کہا کہ یا تو ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کردیں گے یا اس سے کہہ دو کہ واپس آجائے۔
آپ نے دوبارہ اس کو پیغام بھیجا کہ اگر تم علی علیہ سلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جنگ روک دو اور واپس آجاؤ ،وہ واپس آیا اور دشمن خوش ہوگیا کہ اس کا فریب خوب کارگر ہوا۔
جنگ روک دی گئی تاکہ قرآن کو حاکم قرار دیں، ثالثی کو نسل تشکیل دیں اور دونوں طرف کے حکم قرآن و سنت میں طرفین کا جن باتوں پراتفاق ہے ان کو رو سے فیصلہ کریں اور اختلافات کو ختم کریں یا ایک اور اختلاف کا اضافہ کریں اور حالات کو بد سے بد تر بنادیں۔
علی علیہ سلام نے کہا کہ وہ اپنے حکم کی تعیین کردیں تاکہ ہم بھی اپنا حکم معین کریں، انہوں نے تجویز پیش کی کہ عبد اللہ ابن عباس جیسے سیاست دان، یا مرد فدا کار و روشن بین با ایمان مالک اشتر یا اسی قبیل کے کسی شخص کو مقرر کیا جائے لیکن ان احمقوں کو اپنے جیسے کسی کی تلاش تھی، انہوں نے ابو موسیٰ جیسے کو جو ایک ناسجھ آدمی تھا اور جس کو علی علیہ السّلام سے کوئی خاص لگاء نہ تھا، منتخب کیا۔ ہر چند کہ علی علیہ سلام اور ان کے دوستوں نے ان لوگوں کو یہ واضح کرنا چاہا کہ یہ کام ابو موسیٰ کا نہیں ہے اور وہ اس مقام کا اہل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہم کسی اور پر اتفاق نہیں کرتے۔ علی علیہ سلام نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو جو تم چاہو کرو۔
آخر کار انہوں نے اس کو علی علیہ سلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے حکم کی حیثیت سے ثالثی کونسل میں بھیجا۔ مہینوں کے مشورے کے بعد عمر و عاص نے ابو موسیٰ سے کہا کہ مسلمانوں کے مفاد میں بہتر یہی ہے کہ نہ علی علیہ سلام ہو اور نہ معاویہ اور ہم کسی تیسرے شخص کو منتخب کریں اور وہ تمہارے داماد عبد اللہ ابن عمر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوسکتا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تو علی علیہ سلام کو خلافت سے معزول کرے گا اور میں معاویہ کو، بعد میں مسلمان جاھیں گے اور ایک مناسب آدمی کو جو لازما عبد اللہ ابن عمر ہی ہے، منتخب کریں گے اور یوں فتنے کی جڑ ختم کردی جائےگی۔ اس بات پر دونوں نے اتفاق کیا اور اعلان کردیا کہ لوگ حکمیت کا نتیجہ سننے کے لیے جمع ہو جائیں۔
لوگ جمع ہوگئے، ابوموسیٰ نے عمر و عاص سے کہا کہ منبر پر جا کر اپنے فیصلے کا اعلان کرے، عمر و عاص سے کہا کہ میں؟ تم سفیر ریش اور پیغمبر کے محترم صحابی ہو میں ہر گز یہ جسارت نہیں کرسکتا کہ تم سے پہلے کوئی بات کروں۔ او موسیٰ اپنی جگہ سے اٹھا اور منبر پر جاکر بیٹھ گیا۔ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، آنکھیں خیرہ ہونے اور سانسیں سینوں میں اٹکنے لگیں۔ سب کو یہ انتظار کہ کیا نتیجہ نکلے؟ اس نے بولنا شروع کیا کہ ہم نے مشورے کے بعد امت کا مفاد اس میں دیکھا کہ نہ علی علیہ سلام ہو اور نہ معاویہ اور مسلمان خو دجانتے ہیں وہ جس کو چاہیںمنتخب کریں اور اپنی انگوٹھی کو دائیں ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا کہ میں نے علی علیہ سلام کو خلافت سے معزول کردیا جس طرح میں نے اس انگوٹھی کو ہاتھ سے نکالا۔ یہ کہا اور منبر سے اتر آیا۔
عمر و عاص اٹھا اور منبرپر بیٹھ گیا اور کہا کہ تم لوگوں نے ابو موسیٰ کی باتیں سن لیں کہ اس نے علی علیہ سلام کو خلافت سے معزول کردیا ہے میں بھی ان کو خلافت سے معزول کرتا ہوں جس طرح کہ ابو موسیٰ نے کیا ہے اور اپنی انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ سے باہر نکالا اس کے بعد اپنی انگوٹھی کو اپنے بائیں ہاتھ میں ڈالتے ہوئے کہا کہ میں معاویہ کو اس طرح خلافت پر نصب کرتا ہوں جس طرح اپنی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں ڈالا ہے۔ یہ کہا اور منبر سے نیچے اترا۔
مجلس میں کھلبلی مچ گئی لوگوں نے ابو موسیٰ پرحملہ کرنا شروع کیا اوربعض لوگ تازیانہ لے کراس کی طرف بڑھے، وہ مکہ کی طرف بھاگ گیا اور عمر و عاص بھی شام چلاگیا۔
خوارج نے جو اس معاملے کو پیدا کرنے کے ذمہ دار تھے حکمیت کی رسوائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے معاویہ اور عمر و عاص کی مکاری کو تسلیم کیا اور جنگ بند کرلی اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ حکمیت کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ''مصلح،، کے انتخاب میں ہم نے خطا کی کہ عمر و عاص کے مقابلے میں ابو موسیٰ کو مقرر کیا۔ بلکہ کہتے تھے کہ ہم نے دین خدا میں دو انسانوں کو حکم اور مصلح قرار دیا جو خلاف شرع اور کفر تھا۔ حاکم صرف خدا ہے نہ کہ انسان۔
وہ علی علیہ سلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے نہیں سمجھا ارو حکمیت کو تسلیم کیا تو بھی کافر ہوگئے اور ہم بھی، ہم نے توبہ کرلی ہے تم بھی توبہ کرلوٍ۔ مصیبت تازہ ہوگئی اوربڑھ گئی۔
علی علیہ سلام نے کہا بہرحال توبہ کرنا اچھی بات ہے''استغفر الله من کل ذنب '' ہم ہمیشہ ہر گناہ سے استغفار کرتے ہیں،،۔ انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے بلکہ تم کو اعتراف کرلینا چاہیے کہ ''حکمیت،، گناہ تھی اور اس گناہ سے توبہ کرو۔ کہا کہ آخر میں نے تحکیم کا مسئلہ پیدا کیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے اور دوسری طرف سے جو چیز شریعت میں جائز ہے میں کس طرح اس کو گناہ قرار دوں اور جس گناہ کا میں مرتکب نہیں ہوا ہوں اس کا اعتراف کرلوں۔ یہاں سے انہوں نے ایک مذہبی فرقہ کی حیثیت سے کام شروع کردیا۔ ابتداء میں ایک باغی اور سرکش گروہ تھا اسی لیے ان کا نام ''خوارج،، رکھ دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے لیے اصول عقائد منظم کرلیے اور وہ گروہ جو ابتداء میں سیاسی شکل کا تھا رفتہ رفتہ ایک مذہبی فرقہ کی صورت اور مذہبی رنگ اختیار کرگیا۔ بعد میں خوارج نے ایک مذہب کے حامیوں کی حیثیت سے تیز تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور آہستہ آہست جب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اپنے خیال میں دنیائے اسلام کے مفاسد کی نشاندہی کریں، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عثمان، علی علیہ سلام اور معاویہ سب غلطی پر اور گناہگار ہیں اور ہمیں چاہیے کہ جو مفاسد پیدا ہوگئے ہیں ان کا مقابلہ کریں اور امر بہ معروف اور نہی از منکر کریں۔ اس طرح خوارج کامذہب امر بہ معروف اور نہی از منکر کے فریضے کے عنوان سے وجود میں آیا۔
امر بہ معروف اورنہی از منکر کا فریضہ سب سے پہلے دو اساسی شرطیں رکھتا ہے: ایک دینی بصیرت اور دوسرے عمل میں بصیرت۔
دین کی بصیرت ___ جس طرح کہ روایت میں آیا ہے ___ اگر نہ ہو تو اس کام کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔
جہاں تک عمل میں بصیرت کا تعلق ہے وہ ان دو شرطوں کا لازمہ ہے جن کوفقہ میں ''احتمال تاثیر،، اور ''عدم ترتب مفسدہ،، سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کا فائدہ تب ہے جب ان دو فریضوں کے سلسلے میں عقل و منطق کو دخل ہو۔(۱) خوارج نہ بصیرت دینی رکھتے تھے اور نہ بصیرت عملی، وہ نادان اور بے بصیرت لوگ تھے۔ بلکہ
____________________
۱) یعنی امر بہ معروف اور نہی از منکر اس لیے ہے کہ ''معروف،، رائج ہوجائے اور ''منکر،، مٹ جائے۔ پس امر بہ معروف اور نہی از منکر وہاں کیا جانا چاہیے کہ جہاں اس نتیجے کے مترتب ہونے کا احتمال ہو، اگر ہمیں معلوم ہو کہ قطعا بے اثر ہے تو واجب کیونکر؟
اور دوسرے یہ کہ اس عمل کو شریعت نے اس لیے رکھا ہے کہ کوئی مصلحت انجام پائے اس لیے لازماً وہاں انجام پاناچاہیے کہ جہاں پہلے سے زیادہ خرابی پیدا نہ ہو۔ ان دو شرطوں کا لازمہ بصیرت در عمل ہے وہ شخص جس میں بصیرت در عمل مفقود ہے پیش بینی نہیں کرسکتا کہ اس کام کاکوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں اور یہ کہ کوئی پہلے سے زیادہ مفسدہ ہوگا یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جاہلانہ امر بہ معروف، جس طرح کہ حدیث میں ہے، اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔
تمام فرائض میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ احتمال ترتب فائدہ اس کی شرط ہے اوراگر فائدہ کا احتمال ہے تو انجام دیا جائے اور اگر فائدہ کااحتمال نہ ہو تو انجام دیا جائے حالانکہ ہر فریضہ میں کوئی فائدہ اور مصلحت پیش نظر ہے لیکن ان مصلحتوں کو پہچاننے کی ذمہ داری لوگوں پر نہیں ڈالی گئی ہے۔ نماز کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے کہ اگر تم دیکھو کوئی فائدے کی صورت ہے تو پڑھو ورنہ نہ پڑھو، روزہ کے سلسلے میں بھی نہیں کہا گیا کہ اگر تمہیں فائدہ کا احتمال ہو تو رکھو ورنہ نہ رکھو۔ روزہ کے سلسے میں کہا گیا ہے کہ اگر تم دیکھ کہ نقصان یا ضرر کی صورت ہے تو نہ رکھو اسی طرح جج یا زکوٰۃ یا جہاد کے بارے میں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے لیکن امر بہ معروف اور نہی از منکر کے بارے میں یہ قید ہے کہ دیکھنا چاہیے کیا اثر اور کیا رد عمل رکھتا ہے اور یہ کہ کیا عہ عمل اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں ہے یا نہیں؟ یعنی مصلحت کو پہچاننے کی ذمہ داری خود عمل کرنے والوں پر ڈالی گئی ہے۔
اس فریضے میں ہر شخص کو یہ حق ہے بلکہ واجب ہے کہ منطق اور عقل و بصیرت در عمل اور توجہ بہ فائدہ کو دخل دینے کا راستہ دے کیونکہ یہ عمل محض تعبدی نہیں ہے (گفتار ماہ جلد اول میں امربہ معروف و نہی از منکر کے موضوع پر تقریر، کی طرف رجوع کیا جائے)
یہ شرط کہ امر بہ معروف اور نہی از منکر کے سلسلے میں عملی بصیرت سے کام لینا واجب ہے، اس پر خوارج کو چھوڑ کر باقی تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے۔ وہ اسی جمود، خشکی اور مخصوص تعصب کی بناء پر جو وہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ امربہ معروف و نہی از منکر ''تعبد محض،، ہے اس میں ''احتمال اثر،، اور ''عدم ترتب مفسدہ،، کی کوئی شرط نہیں ہے اس لیے کسی کو بیٹھ کر اس کے نتائج کا حساب نہیں لگانا چاہیے ۔ اپنے اسی عقیدے کی بناء پر یہ جانتے ہوئے کہ وہ مارے جائیں گے، ان کا خون بہایا جائے گا اور یہ جانتے ہوئے کہ ان کے قیام کا کوئی مفید نتیجہ مرتب نہیں ہوگا، وہ قیام کرتے تھے اور یا دوسروں پر حملہ کرتے تھے۔
بنیادی طور پر وہ عملی بصیرت کے منکر تھے کیونکہ وہ اس فریضے کو ایک ''امر تعبدی،، جانتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ آنکھیں بند کرےے اس کو انجام دینا چاہیے۔
اصول عقائد خوارج
''خارجیت،، کی بنیاد پر چند چیزوں سے تشکیل پائی تھی:
۱ علی علیہ سلام، عثمان، معاویہ، اصحاب جمل اور اصحاب حکمیت اور ان تمام لوگوں جو حکمیت پر راضی ہوئے، کی تکفیر۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حکمیت کا مشورہ دیا اور بعد میں توبہ کرلی۔
۲ ان لوگوں کی تکفیر جو علی علیہ سلام و عثمان اور دوسرے لوگوں کے کفر کے قائل نہ ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔
۳ صرف ایمان ولی عقیدہ نہیں ہے بلکہ اوامر پر عمل اور نواہی کو ترک کرنا بھی جزو ایمان ہے۔ ایمان، اعتقاد اور عمل سے مرکب ایک امر ہے۔
۴ ایک ظالم امام اور حکمران کے خلاف غیر مشروط بغاوت کا وجوب۔
وہ کہتے تھے کہ امر بہ معروف اور نہی از منکر کے لیے کسی چیز کی شرط نہیں ہے اور ہر جگہ بغیر کسی استثناء کے اس حکم الہی کو انجام دیا جانا چاہیے۔(۱)
ان عقائد کی وجہ سے انہوں نے ایسے عالم میں سحر کی کہ روئے زمین کے تمام لوگوں کو کافر، واجب القتل اور ابدی جہنمی سمجھتے تھے۔
____________________
١(۱)ضحی الاسلام ج ٣، ص ٣٣٠ منقول از کتاب الفرق بین الفرق
خلافت کے بارے میں خوارج کا عقیدہ
خوارج کی واحد فکر جو آج کے تجدّد پسندوں کی نظر میں درخشاں ظاہر کی جاتی ہے وہ خلافت آزادانہ انتخاب کے ذریعہ ہونی چاہیے اور موزوں ترین شخص وہ ہے جو ایمان و تقویٰ کے لحاظ سے صلاحیت رکھتا ہو خواہ قریش سے ہو یا غیر قریش سے، ممتاز قبیلے سے ہو یا گمنام اور پسماندہ قبیلے سے۔ عرب ہو یا غیر عرب۔
انتخاب اور بیعت مکمل ہونے کے بعد خلیفہ اگر اسلامی معاشرے کے مفاد کے خلاف چلے تو وہ خلافت سے معرزول ہو جاتا ہے اور اگروہ (معزول ہونے سے ) انکار کر بیٹھے تو اس سے جنگ کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ مارا جائے ۔(۱)
یہ لوگ خلافت کے بارے میں شیعوں کے مخالف قرار پائے ہیں جو کہتے ہیں کہ خلافت ایک امر الہی ہے اور خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف خدا کی طرف سے معین کیا گیا ہو اور اسی طرح سنیوں کے بھی مخالف ہیں جو کہتے ہیں کہ خلافت صرف قریش کے لیے ہے اور''انما الائمة من القریش،، کے جملے سے وابستگی ڈھونڈھتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ خلافت کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ایسی چیز نہیں ہے کہ
____________________
۱) ضحی الاسلام ج ۳، ص ۳۳۲
جس تک وہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی پہنچے ہوں۔ بلکہ جیسا کہ ان کا مشہور نعرہ ''لا حکم الا للہ،، حکایت کرتا ہے اور نہج البلاغہ(۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں وہ کہتے تھے کہ افراد اور معاشرے کو کسی امام یا حکومت کی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کو خود خدا کی کتاب پر عمل کرنا چاہیے۔
لیکن بعد میں وہ اس عقیدے سے پھر گئے اور خود عبد اللہ بن وہب راسبی کی بیعت کرلی۔(۲)
خلفاء کے بارے میں خوارج کاعقیدہ
وہ ابوبکر اور عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے تھے اس اعتبار سے کہ یہ دونوں ایک صحیح انتخاب کے ذریعے خلافت تک پہنچے تھے اور مصالح کی راہ سے بھی منحرف نہیں ہوئے اور اس کے خلاف کسی چیز کے مرتکب نہیں ہوئے۔ وہ عثمان اور علی علیہ سلام کے انتخاب کو بھی صحیح جانتے تھے۔ بالآخر کہتے تھے کہ عثمان اپنی خلافت کے چھٹے سال کے آخر میں راہ سے منحرف ہوگیا ہے اور مسلمانوں کے مفادات سے آنکھیں پھیر لی ہیں اس لیے وہ خلافت سے معزول تھا اور چونکہ مسئلہ تحکیم کو قبول کیا اور اس کے بعد توبہ نہیں کی ہے وہ بھی کافر ہوگیا اور واجب القتل تھا اور اس لیے ساتویں سال کے بعد عثمان کی خلافت اورتحکیم کے بعد علی علیہ سلام کی خلافت سے تبّریٰ (بیزاری کا اظہار) کرتے(۳) تھے۔ وہ سارے خلفاء سے بیزاری کااظہار کرتے تھے اور
____________________
۱) خطبہ ۴۰ و شرح ابن ابی الحدید ج ۲، ص۳۰۸
۲) کامل ابن اثیر ج ۳، ص ۳۳۶
۳) الملل و النحل شہرستانی
ہمیشہ ان کے ساتھ برسرپیکار رہتے تھے۔
خوارج کا خاتمہ
یہ گروہ پہلی صدی ہجری کے چوتھے دہے کے اواخر میں ایک خطرناک فریب کے نتیجے میں وجود میں آیا اور ڈیڑھ صدی سے زیادہ نہ ٹھہر سکا۔ اپنے بے جا جوش اور جنون آمیز بے باکیوں کی وجہ سے وہ خلفاء کی سرزنش کا شکار بنے جنوہں نے ان کو اور ان کے مذہب کو تباہی و بربادی کی طرف دھکیلا اور عباسی سلطنت کے قیام کے اوائل میں سرے سے نابود ہوگئے۔ ان کی خشک اور بے روح منطق، ان کو وہ روش جو زندگی سے ناآہنگ تھی اور سب سے بڑھ کر ان کے بیجا جوش نے جس کی وجہ سے انہوں نے ''تقیّہ،، کے صحیح اور منطقی مفہوم تک سے کنارہ کشی اختیا رکی، ان کو نابود کردیا۔ خوارج کا مکتب کوئی ایسا مکتب نہ تھا جو واقعاً باقی رہ سکتا لیکن اس مکتب نے اپنا اثر باقی رکھا۔ خارجیت کے افکار و عقائد نے تمام اسلامی فرقوں میں نفوذ پیدا کیا اور اب بھی بہت سے ''نہروانی،، موجود ہیں اور علی علیہ سلام کے عہد و عصر کی طرح اسلام کے خطرناک ترین داخلی دشمن یہی لوگ ہیں۔ جس طرح کہ معاویہ اور عمر و عاص بھی ہر دور میں رہے ہیں اور ''نہرانیوں،، کے وجود سے جوان کے دشمن شمار ہوتے ہیں،موقعہ پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔
رُسوم یا روح
ایک مذہبی بحث کی حیثیت سے خارجیت یا خوارج کے اوپر بحث کرنا، کسی مورد کے بغیر بحث اوربے نتیجہ ہے کیونکہ آج دنیا میں ایسا کوئی مذہب وجود نہیں رکھتا لیکن اس کے ساتھ ہی خوارج اور ان کے کام کی نوعیت کے بارے میں بحث ہمارے اور ہمارے معاشرے کے لیے سبق آموز ہے کیونکہ ہر چند خوارج کا مذہب ختم ہوچکا ہے لیکن اس کی روح ابھی زندہ ہے۔ خارجیت کی روح ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پیکر میں حلول کئے ہوئے ہے۔ لازم ہے کہ مقدمے کے طور پر کچھ کہوں:
یہ ممکن ہے کہ کچھ مذاہب رسوم کے اعتبار سے مرچکے ہوں لیکن اپنی روح کے اعتباد سے زندہ ہوںجیسا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے برعکس ہو کہ کوئی مسلک رسوم کے اعتبار سے زندہ ہو لیکن روح کے اعتبار سے کلی طورپر مرچکا ہو لہذا ممکن ہے کہ کوئی فرد یا کچھ افراد رسوم کے لحاظ سے ایک مذہب کے تابع اور پیرو شمار کئے جاتے ہوں اور روح کے اعتبار سے اس مذہب کے پیرو نہ ہوں اور اس کے برعکس ممکن ہے کہ بعض روح کے اعتبار سے کسی مذہب کے پیرو ہوں حالانکہ اس مذہب کے رسوم کو انہوں نے قبول نہ کیا ہو۔
مثلاً جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد ابتداء ہی مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے:۔ سُنّی اور شیعہ۔ سُنّی ایک رسم اور عقیدے کے چوکھٹے کے اندر ہیں اور شیعہ دوسرے رسم اور عقیدے کی چار دیواری کے اندر۔
شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے خلیفہئ بلا فصل علی علیہ سلام ہیں اور آنحضرت نے علی علیہ سلام کو خدا کے حکم سے اپنی خلافت اور جانشینی کے لیے معین کیا ہے اور پیغمبر کے بعد یہ مقام ان کے لیے مخصوص ہے اور اہل سنت کہتے ہیں کہ اسلام نے اپنا قانون بناتے ہوئے خلافت و امامت کے موضوع میں کوئی مخصوص پیش بینی نہیں کی ہے بلکہ رہبر کے انتخاب کا معاملہ خود لوگوں پرچھوڑا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ قریش کے درمیان سے منتخب کیا جائے۔
شیعہ پیغمبر کے بہتسے ایسے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں جن کا شمار اکابر اور مشہور شخصیتوں میں ہوتا ہے اور سنی اس معاملے شیعوں کے بالکل مخالف ہیں وہ ہر اس شخص کے بارے میں بہت زیادہ اور عجیب خوش بینی رکھتے ہیں ،جو ''صحابی،، کہلاتا ہو۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے تمام صحابہ عادل اور صحیح کام کرنے والے ہیں۔ تشیع کی بنیاد تنقید ،تحقیق، ناخوش عقیدگی اور بال کی کھال اتارنا ہے اور تسنن کی بنیاد حمل بر صحت، توجیہ اور ''انشاء اللہ بلی ہوگی،، پر ہے۔
اس عصر اور زمانے میں جس میں ہم ہیں۔ کافی ہے کہ جو شخص کہد ے: علی علیہ سلام پیغمبر کے خلیفہئ بلا فصل ہیں ہم اس کو شیعہ سمجھیں اور اس سے کسی اور چیز کی توقع نہ رکھتے ہوں؟ وہ جسی روح اور جس نوعیت کے طرز فکر کا ہو، ہوا کرے؟
لیکن اگر ہم صدر اسلام کی طرف مڑ کر دیکھیں تو ہمیں ایک خاص قسم کا جذبہ نظر آتا ہے کہ وہ جذبہ تشیع کا جذبہ ہے اور وہی جذبات تھے جو علی علیہ سلام کے بارے میں پیغمبر کی وصیت کو سو فیصد قبول کرسکتے تھے اور کسی قسم کے شک اور تذبذب کا شکار نہ ہوتے تھے جس جذبہ اور اس طرز فکر کے مقابلے میں ایک اور جذبہ اور طرز فکرتھا کہ لوگ آنحضرت پجر مکمل ایمان رکھنے کے باوجود پیغمبر اکرم کی وصیتوں کی ایسی توجیہہ اور تفسیر اور تاویل کرتے تھے جو مطلوب نہ تھی اور درحقیقت اسلام میں انتشار یہاں سے پیدا ہوا کہ ایک گروہ جس کی یقیناً اکثریت تھی صرف ظاہر کو دیکھتا تھا اور ان کی نظر اتنی تیز اور گہری نہ تھی کہ ہر واقعہ کی حقیقت اور اس کے باطن کو بھی دیکھتی وہ ظاہر کو دیکھتا اور ہر جگہ حمل بر صحت کرتا تھا وہ لوگ کہتے کہ برزگ، بوڑھے اور اسلام میں پہل کرنے والے صحابہ ایک راہ پر چلے ہیں اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے
لیکن دوسرا گروہ جو اقلیت میں تھا وہ اسی وقت سے کہتارہا ہے کہ شخصیتیں اس وقت تک ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں جب تک وہ حقیقت کا احترام کرتی رہیں لیکن جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اصول انہی پہل کرنے والوں کے ہاتھوں پائمال ہو رہے ہیں، پھر ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ہم اصول کے طرفدار ہیں نہ کہ شخصیتوں کے۔ اس روح کے ساتھ تشیع وجود میں آیا ہے۔
ہم جب تاریخ میں سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد کندی، عمار یاسر اور اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو علی علیہ سلام کے گرد جمع ہونے اور اکثریت کو چھوڑ دینے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے جو اصولی بھی تھے اور اصول شناس بھی، دیندار بھی تھے اور دین شناس بھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنی فکر و ادراک کو دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دیناچاہیے اور یہ کہ جب وہ غلطی کریں توہم بھی غلطی کریں اور در حقیقت ان کی روح ایسی روح تھی جن پر اصول اور حقائق کی حکمرانی تھی نہ کہ اشخاص اور شخصیتوں کی!
امیر المومنین کے صحابہ میں سے ایک شخص جنگ جمل کے معاملے میں سخت تردد کاشکار تھا۔ وہ دونوں طرف دیکھتا ایک طرف علی علیہ سلام کو دیکھتا تھا اور ان برزگ مسلمان شخصیتوںکو جو علی علیہ سلام کے ہمرکاب ہو کر تلواریں کھینچے ہوئے تھیں اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کو دیکھتا کہ قرآن، آنحضرت کی بیویوں کے بارے میں کہتا ہے''و ازواجه مهاتهم،، (سورہئ احزاب آیت ۶) ''اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں،، اور عائشہ کے ہمرکاب طلحہ کو دیکھتا جو سابقین میںسے تھا ایک اچھا ماضی رکھنے والا، تیز انداز اور اسلامی جنگوں کا ماہر سپاہی، ایسا شخص جس نے اسلام کی بیش بہا خدمت کی ہے اور پھر زبیر کو دیکھتا جو طلحہ سے بھی اچھا ماضی رکھنے والا حتیٰ کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے سقیفہ کے روز علی علیہ سلام کے گھر پناہ لی تھی۔
یہ شخص عجیب حیرت میں پڑا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ آخر علی علیہ سلام و طلحہ اور زبیراسلام میں پہل کرنے والوں اور اسلام کے سخت ترین فدا کاروں میں سے ہیں، اب وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں؟! ان میں کون زیادہ حق کے قرب ہے؟ اس الجھن میں کیا کرنا چاہےے؟ یاد رکھیے! اس حیران شخص کی زیادہ ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ شاید اگر ہم بھی ان حالات سے دوچار ہوتے جن میں وہ دو چار ہوا تو زبیر اور طلحہ کی شخصیت اور خدمات ہماری آنکھوں کو خیرہ کردیتیں۔
آج جب ہم علی علیہ سلام و عمار و اویس قرنی اور دوسرے لوگوں کو ۔۔۔ زبیر و طلحہ کے بالمقابل دیکھتے ہیں تو تردد کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ ہم سمجہتے ہیں کہ دوسرے گروہ کے لوگوں کی پیشانی سے جنایت ٹپکتی ہے یعنی ان کے چہرے سے جرم اور خیانت کے آثار ظاہر ہیں اور ان کے قیافہ اور چہروں کو دیکھنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہیں لیکن اگرہم اس زمانے میں ہوتے اور ان کی خدمات کو نزدیک سے دیکھتے تو شاید تردد سے محفوظ نہ رہ سکتے۔
آج جب ہم پہلے گروہ کو برحق اور دوسرے گروہ کو باطل پر جانتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہے کہ گذشتہ تاریخ کے نتیجے میں اور حقائق کے روشن ہونے کی وجہ سے ایک طرف علی علیہ سلام اور عمار اور دوسری طرف زبیر اور طلحہ کو ہم نے پہچان لیا ہے اور ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس بارے میں صحیح فیصلہ کریں یا کم از کم اگر ہم خود تاریخ میں تحقیق اور مطالعہ کے اہل نہیں تو بچپنے سے ہمیں اسی طرح سمجھایا گیا ہے لےکن ان دنوں ان دو اسباب میں کوئی ایک بھی وجود نہیں رکھتا تھا۔
بہرحال وہ شخص امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا اور کہا:
''أیمکن ان یجتمع زبیر و طلحة و عائشة علی باطل،،
کیا ممکن ہے کہ طلحہ و زبیر اور عائشہ باطل پر اجماع کرلیں؟ ان جیسی شخصیتیں، رسول اللہ کے بزرگ صحابہ کس طرح غلطی کرسکتے اور باطل کی راہ پر چل سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟
علی علیہ سلام جواب میں ایسی بات کرتے ہیں کہ مصر کے دانشور اور ادیب ڈاکٹر طہٰ حسین کہتے ہیں: اس سے زیادہ محکم اور بالاتر بات نہیں ہوسکتی، وحی کے خاموش ہونے اور ندائے آسمانی کے منتقطع ہونے کے بعد اتنی عظیم بات نہیں سنی گئی ہے،(۱) فرمایا:
''انک لملبوس علیک، ان الحق و الباطل لا یعرفان باقدار الرجال، و اعرف الحق تعرف اهله، و اعرف الباطل تعرف اهله،،
''تمہیں دھوکہ ہوا اور حقیقت کی پہچان میں تم سے غلطی ہوئی ہے۔ ےق و بائل کو افراد کی شخصیت اور قدر قیمت کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جاسکتا۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ تم پہلے شخصیات کو پیمانہ قرار دو اور اس کے بعد حق و باطل کو ان پیمانوں سے پرکھو، فلاں چیز حق ہے کیونکہ فلاں اس کے ساتھ موافق ہےں اور فلاں چیز باطل کیونکہ فلاں فلاں
____________________
۱) علی و نبوہ ص ۴۰
اس کے مخالف ہیں۔ نہیں، اشخاص کو حق و باطل کا پیمانہ نہیں بنایا جانا چاہیے بلکہ حق و باطل کو اشخاص اور ان کی شخصیت کا پیمانہ قرار دیا جانا چاہیے۔،،
یعنی تمہیں چاہیے کہ حق شناس اور باطل شناس بنو نہ کہ اشخاص و شخصیت شناس۔ افرا د کو خواہ بڑی شخصیات ہوں یا چھوٹی شخصیات حق کے معیار پر پرکھو اگر اس کے اوپر پورا اتریں تو ان کی شخصیت کو قبول کرو ورنہ نہیںٍ۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آیا طلحہ و زبیر و عائشہ کے لیے ممکن ہے کہ باطل پر ہوں؟
یہاں علی علیہ سلام نے خود حقیقت کو حقیقت کا معیار قرار دیا ہے اور روح تشیّع بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور در حقیقت شیعہ فرقہ ایک مخصوص نظر کی پیداوار ہے جو اسلامی اصول کو اہمیت دینے سے عبارت ہے نہ کہ افراد اور اشخاص کو۔ یوں لازمی طور پر ابتداء شیعہ تنقید کرنے اور (شخصیت کے) بُت توڑنے والوں کی حیثیت سے ابھرے۔
پیغمبر کے بعد تینتیس (۳۳) سالہ جوان علی علیہ سلام کے ساتھ انگلیوں کی تعداد سے کمتر اقلیت تھی اور ان کے مقابلے میں ساٹھ سالہ بوڑھے جن کے ساتھ بہت زبردست اکثریت تھی۔ اکثریت کی منطق یہ تھی کہ بزرگوں او مشائخ کا راستہ یہ ہے اور بزرگ غلطی نہیں کرتے اور ہم ان کی راہ پر چلتے ہیں۔ اُس اقلیت کی منطق یہ تھی کہ صرف یہ حقیقت ہی ہے جو غلطی نہیں کرتی، بزرگوں کو چاہےے کہ خود کو حقیقت کے ساتھ تطبیق کریں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کتنے زیادہ ہیں جو رسوم کے اعتبار سے شیعہ ہیں لیکن ان میں شیعیت کی روح نہیں ہے۔
تشیّع کی راہ اس کی روح کی طرح حقیقت کی تشخیص اور اس کی پیروی ہے اور اس کا سب سے بڑا اثر ''جذب،، اور ''دفع،، ہیں۔ لیکن ہر ''جذب،، اور ہر ''دفع،، نہیں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کبھی جذب، باطل، ظلم اور ظالم کا جذب ہے اور دفع، حقیقت اور انسانی فضائل کا دفع، بلکہ وہ ''جذب،، اور ''دفع،، جو علی علیہ سلام کے جاذبہ و دافعہ کی قسم سے ہوں۔ شیعہ یعنی علی علیہ سلام کی سیرت کا نمونہ۔ شیعہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ علی علیہ سلام کی طرح دوہری قوّت رکھتا ہے۔
یہ مقدّمہ اس لیے تھا کہ ہم یہ جان لیں کہ ممکن ہے ایک مذہب مرچکاہو لیکن اس مذہب کی روح دوسرے لوگوں میں جو بظاہر اس مذہب کے پیرو نہ ہوں، بلکہ اپنے کو اُس مذہب کے مخالف سمجھتے ہوں، زندہ ہو۔ خوارج کا مذہب مرچکا ہے، یعنی آج روئے زمین پر کوئی قابل توجہ گروہ خوارج کے نام سے موجود نہیں ہے جو اسی نام سے اس کی پیروی کرتا ہو لیکن کیا مذہب خارجی کی روح بھی مرچکی ہے؟ کیا اس روح نے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں میں حلول نہیں کیا ہے؟ آیا مثلاً خدانخواستہ ہمارے درمیان خاص کو اصطلاح میں ہمارے مقدس مآب طبقہ کے درمیان اس روح نے حلول نہیں کیا ہے؟
یہ ایسے موضوع ہیں جن پر علیٰحدہ غور و فکر کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم مذہبِ خارجی کو صحیح طور پر پہچان لیں تو شاید اس سوال کا جواب دے سکیں۔ خوارج کے بارے میں بحث کی افادیت صرف اسی نقطہئ نظر سے ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ علی علیہ سلام نے ان کو کیوں ''دفع،، کیا یعنی علی علیہ سلام کے ''جاذبہ،، نے ان کو نہ کھینچا اور اس کے برعکس، اُن کے دافعہ نے ان کو ''دفع،، کردیا؟
یہ بات مسلّم ہے جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ خوارج کی شخصیت اور ان کی جبلّت کی تشکیل میں اثر انداز ہونے والے تمام عناصر ایسے نہ تھے کہ علی علیہ سلام کے دافعہ کے دائرہئ اثر میں قرار پاتے۔ بلکہ ان کی جبلت میں ایسی خصوصیات اور روشن امتیازات بھی موجود تھے کہ اگران کے ساتھ تاریک پہلوؤں کا ایک سلسلہ نہ ہوتا تو وہ علی علیہ سلام کے جاذبہ کے زیر اثر قرار پاتے۔ لیکن ان کی جبلّت کے تاریک پہلو اتنے زیادہ تھے کہ جنہوں نے ان کو علی علیہ سلام کے دشمنوں کی صف میں لاکھڑا کیا۔
علی علیہ سلام کی جمہوریت
امیر المومنین نے خوارج کے ساتھ انتہائی آزادی اور جمہوری رویہ روا رکھا۔ یہ خلیفہ تھے اور وہ ان کی رعایا، ہر قسم کا سیاسی ایکشن ان کے بس میں تھا لیکن انہوں نے ان کو قید نہیں کیا ان کو کوڑے نہیں مارے اور حتیّٰ کہ بیت المال سے ان کا وظیفہ بھی بند نہیں کیا اور ان کو باقی لوگوں کے ساتھ ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ مثال علی علیہ سلام کی زندگی کی تاریخ میں انوکھی نہیں ہے تاہم دنیا میں اس کی مثال بہت ہم ہے۔ وہ ہر جگہ اپنے عقیدے کے اظہار میں آزاد تھے حضرت خود اور ان کے اصحاب آزاد عقیدے کے ساتھ اُن کے روبرو ہوتے اور گفتگو کرتے تھے۔ طرفین استدلال کرتے تھے ایک دوسرے کے استدلال کا جواب دیتے تھے۔ شاید اس قدر آزادی کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک حکومت نے اپنے مخالفین کے ساتھ اس حد تک جمہوری روّیہ روا رکھا ہو۔ وہ مسجد میں آتے اور علی علیہ سلام کی تقریریوں اور ان کے خطبوں میں مداخلت کرتے۔ ایک دن امیر المومنین منبر پر تھے ایک شخص آیا اور کوئی سوال کیا، علی علیہ سلام نے فی البدیہہ جواب دیا۔ لوگوں کے درمیان سے ایک خارجی پکار اٹھا: ''قاتلہ اللہ ما افقھہ،، ''خاد اس کو ہلاک کرے کتنا عالم ہے،، اور لوگوں نے اس کے ساتھ نمٹنا چاہا لیکن علی علیہ سلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اس نے صرف مجھے گالی دی ہے۔خارجی نمازِ جماعت میں علی علیہ سلام کی اقتداء نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں کافر سمجھتے تھے، مسجد میں آتے تھے اور علی علیہ سلام کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے اور یوں ان کو آزار پہنچاتے تھے۔ ایک روز جبکہ علی علیہ سلام نے نماز میں کھڑے ہیں اور لوگ ان کی اقتداء کر رہے ہیں، ابن الکواء نامی ایک خارجی کی آواز بلند ہوئی اور علی علیہ سلام کی طرف کنایۃً ایک آیت زور سے پڑھی:
( ولقد اوحی الیک و والی الذیب من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین )
یہ آیت پیغمبر سے خطاب ہے کہ تم اور تم سے پہلے پیغمبروں پر وحی ہوئی کہ اگر مشرک ہو جاؤ تو تمہارے اعمال ضائع ہوجائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ ابن الکواء اس آیت کو پڑھ کر علی علیہ سلام کو یہ جتانا چاہتا تھا کہ اسلام کے لیے تمہاری خدمات کو جانتے ہیں، تم سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہو، پیغمبر نے تمہیں اپنی برادری کے لیے منتخب کیا ہے، شب ہجرت تم نے درخشاں فداکاری کی اور پیغمبر کے بستر پر سوئے، اپنے آپ کو تلواروں کے منہ میں دے دیا اور بالآخر اسلام کے لیے تمہاری خدمات سے انکارنہیں کیا جاسکتا، لیکن خدا نے اپنے پیغمبر سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم مشرک ہو جاؤ تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اورچونکہ اب تم کافر ہوگئے ہو اس لیے تم نے اپنے گذشتہ اعمال کو ضائع کردیا ہے۔
علی علیہ سلام نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ جب تک اسکے قرآن پڑھنے کی آواز بلدن رہی آپ خاموش رہے یہاں تک کہ اس نے آیت ختم کرلی جونہی اس نے آیت ختم کی علی علیہ سلام نے اپنی نماز جاری رکھی۔ ابن الکواء نے دوبارہ آیت کو دُھرایا اور علی علیہ سلام نے فوراً خاموشی اختیار کرلی۔ علی علیہ سلام سکوت اس لیے اختیار کرتے تھے چونکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ:''و اذا قریئ القراٰن فاستمعوا له و انصتوا،، (۱)
''جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔،،
اور اسی لیے ہے کہ جب امام قرات میں مشغول ہو مامومین کو چاہےے کہ خاموش رہیں اور سنیں۔
جب وہ کئی بار اس آیت کو دُھرا چکا اور چاہا کہ نماز کی حالت کو برہم کرے اس کے بعدعلی علیہ سلام نے یہ آیت پڑھی:
( فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخلفنک الذیب لا یؤمنون )
''صبر کرو خدا کا وعدہ سچا ہے اور پورا ہوگا یہ ایمان و یقین سے بے بہرہ لوگ تمہیں نہیں ڈرا سکتے اور نہ تمہارے عزم کو کمزور کرسکتے ہیں،،
پھر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور نماز جاری رکھی۔
خوارج کی بغاوت اور سرکشی
ابتداء میں خارجی پرامن تھے اور صرف تنقید ار کھُلی بحث اپر اکتفا کرتے تھے، علی علیہ سلام کا رویہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا کہ ہم نے پہلے کہا یعینی کسی لحاظ سے ان کی راہ نہ روکتے یہاں تک کہ بیت المال سے ان کے وظیفے بھی بند نہ کئے لیکن جوں جوں وہ علی علیہ سلام کے توبہ کرنے کی طرف سے مایوس ہوتے گئے، انہوں نے اپنا رویہ بدل ڈالا اور انقلاب برپا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ وہ اپنے ایک ہم مسلک کے گھر میں جمع ہوگئے اور ان میں سے ایک نے پرجوش اور اشتعال انگیز تقریر کی اور اپنے دوستوں کو امر بہ معروف اور نہی از منُکر کے نام پر بغاوت اور سرکشی کی دعوت دی ان سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا:
____________________
(ابن ابی الحدید ج ۲، ص ۳۱۱)
''اما بعد فو الله ما ینبغی لقوم یومنون بالرحمٰن و ینیبون الی حکم القرآن ان تکون هذی الدنیا آثر عند هم من الامر بالعروف و النهی عن المنکر و القول بالحق و ان من و ضر فانه من یمن و یضر فی هذه الدنیا فانّ ثوابه یوم القیٰمة رضوان الله و الخلود فی جنانه فالخرجوا بنا أخواننا من هذه القریة الظالم اهلها الی کور الجبال اوالیٰ بعض هذه المدائن منکرین لهٰذه البدع المضلّة،، (۱)
''حمد و ثنا کے بعد! خدا کی قسم مناسب نہیں ہے کہ وہ گروہ جوبخشنے والے خدا پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن کے حکم پر چلتا ہو، اس کی نظر میں امربہ معروف اور نہی از منکر اور سچّی بات سے زیادہ، دنیا محبوب ہو، اگرچہ یہ نقصان پہنچانے اور خطرہ پیدا کرنے والی چیزیں کیوں نہ ہوں کیونکہ اس دنیا میں جو بھی خطرہ اور نقصان میں رہا، اس کی جزا قیامت میں حق کی رضا مندی اور ہمیشہ کی بہشت ہے۔ بھائیو! ہم کو اس شہر سے باہر نکالو جس کے رہنے والے ظالم ہیں، پہاڑی مقامات کی طرف یا کسی اور شہر کی طرف تاکہ ان گمراہ کن بد غنوں کے خلاف ہم جہاد کرسکیں اور ان سے اپنا دامن بچائیں۔،،
ان باتوں سے ان کے مشتعل جذبات اور بھڑک اٹھے، وہاں سے اٹھے۔ سرکشی اور انقلاب شروع کردیا۔ راستوں کا امن و امان سلب کرلیا اور لوٹ مار اور دہشت کو اپنا پیشہ بنالیا۔(۲) وہ چاہتے تھے کہ اس طرح حکومت کو کمزور کریں اور حکومت وقت کا تختہ الٹ دیں۔
یہ درگذر اور آزاد چھوڑ دینے کا مقام نہ تھا اب یہ اظہار عقیدہ کا مسئلہ نہ تھا بلکہ امن عامہ میں رخنہ ڈالنے کی کوشش اور شرعی حکومت کے خلاف مسلّح بغاوت تھی، اس لیے علی علیہ سلام نے ان کا پیچھا کیا اور نہرو ان کے مقام پر ان کے ساتھ آمنا ہوا۔ خطبہ پڑھا، نصیحت کی اور اتمام حجت کیا۔ پھر امان کا پرچم ابو ایّوب انصاری کے ہاتھ میں دیا کہ جوبھی اس کے سائے میں آجائے اس کے لیے پناہ ہے۔ بارہ ہزار میں سے آٹھ ہزار واپس آئے۔ باقیوں نے مزاحمت کی اور بُری طرح شکست کھائی اور چند ایک کے سوا ان میں سے کوئی باقی نہ بچا۔
____________________
۱)۲) الامامۃ والسیّاستہ ص ۱۴۱،۱۴۳ و کامل مبّرد ج ۲
خوارج کی نمایاں خصوصیّات
خوارج کی ذہنیت ایک مخصوص ذہنیت ہے وہ لوگ اچھائی اور برائی کا مرکّب تھے اور مجموعی طور پر ا س طرح کے لوگ تھے کہ بالآخر علی علیہ سلام کے دشمنوں کی صف میں قرار پائے اور علی علیہ سلام کی شخصیت نے ان کو ''دفع،، کیا ''جذب،، نہیں۔ ہم ان کی ذہنیت کے مثبت اور خوشگوار اور منفی و ناخوشگوار دونوں پہلوؤں اور مجموعی طور پر ان کی خطرناک بلکہ وحشت ناک فطرت کا ذکرکرتے ہیں:
۱ وہ مجاہدانہ اور فدا کارانہ ذہنیت رکھتے تھے اور اپنے عقیدہ اور نظریے کی راہ میں جان توڑ کوشش کرتے تھے۔ خوارج کی تاریخ میں ہم ایسی فداکاریاں دیکھتے ہیں جن کی نظیر انسانی زندگی کی تاریخ میں کم ہے اور اس فداکاری اور جذبہئ قربانی نے کو دلیر اور طاقتور بنا دیا تھا۔ ابن عبدربّہ ان کے بارے میں کہتا ہے:
''و لیس فی الافراق کلها اشد بصائر من الخوارج، و لا اشدا جتهاداً، ولا أوطن انفسا علی الموت منهم الّذی طعن فانقده الرمح فجعل یسعیٰ الی قاتله و یقول: و رب لترضیٰ،، (۱)
____________________
۱) فجر الاسلام ص ۲۶۳ بہ نقل از العقد الفرید
''تمام فرقوں میں خوارج سے زیادہ عقیدہ میں پختہ اور کوشش کرنے والا کوئی نہ تھا اور ان سے زیادہ موت کے لیے آمادہ کوئی پایا نہیں جاتا تھا۔ ان میں سے ایک کے نیزہ لگا تھا اور نیزہ سخت کاری لگا تھا، پھر بھی وہ اپنے قاتل کی طرف بڑھتا تھا اور کہتا تھا خدایا! میں تیری طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ تو خوش ہو۔،،
معاویہ نے ایک شخص کو اس کے بیٹے کے پیچھے بھیجا جو خارجی تھا، تاکہ اسے واپس لائے۔ لیکن باپ اپنے بیٹے کو اس کے فیصلے سے نہیں پلٹا سکا۔ آخر اس نے کہا میرے بیٹے! میں جاکر تیرے نو عمر بچے کو لاؤں گا تاکہ تو اسے دیکھے اور تیری محبت پدری بیدا ر ہو اور تو دست بردار ہو۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اپنے بیٹے سے زیادہ ایک کاری زخم کا مشتاق ہوں۔(۱)
۲ وہ عبادت گذار اور پرہیز گار لوگ تھے۔ راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ دنیا اور اس کی زیب و زینت سے کوئی رغبت نہ تھی۔ جب علی علیہ سلام نے ابن عباس کو اصحاب نہرو ان کی طرف بھیجا کہ وہ پند و نصیحت کرے۔ ابن عبّاس نے واپس آکر ان کی اس طرح توصیف کی:
''لهم جباه قرحة لطول السجود واید کثفنات الابل علیهم قمص مرحضة و هم مشمرون،، (۲)
''بارہ ہزار آدمی جن کی پیشانیاں کثرت عبادت کی وجہ سے داغدار ہیں خدا کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اس کثرت سے ان کے ہاتھ تپتی ہوئی
____________________
۱) فجر الاسلام ص ۲۴۳
۲) العقدالفرید ج ۲، ص ۳۸۹
خشک ریت کے اوپر رکھے گئے ہیں کہ وہ اونٹ کے پیرون کی طرح سخت ہوگئے ہیں۔ ان کا لباس کہنہ اور کھردرا ہے لیکن وہ سخت اور کٹر لوگ ہیں۔،،
خوارج اسلام کے احکام اور رسوم کے سخت پابند تھے۔ جس چیز کو وہ گناہ سمجھتے اس کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ ان کے اپنے معیار تھے اور ان معیاروں کے خلاف کسی چیز کا ارتکاب نہیں کرتے تھے اور جس کے ہاتھ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا اس سے دور رہتے تھے۔ زیاد بن ابیہ نے ان کے کسی آدمی کو قتل کردیا اور اس کے غلام کو طلب کرکے اس سے اس کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا کہ نہ میں نے دن کو اسے کھانا پہنچایا اور نہ رات کو اس کے لیے بستر بچھایا دن کو وہ روزہ رکھتا اور رات عبادت میں گذار دیتا۔(۱)
وہ جوبھی قدم اٹھاتے اپنے عقیدے کی راہ میں اٹھاتے اور اپنے تمام افعال میں اپنے مسلک کے پابند تھے اور اپنے عقائد کو پھیلانے کی راہ میں کوشش کرتے تھے۔ علی علیہ السّلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں:
''لا تقتلوا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فأخطاه کمن طلب الباطل فادرکه،،
(نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۶۰)
''میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرو کیونکہ جو حق کو تلاش کرتے اور خطا کو پائے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو باطل کو طلب کرے اور اسے پالے۔،،
____________________
۱) کامل مبّرد ج ۲
یعنی ان میں اور اصحاب معاویہ م یں فرق ہے، یہ حق کو چاہتے ہیں لیکن غلطی میں جا پڑے ہیں لیکن وہ شروع سے ہی دھوکہ باز رہے ہیں اور ان کا راستہ ہی باطل کا راستہ رہا ہے۔ اس کے بعد ار تم ان کو قتل کروگے تو اس کا فائدہ معاویہ کو پہنچے گا جو ان سے بد تر اور زیادہ خطرناک ہے۔
قبل اس کے خوارج کی تمام خصوصیات کو بیان ںکریں لازم ہے کہ یہاں ایک نکتے کا ذکر کریں جو خوارج کے تقدس و تقویٰ اور ان کی زاہد مآبی کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ علی علیہ سلام کی زندگی کی شگفتہ، ممتاز اور غیر معمولی خصوصیات میں سے ایک جس کی مثال نہیں مل سکتی، وہ آپ کا دلیرانہ اور پرجوش اقدام ہے ان تنگ نظر اور مغرور زادہ ان خشک کے مقابلے میں کیا۔ علی علیہ سلام نے ایسے ظاہر الصّلاح اور آراستہ، قیافے سے حق بجانب نظرآنے والے، بوسیدہ لباس اور عبادت پیشہ لوگوں پر تلوار کھینچی اور سب کو موت کے گھاٹ اتارا۔
ہم اگر ان کے اصحاب کی جگہ پر ہوتے اور اس طرح کے قیافے دیکھتے تو یقیناً ہمارے جذبات برانگیختہ ہوتے اور علی علیہ سلام پراعتراض کرتے کہ ایسے لوگوں پر تلوار اٹھائی؟!
ان خوارج کی داستان تاریخ اسلام کی عموماً اور تاریخ تشیع کی خصوصاً ایک انتہائی سبق آموز داستان ہے۔ علی علیہ سلام اپنے اس کام کی اہمیت اور غیر معمولی حیثیت سے واقف ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
''فانا فقأت عین الفتنة و لم یکن لیجترء علیها احد غیری بعد ان ماج غیهبها و اشتد کلبها،،
(نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۹۲)
''اس فتنے کی آنکھ میں نے نکال کی۔ میرے علاوہ کسی میں ایسے کام کی جرات نہ تھی جبکہ اس کے تاریکی اور شک پیدا کرنے والے دریا کی لہرین اوپر اٹھ چکی تھیں اور اس کی دیوانگی میں اضافہ ہوچکا تھا۔،،
امیر المومنین علیہ السّلام یہاں دو خوبصورت تعبیریں کرتے ہیں:
ایک اس معاملے کا شک اور تردد پیدا کرنا۔ خوارج کے ظاہری تقدس اور تقویٰ کی حالت ایسی تھی کہ راسخ الایمان مؤمن کو تردد میں مبتلا کردیتی۔ اس اعتبار سے ایک تاریک اور مبہم اور شک سے بھرپور فضا اور دو دلی پیدا ہو گئی تھی۔
دوسری تعبیر یہ ہے کہ آپ ان زاہد ان خشک کی حالت کو کَلَب (کاف اور لام پر زبر) سے تشبیہہ دیتے ہیں۔ کلب یعنی باؤلاپن۔ باؤلاپن دو دیوانگی ہے جو کُتّے میں پیدا ہوتی ہے اور وہ ہر ایک کو کاٹتا ہے اور اتفاق سے وہ (کتا) ایک پوشیدہ بیماری ( MICROBIC ) کاحامل ہوتا ہے، کتے کے دانت جس انسان یا حیوان کو کاٹیں اس کے لعاب دھن کے ساتھ وہ چیز انسان یا حویان کے جسم میں داخل ہوجاتی ہیں، وہ بھی دیوانہ ہو جاتا ہے اور کاٹنے لگتا ہے اور دوسروں کو بھی دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اگر یہ صورت حال جاری رہے تو غیر معمولی طورپر خطرناک ہوجاتی ہے یہی وجہ ہے کہ عقلمند لوگ ایسے کتوں کو ختم کردیتے ہیں تاکہ کم از کم دوسرے لوگ دیوانگی کے خطرے سے نجات پائیں۔
علی علیہ سلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ باؤلے کتوں کی طرح ہوچکے تھے اور قابل علاج نہ تھے۔ یہ اوروں کو کاٹتے تھے اور مبتلا کردیتے تھے اور باقاعدہ باؤلوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے تھے۔
افسوس! اس وقت کے مسلمانوں کی حالت پر۔ زاہدان خشک کا ایک گروہ،مٹھی بھر جاہل، بے خبر اور ضدی لوگ سب پر حملہ آور تھے۔
وہ کونسی قدرت ہے جو ان بہرے سانپوں کے مقابلے میں کھڑی ہو؟ وہ کونسی قوی اور طاقتور روح ہے جو ان زاہدانہ قیافوں اور تقویٰ کے مقابلے میں ٹھہر سکے؟ وہ کونسا ہاتھ ہے جو ان کے سروں پر وار کرنے کے لیے اٹھے اور نہ کانپے؟
یہی وجہ ہے کہ علی علیہ سلام فرماتے ہیں:
''و لم یکن لیجترء علیها احد غیری،،
یعنی ''میرے علاوہ کوئی ایسا اقدام کرنے کی جرات نہیں کرسکتا تھا۔،،
علی علیہ سلام، علی علیہ سلام کی بصیرت اور علی علیہ سلام کے راسخ ایمان کے علاوہ، خدا اور رسول اور قیامت پر ایمان رکھنے والا کوئی مسلمان اپنے اندر یہ جرات نہیں پاسکتا کہ وہ ان لوگوں پر تلوار اٹھائے۔ ایسے لوگوں کو قتل کرنے کی جرات صرف وہ کرسکتے ہیں جو اور اسلام پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں نہ کہ معمولی مؤمن اور معتقد افراد۔
یہی بات جس کو علی علیہ سلام اپنے لیے ایک عظیم فخر سمجھتے ہوئے کہتے ہیں:
''یہ میں تھا اور صرف میں کہ جس نے اس بڑے خطرے کا ادرا ک کیا جو ان زاہدان خشک کی طرف سے اسلام کو لاحق تھا۔ ان کی داغدار پیشانیاں، ان کا زاہدانہ لباس، ان کی ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول زبانیں حتّی کہ ان کا محکم عقیدہ اور ثابت قدمی (ان میں سے کوئی چیز) مریی بصیرت میں مانع نہ ہوسکی۔ وہ میں تھا جس نے سمجھ ل یا کہ اگر ان کے پاؤں جم گئے تو سب کو اپنی بیماری میں مبتلا کردیں گے اور دنیائے اسلام کو جمود، ظاہر پرستی، سطح پسندی اور تنگ نظری کی طرف لے جائیں گے جس سے اسلام کی کمر جھک جائے گی۔ کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا: دو گروہوں نے میری کمر توڑ دی، غیر ذمہ دار عالم اور مقدس مآب جاہل۔،،
علی علیہ سلام نے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے عالم اسلام میں خارجیت کا مقابلہ نہ کیا ہوتا اور کوئی ایسا نہ ہوتا جو اس طرح کے مقابلے کی جرات کرتا۔ میرے سوا کوئی نہ تھا جو یہ دیکھتا کہ وہ گروہ جن کی پیشانیاں کثرت عبادت سے داغدار ہوں، دینی اور مسلکی لوگ ہوں___ مگر در حقیقت اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہوں، ایسے لوگ جو اپنے خیال میں اسلام کے مفاد میں کام کرتے ہوں لیکن حقیقت میں اسلام کے حقیقی دشمن ہوں، اور ان کے ساتھ جنگ کرسکتا اور ان کا خون بہا سکتا، مگر میں نے یہ کام کردکھایا۔
علی علیہ سلام کے عمل نے خلفاء اور بعد کے حکام کے لیے راستہ ہموار کیا کہ وہ خوارج سے جنگ کریں اور ان کا خون بہائیں۔ اسلام کے سپاہی بھی بلا چون و چرا ان کی پیروی کرتے تھے کہ علی علیہ سلام نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی اور در حقیقت علی علیہ سلام کی سیرت اور دوسروں کے لیے یہ راستہ بھی کھولا کہ بغیر کسی پرواہ کے وہ کسی بھی ظاہر الصلاح، مقدس مآب اور دیندار لیکن احمق گروہ کے ساتھ جنگ کریں۔
۳ خوارج جاہل اور نادان لوگ تھے۔ وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے حقائق کو نہیں سمجھتے تھے اور ان کی غلط تفسیر کرتے تھے اور یہی کج فہمیاں آہستہ آہستہ ان کے لیے ایک مذہب اور آئین کی شکل اختیار کرگئیںکہ وہ اس راہ میں بڑی سے بڑی فداکاری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ شروع میں نہی از منکر کے اسلامی فریضے نے ان کو ایک گروہ کی شکل دی جن کا واحد ہدف ایک اسلامی سنت کا احیاء تھا۔
یہاں ہمیں توقف کرنا چاہیے اور تاریخ ا سلام کے ایک نکتے پر دقت سے سوچنا چاہیے۔
جب ہم سیرت نبوی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنحضرت نے پورے تیرہ سالہ مکی دور میں کسی کو جہاد حتی کہ دفاع کی اجازت نہ دی یہاںتک کہ مسلمان واقتی تنگ آگئے اور ایک گروہ نے آنحضرت کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی لیکن جو باقی رہ گئے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ ہجرت مدینہ کا دوسرا سال تھا جب جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ مکی دور میں مسلمانوں نے تعلیمات دیکھیں، اسلام کی روح سے آشنا ہوگئے اور اسلامی ثقافت روح کی گہرایوں میں رچ بس گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد ان میں سے ہر ایک کا حقیقی مبلغ بن گیا تھا اور رسول اکرم ان کو جب اطراف و اکناف میں بھیجتے تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح عہدہ برآہوتے ۔ جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا کہ وہ کس ہدف اور کس نظریئے کے لےے جنگ کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السّلام کے الفاظ میں:
''و حصلوا بصائر هم علی اسیافهم،،
''وہ اپنی بصیرتوں اور روشن اور منظم افکار کو اپنی تلواروں پر اٹھائے ہوئے ہوتے۔،،
ایسی صیقل شدہ تلواریں ہی تھیں اور ایسے ہی تعلیم یافتہ انسان تھے جو اسلام کے سلسلے میں اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں کامیا ہوسکے۔ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کی گفتگو کو دیکھتے ہیں جن چند سال پیشتر تلوار اور اونٹ کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں پہچانتے تھے، تو ان کے بلند افکار اور ان کی اسلامی ثقافت کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔
نہایت افسوس ہے کہ خلفاء کے دور میں زیادہ تر توجہ فتوحات کی طرف مبذول کی گئی اور دوسرے لوگوں کے لیے متوازی طورپر اسلام کے دروازے کھولنے اور
____________________
۱) نہج البلاغہ خطبہ ۱۴۸
ان کو اسلام کی طرف لے آنے سے غافل رہے کیونکہ اسلام کے نظریہئ توحید اور اسلام کے نظام عدل و مساوات کی کشش عرب و عجم کو اپنی طرف کھینچتی تھی لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ اسلام کی تہذیب و ثقافت کی تعلیم بھی دی جاتی اور لوگ مکمل طور پر اسلام کی روح سے آشنا ہوجاتے۔
زیادہ تر خوارج عرب تھے اور کم و بیش کچھ غیر عرب بھی ان کے درمیان تھے، لیکن سب کے سب بلا امتیاز عرب و غیر عرب مسلک سے جاہل اور اسلامی ثقافت سے نا آشنا تھے وہ اپنی تمام تر خامیوں کو طویل رکوع و سجود کے زور سے پر کرنا چاہتے تھے علی علیہ السّلام ان کی فطرت کی تعریف اسی طرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔
''جفاة طغام و عبید اقزام، جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب، ممن ینبغی ان یفقه و یودب و یعلم و یدرب و یولیّٰ علیه و یؤخذ علیٰ یدیه لیسوا من المهاجرین و الانصار الذین تبوؤا الدار و الایمان،،
''وہ گستاخ، بلندافکار اور لطیف احساسات سے عاری، پست، غلامانہ ذہنیت رکھنے والے، اوباش لوگ ہیں جوہر کونے سے اکٹھے ہوئے اور ہر کھدرے سے چلے آئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پہلے تعلیم دی جانی چاہیے، ان کو اسلامی آداب سکھا دیا جانا چاہیے اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے باخبر بنا دیا جانا چاہیے۔ ان کی نگرانی کی جانی چاہیے اور ان کے بازؤں کو گرفت میں رکھا جانا چاہیے نہ یہ کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ ہاتھ میں تلوار اٹھائے اسلام کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہار کرتے پھریں۔ یہ نہ ان مہاجرین میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت کی اور نہ انصار میں جنہوں نے مہاجرین کو اپنے جوار میں قبول کیا۔،،
مسلک سے بے خبر مقدس مآب طبقے کی پیدائش کہ خوارج بھی اس کا ایک جزو ہیں، اسلام کے لیے انتہائی گراں ثابت ہوئی خوارج سے گزر کر، جو تمام عیوب کے باوجود شجاعت اور فداکاری کی خوبیوں سے بہرہ مند تھے، اس قبیل کا ایک اور ظاہر پرست گروہ بھی وجود میں آگیا جن میں یہ خوبیاں بھی نہیں تھیں۔ یہ لوگ اسلام کی رہبانیت اور خلوت پسندی کی طرف لے گئے اور ظاہر داری اور ریا کا بازار گرم کیا۔ چونکہ یہ طاقتور لوگوں پر آہنی تلواریں کھینچنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے اس لیے صاحبان فضیلت کے خلاف زبان کی تلوار کھینچی اور ہر صاحب فضیلت کی تکفیران کو فاسق کہنے اور ان کی طرف بے دینی کی نسبت دینے کا بازار گرم کیا۔
بہرحال خوارج کی ایک ممتاز ترین خصوصیت ان کی جہالت اور نادانی تھی۔ ظاہر یعنی قرآن کے خط اور جلد اور معنی کے درمیان فرق نہ کرسکنا ان کی جہالت کا ایک مظہر ہے۔ اسی لیے انہوں نے معاویہ اور عمر و عاص کی سادہ چال سے دکھوکہ کھایا۔
ان لوگوں میں جہالت اور عبادت جڑواں تھیں۔ علی علیہ سلام چاہتے تھے کہ ان کی جہالت کے خلاف جنگ کریں لیکن یہ کیونکر ممکن تھا کہ ان کے زہدو تقویٰ اور عبادت کے پہلو کو ان کی جہالت کے پہلو سے الگ کردیا جائے بلکہ ان کی عبادت ہی عین جہالت تھی، جہالت سے جڑی ہوئی عبادت کی علی علیہ سلام کی نظر میں جو اوّل درجے کے اسلام شناس ہیں، کوئی قیمت نہ تھی لہذا انہوں نے ان کی سرکوبی کی اور ان کے زہد و تقویٰ اور عبادت کا پہلو علی علیہ سلام کے مقابلے میں کوئی ڈھال قرار نہ پاسکا۔
ایسے لوگوں اور گرہوں کی جہالت کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ موقعہ پرست لوگوں کا آلہئ کار بن جاتے ہیں اور اسلام کے بلند مقاصد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بے دین منافق لوگ ہمیشہ بیوقوف مقدس لوگوں کو اسلام کے مقاصد کے خللاف بھڑکاتے رہے ہیں اور یہ ان کے ہاتھوں کی تلوار اور ان کے کمان کا تیر بنتے رہے ہیں۔ علی علیہ السّلام کس قدر بلند اور لطیف پیرائے میں ان کی اس حالت کو بیان کرتے ہیں: فرماتے ہیں:
''ثم انتم شراء الناس و من رمی به الشیطان مرامیه و ضرب به تیهه،،
''پھر تمبدترین لوگ ہو تم شیطان کے ہاتھ میں اک تیر ہو کہ وہ اپنے نشانے پر مانے کے لیے تمہارے نجس وجود سے استفادہ کرتا ہے اور تمہارے ذریعے سے لوگوں کوشک و تردد اور گمراہی میں ڈالتا ہے۔،،
جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے: شروع میں خوارج کا گروہ ایک اسلامی سنت کے احیاء کے لیے وجود میں آیا لیکن بے بصیرتی اور نادانی نے ان کو اس مقام تک پنچا دیا کہ وہ قرآنی آیات کی غلط تفسیر کریں اور یہیں سے انہوں نے ایک مذہبی ریشہ پیدا کیا اور مذہب اور طریقہ ئ زندگی کی حیثیت سے جڑ پکڑی۔ قرآن کی ایک آیت ہے۔ جس میں خدا نے فرمایا:
( ان الحکم الا لله یقص الحق وهو خیر الفاصلین )
(سورہئ انعام آیت نمبر ۵۷)
اس آیت میں ''حکم،، کو ذات حق کے لیے مختص بتایا گیا ہے لیکن دیکھنا چاہیے کہ حکم سے مراد کیا ہے؟
بیشک یہاں حکم سے مراد انسانی زندگی کا آئین اور اس کے قوانین ہیں۔ اس آیت کی رو سے قانون وضع کرنے کا حق غیر خدا سے چھین لیا گیا ہے اور اس کو ذات حق (یا وہ شخص جس کو خدا اختیار دیدے) کا حق قرار دیا ہے لیکن خوارج نے ''حکم،، کو ، حکومت جس میں حکمیت بھی شامل ہے، کے معنی میں لیا ہے اور اپنے لیے ایک نعرہ تراش لیا اور کہتے تھے''لاحکم الا للہ،، ان کی مراد یہ تھی کہ وضع قانون کی طرح حکومت، حکمیت اور رہبری کرنے کا حق بھی صرف خدا کے لیے مخصوص ہے اور خدا کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی صورت میں لوگوں کے درمیان حکم یا حاکم ہو، جس طرح کہ قانون وضع کرنے کا حق نہیں رکھتا۔
کبھی امیر المؤمنین نماز میں مشغول ہوتے یا منبر کے اوپر سے خطبہ دے رہے ہوتے،یہ لوگ پکار اٹھتے اور ان سے خطاب کرکے کہتے''لاحکم الا لله لالک و لا لاصحابک،، ''اے علی علیہ سلام! حاکمیت کا حق خدا کے سوا کسی کونہیں ہے۔ تمہیں یا تمہارے اصحاب کو حق نہیں ہے کہ حکومت یا حکمیت کریں۔،، تو وہ جواب میں کہتے:
''کلمة حق یراد بها الباطل، نعم انه لاحکم الا لله، و لکن هو لاء یقولون لاامرة الا لله و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر، یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل ویجمع به الفییء و یقاتل به العدو، و تأمن به السبل و یؤخذ به للضّعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر ،،(۱)
____________________
۱) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۴۰
''ان کی بات حق ہے لیکن اس سے ان کی مراد باطل ہے۔ یہ درست ہے کہ قانون وضع کرنا خدا کے لئے مختص ہے لیکن یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کو حکومت کرنا اور امیر نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ حاکم کے محتاج ہیں خواہ وہ نیکو کار ہو یا بدکار (یعنی کم از کم نیکو کار نہ سمجھا جاسکے) اس کی حکومت کے سائے میں مؤمن اپنا کام (خدا کے لیے) انجام دیتا ہے اور کافرا اپنی دنیوی زندگی سے بہرمند ہوتا ہے یہاں تک کہ خداوند عالم اس کا وقت پورا کرتا ہے۔یہ حکومت ہی ہے جس کے ذریعے اور جس کے زیر سایہ مالیات جمع ہوتے ہیں، دشمن کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، راستے محفوظ اور پر امن ہوتے ہیں، کمزور اور ناتوان کا حق قوی اور ظالم سے دلایا جاتا ہے تاکہ نیکوکار آسائش پائیں اور بدکار کے شر سے محفوظ رہیں۔،،
خلاصہ یہ ہے کہ قانون خود بخود جاری نہیں ہوتا بلکہ ضروری ہے کہ کوئی فرد یا جماعت ہو جو اس کے اجراء کی کوشش کرے۔
۴ وہ تنگ نظر اور کوتاہ اندیش لوگ تھے۔ وہ انتہائی پست سطح پر سوچا کرتے انہوں نے اسلام اور مسلمانی کو اپنے محدود افکار کی چار دیواری میں محصور کردیاتھا دوسرے تمام کوتاہ نظروں کی طرح وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ سب غلط سمجھتے ہیں یا سرے سے سمجھتے ہیں نہیں ہیں اور سب غلط راستے پر چلتے ہیں اور سب جہنمی ہیں۔ اس قسم کے کوتاہ نظر لوگ سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں یہ ہے کہ اپنی تنگ نظری ایک دینی عقیدہ بنا لیتے ہیں، خدا کی رحمت کو محدود کردیتے ہیں ،خداوند عالم کو ہمیشہ غضب کی کرسی پر بٹھاتے ہیں اور اس بات کا منتظر قراردیتے ہیں کہ اس کے بندے سے کوئی لغزش ہو اور وہ دائمی عذاب کی طرف دھکیلا جائے۔ خوارج کے اصول عقائد میں سے ایک یہ تھا کا گناہ کبیرہ مثلاً جھوٹ یا غیبت یا شراب نوشی کاارتکاب کرنے والا کافر اور اسلام سے خارج ہے اور جہنم کی آگ کا ابدی طور پر مستحق ہے۔
اس طرح چند ایک کے سوا تمام انسان جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مذہبی تنگ نظری خوارج کی خصوصیات میں سے ہے لیکن آج اس کو ہم دوبارہ اسلامی معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے کی ہے کہ خوارج کے رسوم فنا ہوچکے اور مر چکے ہیں لیکن ان کے مذہب کی روح کم و بیش بعض افراد اور طبقات میں اسی طرح زندہ اور باقی ہے۔ چند خشک دماغ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اور انتہائی گنے چنے اپنے جیسے لوگوں کے علاوہ، دنیا کے سب لوگوں کو کفر اور الحاد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسلام اور مسلمانی کے دائرے کو انتہائی محدود سمجھتے ہیں۔
سابقہ باب میں ہم نے کہا ہے کہ خوارج اسلامی ثقافت کی روح سے آشنا نہ تھے لیکن بہادر تھے۔ چونکہ جاہل تھے اس لیے تنگ نظر تھے اور چونکہ تنگ نظر تھے جلد کفر اور فسق کافتویٰ لگاتے تھے یہاں تک کہ اسلام اور مسلمانی کو صرف اپنے آپ میں منحصر سمجھتے تھے اور ان تمام مسلمانوں کو جو ان کے اصول عقائد کو قبول نہ کرتے ہوں، کافر کہتے تھے اور چونکہ بہادت تھے اس لیے صاحبان قدرت کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور اپنے خیال میں ان کو امر بہ معروف اور نہی از منکر کرتے تھے اور خود مارے جاتے تھے اور جیساکہ ہم نے کہا ہے بعد کے ادوار میں ان کا جمود، ان کی جہالت، ظاہر پرستی، مقدق مآبی اور تنگ نظری دوسرے لوگوں میں باقی رہی لیکن شجاعت، بہادری اور فدا کاری ختم ہوگئی۔
بزدل خوارج یعنی ڈرپوک مقدس مآبوں نے آہنی شمشیریں تو کنارے پر رکھ دی ہیں اور قدرت مند لوگوں کو امر بمعروف و نہی از منکر سے، جوان کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور زبان کی تلوار کے ساتھ صاحبان فضیلت کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ اس طرح اور ایسے طریقے سے متّہم کیا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت کم ایسے فضیلت والے پائے جاتے ہیں جو اس طبقے کی تہمت کے تیر کا نشانہ نہ بنے ہو ایک کو انہوں نے منکر خدا کہا، دوسرے کو منکر معاد کہا، تیسرے کو معراج جسمانی کا منکر کہا، چوتھے کو صوفی کہا۔ پانچویں کو کچھ اور ۔۔۔ اور اسی طرح ۔۔۔ اور اس طریقے سے کہ اگر ہم ان بیوقوفوں کے نظریئے کو معیار قرار دیں تو کسی وقت کوئی عالم مسلمان نظر نہ آئے۔ جب علی علیہ سلام کو کافر قرار دیا گیا تو اوروں کا حال واضح ہے۔ بو علی سینا، خواجہ نصیر الدین طوسی، صدر المتالہین شیرازی، فیض کاشانی، سید جمال الدین اسد آبادی اور آخر میں محمد اقبال پاکستانی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس جام کا ایک گھونٹ چکّھا ہے۔
بوعلی اسی سلسلے میں کہتا ہے:
کفر چومنی گزاف و آسان نبود
محکم تر از ایمان من ایمان نہ بود
میری طرح کافر بننا بھی آسان نہیں ہے میرے ایمان سے زیادہ مضبوط کوئی ایمان نہیں ہے
دردھریکی چومن و آنہم کافر
پس درہمہ دھر یک مسلمان نبود
زمانے میں مجھ جیسا ایک آدمی ہو اور وہ بھی کافر پس سارے زمانے میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے
خواجہ نصیر الدین طوسی ایک شخص مسّمی ''نظام العلمائ،، کی طرف سے تکفیر کا نشانہ بنا۔ وہ کہتا ہے:
نظام بے نظام ارکافر خواند
چراغ کذب رانبود فروغی
بے نظام، نظام نے اگر مجھے کافر کہا (تو کہا کرے) جھوٹ کا چراغ زیادہ نہیں جلتا
مسلمان خوانمش، زیرا کہ نبود
دروغی را جوابی جز دروغی
میں اس کو مسلمان کہتا ہوں کیونکہ وہ مسلمان نہ تھا جھوٹ کا جواب، جھوٹ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں دیا جاسکتا
بہرحال خوارج کو مشخص اور ممتاز کرنے والی چیزوں میں سے ایک ان کی تنگ نظری اور کوتاہ بینی تھی کہ سب کو بے دین لا مذہب کہتے تھے علی علیہ سلام نے ان کو اس کوتاہ نظری کے خلاف استدلال کیا کہ یہ کیسی غلط فکر ہے جس کے پیچھے تم چلتے ہو؟ آپ نے فرمایا:
''پیغمبر ایک مجرم کو سزا دیتے تھے اس کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے حالانکہ اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب اگر کفر کا موجب ہوتا تو پیغمبر ان کے جنازے کی نماز کبھی نہ پڑھتے کیونکہ کافر کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔(۱) ''حضور نے شراب خوار پر حد جاری کی، چور کے ہاتھ کاٹے اور غیر شادی شدہ زنا کار کو کوڑے لگائے پھر ان تمام کو مسلمانوں کی صف میں جگہ دی اور بیت المال سے ان کا وظیفہ بند نہ کیا اور انہوں نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کیں۔ پیغمبر نے ان کے حق میں اسلامی سزاؤں کو جاری کیا لیکن ان کے ناموں کو مسلمانوں کی فہرست سے خارج نہ کیا۔(۲)
آپ نے فرمایا:
''فرض کرو میں نے غلطی کی اور اس کے نتیجے میں کافر ہوگیا پھر تم دوسرے تمام مسلمانوں کی تکفیر کیوں کرتے ہو؟ کیا کسی کی گمراہی و ضلالت اس
____________________
۱) سورہئ توبہ آیت نمبر ۴
۲) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۱۲۷
بات کا موجب بنتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی گمراہی اور خطا پر ہوں اور قابل مواخذہ ہوں؟! کیوں تم ہاتھوں میں تلوار لیے بے گناہ اور گناہ گار ۔۔۔ تمہاری اپنی نظر ۔۔۔ تمہاری اپنی نظر میں ۔۔۔ دونوں کو تلوار کے گھاٹ اتارتے ہو؟ !،،(۱)
یہاں امیر المؤمنین دو زاویوں سے ان کے عیوب کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کا دافعہ دونوں زاویوں سے ان کو دفع کرتا ہے، ایک اس زاویئے سے کہ انہوں نے بے گناہ کو گناہ گار قرار دیا ہے اور اس کو مواخذہ کی گرفت میں لیا ہے اور دوسرے اس زاویئے سے کہ انہوں نے ارتکاب گناہ کوکفر اور اسلام سے خارج ہونے کا موجب گردانا ہے یعنی انہوں نے دائرہئ اسلام کو محدود کردیا ہے کہ جس نے بھی بعض حدود سے باہر قدم رکھا وہ اسلام سے خارج ہوگیا۔
علی علیہ سلام نے یہاں تنگ نظری اور کوتاہ بینی کی مذمت کی ہے اور در حقیقت علی علیہ سلام کی خوارج کے ساتھ جنگ اس طرز اندیشہ و فکر کے ساتھ جنگ ہے نہ کہ افراد کے ساتھ جنگ۔ کیونکہ افراد اگر اس طرح فکر نہ کرتے تو علی علیہ سلام بھی ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرتے۔ آپ نے ان کا خون بہایا تاکہ ان کی موت کے ساتھ ان کے خیالات اور افکار بھی مرجائیں، قرآن صحیح طورپر سمجھا جائے اور مسلمان، قرآن اور اسلام کو اس طرح دیکھیں جس طرح کہ ہیں اور جس طرح کہ اس (اسلام) کا قانون بنانے والے (خدا) نے چاہا ہے۔
یہ کوتاہ بینی او رکج فہمی کا نتیجہ تھا کہ وہ قرآن کو نیزے پر بلند کرنے کی سیاست سے دھوکہ کھاگئے اور اسلام کے لےے عظیم خطرے پیدا کئے اور علی علیہ سلام کو جو نفاق کی بیخ کنی اور
____________________
۱) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۱۲۷
معاویہ اور اس کے افکار کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، جنگ کرنے سے روک دیا۔ اس کے نتیجے میں کیسے کیسے منحوس حوادث نے اسلامی معاشرے کا رخ نہ کیا؟(۱) خوارج اپنی اس کوتاہ نظری کے نتیجے
میں عملاً تمام مسلمانوں کو، مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے ذبیحہ کو حلال نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خون مباح سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ شادی بیان نہیں کرتے تھے۔
____________________
۱) جن حوادث نے عالم اسلام کا رخ کیا ان میں مسلمانوں کوپہنچنے والے وہ روحی و معنوی زخم ہیں جو سب سے زیادہ توجہ کو اپنی طرف جلب کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے دعوت اسلامی کی بنیاد بصیرت اور تفکر کو قرار دیا تھا اور خود قرآن نے لوگوں کے لیے اجتہاد اور ادراک عقل کا راستہ کھولا تھا۔
( فلو لا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین )
(۹:۱۲۲)
'' پس ان میں سے ہر گروہ سے کچھ لوگ نہیں نکلتے تاکہ وہ دین میں تفقہہ کریں؟،،
محض کسی چیز کے درک کرلینے کو ''اس چیز میں تفقہہ،، نہیں کہتے بلکہ گہری نظری اور بصیرت تفقہہ ہے۔
( ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ) (۸:۲۹)
''اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو خدا تہارے دل میں ایک روشنی کو قرار دیتا ہے جس سے تم اچھے برے کی پہچان اور تمیز کرو۔،،
( والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ) (۲۹:۶۹)
''جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھا دیتے ہیں۔،،
خوارج نے قرآن کے اس طرز تعلیم کے بالکل برعکس جو چاہتا ہے کہ اسلامی فقہ ہمیشہ زندہ اور متحرک رہے، جمود اور ٹھہراؤکا آغاز کردیا۔ انہوں نے اسلامی معارف کو مردہ اور ساکن سمجھ لیا اور ظاہری شاکل اور صورت کو بھی اسلام کے متن میں گھسیڑ دیا۔
اسلام نے ہرگز شکل و صورت اور زندگی کے ظاہر پر توجہ نہیں دی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی ساری توجہ روح و معنی اور اس راہ پر ہے جو انسان کو ان مقاصد اور معانی تک پہنچاتی ہے۔ اسلام نے مقاصد و معانی اور ان مقاصد تک پہنچنے کی راہ دکھانے کو اپنا دائرہ کار مقرر کر رکھا ہے اس کے علاوہ انسان کو آزاد چھوڑا ہے اور یوں تمدن ارو ثقافت کے پھیلاؤ سے کسی قسم کے تصادم سے پرہیز کرتا ہے۔
اسلام نے کوئی مادّی ذریعہ یا کوئی ظاہری شکل نہیں پائی جس کو ''تقدّس،، کامقام حاصل ہو اور مسلمان اس شکل اور ظاہر کی حفاظت کو اپنا فرض جان لے۔ اس طرح علم اور تمدن کی توسیع کے مظاہرے کے ساتھ تصادم سے پرہیز ان اسباب میں سے ایک ہے جس نے اس دین کو زمانے کے تقاضوں کے ساتھ منطبق کرنا آسان بنا دیا ہے اور اس کی ابدی بقاء میں سب سے بڑی رکاوٹ کو ختم کردیا ہے۔ یہ تعقّل ار تدیّن میں توازن ہی ہے جس نے ایک طرف اصول کو ثبات اور پائداری بخشی ہے اور دوسری جانب اس کو ظاہری اشکال سے الگ کردیا ہے۔ کلیات کو واضح کردیا ہے اور ان کلیات کے گونا گون مظاہر ہیں اور یہ مظاہر بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت (اصول) کو تبدیل نہیں کرتے۔
لیکن مظاہر اور مصادیق پر حقیقت کی تطبیق خود اتنا آسان کام نہیں کہ ہر شخص کا کام ہو بلکہ ایک گہرے ادراک اور صحیح سمجھ بوجھ کا محتاج ہے اور خوارج کی فکر میں جمود تھا اور جو کچھ سن لیتے اس سے ماوراء کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اسی لیے امیر المؤمنین نے جس وقت ابن عباس کو ان سے بات چیت کے لیے بھیجا تو اس نے فرمایا: ''لا تخاصمھم بالقراٰن فان القرآن حمال ذو وجوہ تقول و یقولون و لکن حاججھم بالسنۃ فانہم لن یجدوا عنھا محیصا،، ''ان کے ساتھ قرآن سے بحث نہ کرو۔ کیونکہ قرآن بہت سے احتمالات اور توجیہات کو قبول کرتا ہے جو تم کہو یا وہ کہیں۔ بلکہ سنت اور پیغمبر کے ارشادات کے ساتھ ان سے بحث کرو اور استدلال کرو کہ صریح ہے اور اس سے فرار کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔،، یعنی قران کلیات ہے، بحث کا مقام پر وہ ایک چیز کو مصداق بنا لیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں تم کسی اور چیز کو، اور یہ صورت حال بحث و مباحثہ کے مقام پر قطعاً نتیجہ خیز نہی ہے۔ وہ اس قدر سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ قرآن کی کسی حقیقت کو درک کرلیں اور اس کی اس کے صحیح مصداق کے ساتھ تطبیق کریں بلکہ ان کے ساتھ سنت کی بنیاد پر گفتگو کرو جو جزئی ہے او رمصداق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہاں حضرت نے ان کی جمود فکری اور خشک مغری کی طرف اشارہ کیاہے دراں حالیکہ وہ دیندا رتھے جو تعقل اور تدّین میں فرق کی دلیل ہے۔
خوارج صرف جہالت اور فکری جمود کی پیداوار تھے۔ وہ تجزیہ اور تحلیل کی قدرت نہیں رکھتے تھے اور کلی مصداق سے جدا نہیں کرسکتے تھے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اگر کسی خاش مقام پر حکمیت غلطی تھی تو پھر اس کی اساس ہی باطل اور غلط ہے حالانکہ یہ ممکن ہے کہ اس کی اساس محکم اور صحیح ہو لیکن کسی خاص مقام پر اس کا اجراء نارواء ہو لہٰذا تحکیم کی داستان میں ہم تین مرحلے دیکھتے ہیں:
۱ تاریخ شاہد ہے کہ علی علیہ سلام حکمیت پر راضی نہ تھے۔ معاویہ اور اس کے ساتھیوں کی تجویز کو فریب او ردھوکہ سمجھتے تھے اور اس بات پر ان کو سخت اصرار تھا اور ڈٹے ہوئے تھے۔
۲ کہتے تھے کہ اگر شورای تحکیم کی تشکیل ناگزیر ہے توابو موسیٰ ایک بے تدبیر شخص ہے اور اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایک اہل آدمی کا انتخاب ہونا چاہیے اور خود ابن عباس یا مالک اشتر کو تجویز کرتے تھے۔
۳ حکمیت کا اصول بذاب خود صحیح ہے اور غلط نہیں ہے۔ یہاں بھی علی علیہ سلام کو اصرار تھا ''ابو العباس مبرد،، ''الکامل فی للغۃ و الادب،، ج ۲، ص ۱۳۴ میں کہتا ہے! علی علیہ سلام نے ذاتی طور پر خوارج کے ساتھ مباحثہ کیا اور ان سے کہا: تم خدا کی قسم کھا کر بتاؤ! کیا تم میں سے کوئی بھی میری طرح تحکیم کا مخالف تھا؟ وہ بولے: خدایا! تو گواہ ہے کہ نہ تھا۔ فرمایا: کیا تم نے مجھے مجبور نہ کیا کہ میں قبول کروں؟ بولے، خدایا! توگواہ ہے کہ ایسا ہی تھا۔ فرمایا: پس تم کیوں میری مخالفت کرتے ہو اور مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بولے: ہم ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور ہمیں تونہ کرنی چاہیے، ہم نے توبہ کرلی ہے۔ تم بھی توبہ کرلو۔ فرمایا: ''استغفر اللہ من کل ذنب، وہ بھی جو تقریبا چھ ہزار لوگ تھے لوٹ آئے اور کہنے لگے علی علیہ سلام نے توبہ کرلی ہے اب ہم منتظر ہیں کہ وہ حکم دیں اور ہم شام کی طرف کوچ کریں۔ اشعث ابن قیس ان کی خدمت میں آیا اور کہا: کہ لوگ کہتے ہیں آپ تحکیم کو گمراہی سمجھتے اور اس پر قائم رہنے کو کفر سمجھتے ہیں؟ حضرت نے منبر پر گئے، خطبہ پڑھا اور فرمایا: جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میں تحکیم سے پھر گیا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے اور جو شخص اس کو گمراہی سمجھتا ہے وہ خو دگمراہ تر ہے۔ خوارج بھی مسجد سے باہر نکل آئے اور دوبارہ علی علیہ سلام کے خلاف شورش کی۔،،
حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مقام اشتباہ تھا۔ اس لیے کہ معاویہ اور اس کے ساتھی حیلہ کرنا چاہتے تھے اور چونکہ ابوموسیٰ نالائق آدمی تھا اور میں خود بھی شروع سے کہتا تھا۔ لیکن تم نے قبول نہ کیا لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تحکیم کی اساس ہی باطل ہو۔
ایک طرف لوگ حکومت قرآن اور حکومت افراد میں فرق نہیں کرتے تھے۔ حکومت قرآن کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں قرآن کا جو بھی حکم ہے اس پر عمل کیا جائے اور حکومت افراد کے قبول کرنے کامطلب یہ ہے کہ ان کے ذاتی نظریات اور آراء کی پیروی کی جائے اور قرآن جو خود بات نہیں کرتا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے حقائق کو غور و فکر کے ساتھ حاصل کیا جائے اور ایسا کرنا بھی افراد کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت خود اس بارے میں فرماتے ہیں:
انا لم نحکم الرجال و انما حکمنا القراٰن و هٰذا القراٰن انما هو خط مسطور بین الدفتین لا ینتطق بلسان ولا بدله من ترجمان، و انما ینطق عنه الرجال و لما دعانا القوم الی ان نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب الله، وقد قال سبحانه ''فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول،، فرده الی الله ان نحکم بکتابه، ورده الی الرسول ان نأحذ بسنته، فاذا حکم بالصق فی کتاب الله فنحن احق الناس به، و ان حکم بسنته رسول الله فنحن اولاهم به ۔ (نھج البلاغہ خطبہ نمبر ۱۲۵)
''ہم نے لوگوں کو حاکم قرار نہیں دیا ہے بلکہ قرآن کو حاکم قرار دیا ہے اور یہ قرآن جلد کے درمیان تحریریں ہیں، یہ زبان سے بات نہیں کرتا اور بیان کرنےوالے کا محتاج ہے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور چونکہ اہل شام نے یہ چاہا کہ ہم قرآن کو حاکم قرار دیں، ہم ایسے لوگ نہ تھے جو قرآن سے روگردانی کرتے جبکہ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے:
''اگر تم کسی چیز کے بارے میں کوئی نزاع رکھتے ہو تو اس کو خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو،،
خدا کی طرف رجوع کرنے کامطلب یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کو حاکم قرار دیں اور اس کی کتاب کے مطابق حکم کریں اور پیغمبر کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سنت کی پیروی کریں اور اگر خدا کی کتاب کے مطابق صحیح فیصلہ کیا جائے تو ہم اس کے سب سے زیادہ سزاوار ہیں اور اگر اس کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ ہو تو ہم اس کے لیے اولیٰ ہیں۔،،
یہاں ایک اشکال ہے کہ شیعہ اعتقاد اور امیر المؤمنین (نہج البلاغہ خطبہ ۲ آخری حصہ) کے مطابق اسلام میں حکومت اور امامت ''انتصابی،، اور مطابق ''نصّ،، ہے پس حضرت نے کیونکر حکمیّت کو تسلیم کرلیا اور بعد میں بھی اس کا سختی سے دفاع کیا؟
اس اشکال کا جواب ہم امام کے کلام کے ذیل میں ہی بخوبی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ فرماتے ہیں اگر قرآن میں صحیح تدبر کیا جائے اور اس کے مطابق صحیح فیصلہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ ان کی امامت اور خلافت کے علاوہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا اور یہی حال سنت پیغمبر کا بھی ہے۔
اسلامی فرقوں کا ایک دوسرے پر اثر:
خوارج کے حالات کا مطالعہ ہمارے لیے اس نقطہئ نظر سے قیمتی ہے کہ ہم سمجھ لیںکہ انہوں نے سیاسی لحاظ سے ،عقیدہ و سلیقہ کے لحاظ سے اور فقہ و احکام کے لحاظ سے اسلامی تاریخ پر کیا اثر چھوڑا ہے۔
مختلف فرقے اور گروہ ہر چند رسوم کے چوکھٹے میں ایک دوسرے سے دور ہیں لیکن کبھی ایک مذہب کی روح دوسرے مذہب میں حلول کرجاتی ہے اور وہ مذہب درحالیکہ دوسرے کا مخالف ہے، اس کی روح اور معنی کو قبول کرتا ہے آدمی کی طبیعت (معنی و مفہوم) چراتی ہے کبھی ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو مثلا سنی ہیں لیکن روح اور معنی کے اعتبار سے شیعہ ہیں اور کبھی اس کے برعکس کبھی کوئی شخص طبیعتاً شریعت اور اس کے ظاہر کا پابند ہوتا ہے لیکن روح کے اعتبار سے صوفی ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ اسی طرح بعض لوگ بظاہر اور رسوم کے اعتبار سے ممکن ہے شیعہ ہوں لیکن روحاً اور عملاً وہ خارجی ہوں۔ یہ بات افراد پر بھی صادق آتی ہے اور امتوں اور ملتوں پر بھی۔
جب مختلف فرقے ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوں ہر چند ان کے رسوم محفوظ ہوں، لیکن ان کے عقائد اور طریقے ایک دوسرے میں سرایت کرجاتے ہیں۔ مثلاً ۔۔۔ طبل وترم بجائے کی رسمیں قفقاز کے راسخ العقیدہ لوگوں کے توسط سے ایران میں سرایت کرگئیں اور چونکہ لوگوں کے جذبات ان کو قبول کرنے کے لےےے آمادگی رکھتے تھے، اس لیے بجلی کی طرح ہر جگہ پھیل گئیں۔
اس بناء پر مختلف فرقوں کی روح پر غور کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی فرقہ حسن ظن اور ''ضع فعل اخیک علی احسنہ،، کی پیداوار ہوتا ہے ۔ مثلاً سنی جو شخصیتوں کے ساتھ حسن ظن کی پیداواری ہیں اور ایک فرقہ ایسا ہے جو ایک خاص نقطہء نظر اور افراد شخصیات کی بجائے اصول اسلامی کو اہمیت دینے کے نظریئے کو پیداوار ہے۔ ایسے لوگ قہراً تنقیدی نظر کے حامل ہوں گے جیسے صدر اول کے شیعہ۔ ایک فرقہ باطن، روح اور باطن کی تاویل کو اہمیت دینے کے نقطہء نظر کی پیداوار ہوگا جیسے صوفیاء اور ایک فرقہ تعصب اور جمود کی پیداوار جیسے خوارج۔
جب ہم فرقوں کی روح اور ان کے ابتدائی تاریخی عوامل کو پہچان لیں تو بہتر طور پر فیصلہ کرسکیں گے کہ بد کی صدیوں میں کون سے عقائد ایک فرقے سے دوسرے فرقے تک پہنچے اور اپنے رسوم اور ناموں کے چوکھٹے میں ہونے کے وصف، ان کی روح کو قبول کرلیا ہے۔ اس اعتبار سے عقائد اور افکار زبانوں (نعتوں) کی مانند ہیں کہ بغیر کسی شعوری کوشش کے ایک قوم کی زبان کے الفاظ دوسری قوم کی زبان میں سرایت کرجاتے ہیں جیساکہ ایران کی فتح کے بعد مسلمانوں کے ذریعے عربی زبان کی الفاظ فارسی زبان میں وارد ہوگئے۔ اسی طرح عربی اور فارسی زبانوں میں ترکی زبان کی تاثیر ہے۔ مثلاً متوکل کے دور کی ترکی اور سلجوقیوں اور مغلوں کے دور کی ترکی اور یہی حال دنیا کی ساری زبانوں کا ہے ار اسی طرح ذوق اور سلیقے بھی ہیں۔
خوارج کے طرز تفکر اور ان کے افکار کی روح ___ فکری جود اور تعقل کو تدین سے علیحدہ کرنا ___ نے تاریخ کے دھارے میں مختلف صورتوں سے اسلامی معاشرے کے اندر رخنہ پیدا کیا ہے۔ اگرچہ تمام اسلامی فرقے ان کو اپنا مخالف سمجھتے پیں لیکن خارجیت کی روح کو پم ان کے طرز فکر میں (کار فرما) دیکھتے ہیں اور یہ اس کے نتیجے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو ہم نے کہا ہے کہ آدمی کی طبیعت (معنی اور مفہوم کو) چراتی ہے اور باہمی میل جول نے چرانے کے اس عمل کو آسان کردیا ہے۔
کچھ خارجی مسلک رکھنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور ہیں، جن کا وطیرہ ہر نئی چیز کا مقابلہ کرنا ہے حتی کہ وسائل زندگی کو جن کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ اسلام میں کسی مادی وسیلہ یا ظاہری شکل کو کوئی تقدس کا مقام حاصل نہیں ہے، وہ ان کو تقدس کا رنگ دیتے ہیں اور ہر نئے وسیلے سے استفادہ کرنے کو کفر اور زندقہ سمجھتے ہیں۔
اسلام کے اعتقادی، علمی اور اسی طرح فقہی مکابت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مکاتب ہیں جو تعقل اور تدین میں علیحدگی کی روح کی پیداوار ہیں اور ان کا مکتب جارجیت کی فکر کا صحیح معنوں میں جلوہ گاہ ہے۔ کسی حقیقت کے کشف کی راہ میں یا کسی فرعی قانون کے استخراج کی راہ میں انہوں نے عقل کو مکمل طور پر مسترد کررکھا ہے اور اس کی پیروی کو بدعت اور بے دینی کہتے ہیں حالانکہ قرآن نے بہت سی آیات میں انسان کوعقل کی طرف بلایا اور انسانی بصیرت کو دعوت الہی کا نگہبان قرار دیا ہے۔
معتزلہ جو دوسری صدی ہجری کے اوائل میں وجود میں آئے تھے ___اور ان کی پیدائش کفر و ایمان کے معنی اور تفسیر کے اوپر بحث اور کاوش کے نتیجے میں ہوئی کہ آیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب موجب کفر ہے یا نہیں اور یوں قہراً ان کی پیدائش خوارج کے ساتھ مربوط ہے ___ ایسے لوگ تھے جو کسی قدر آزاد فکر کرنا چاہتے تھے اور ایک عقلی زندگی کو وجود میں لانا چاہتے تھے، اگر چہ وہ علم کے مبادی اور مبانی سے بے بہرہ تھے تاہم اسلامی مسائل کو کسی حد تک آزادانہ غور و فکر اور تدبر کا موضوع قرار دیتے تھے، احادیث پر کسی حد تک تنقید کرتے تھے صرف ان آراء اور نظریات کی پیروی کرتے تھے جن پر ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تحقیق کی گئی ہو یا اجتہاد کیا گیا ہو۔
یہ لوگ شروع سے ہی اہل حدیث اور ظاہر پرستوں کی مخالفت اور مقاومت سے دوچار تھے۔ وہ لوگ جو صرف حدیث کے ظواہر کوحجت جانتے تھے اور قرآن اور حدیث کی روح سے کوئی کام نہ رکھتے تھے، وہ عقل کے صریح حکم کی قدر و قیمت کے قائل نہ تھے۔ جس قدر معتزلہ فکر و اندیشہ کی قیمت کے قائل تھے یہ صرف ظواہر کی اہمیت کے اتنے ہی قائل تھے۔
اپنی ڈیڑھ سو سالہ زندگی میں معتزلہ کو عجیب قیاسات ( NOTIONS ) سے واسطہ پڑا یہاں تک کہ بالآخر اشعری مذہب وجود میں آیا اور تفکر اور اندیشہ ہائے عقلی اور فلسفیانہ طرز فکر کے سرے سے منکر ہوگئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ جو روایات ان تک پہنچی ہیں ان کی ظاہری تعبیر پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں اور معنی کی گہرائی میں تدبر اور تفکر نہ کریں ہر قسم کا سوال و جواب اور چون و چرا بدعت ہے۔ امام احمد بن حنبل جو اہلسنت کے ائمہ اربعہ میں سے ہےں معتزلہ کے طرز فکر کی سخت مخالفت کرتے تھے جس کے نتیجے میں ان کو قید میں ڈال دیا گیا اور کوڑوں کی سزا دی گئی لیکن وہ اپنی مخالفت پر قائم رہے۔ بالآخر اشعری کامیاب ہوگئے اور انہوں نے عقلی طرز فکر کی بساط لپیٹ دی اوران کی کامیابی سے عالم اسلام کی عقلی زندگی پر کاری ضربلگائی۔ اشاعرہ، معتزلہ کو اصحاب بدعت سمجھتے تھے ایک اشعری شاعر اپنے مذہب کی کامیابی کے بعد کہتا ہے:
ذهبت دولة اصحاب البدع
و وهی حبلهم ثم انقطع
و تداعی بانصراف جمعهم
حزب الا بلیس الذی کان جمع
هل لهم یا قومفی بدعتهم
من فقیه او امام یتبع
(المتزلہ تالیف زہدی جاء اللہ ص ۱۸۵)
''صاحبان بدعت کی قددت کا زمانہ ختم ہوگیا۔ ان کی رسی ڈھیلی پڑگئی پھر ٹوٹ گئی۔ اور وہ گروہ جس کو شیطان نے اکٹھا کردیا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ گروہ کو منتشر کردیں۔ اے ہم مسلکو! کیا اپنی بدعتوں میں ان کا کوئی قابل تقلید فقیہ یا امام تھا؟،،
''اخباریوں،، کا مکتب بھی جو ایک شیعہ مکتب فقہ ہے اور گیارہو ںاور بارہوں صدی ہجری میں عروج پر تھا۔ اہلسنت کے فرقوں ظاہریوں اور اہل حدیث کے بہت قریب ہے۔ فقہی نقطہ ء نظر سے ہر دو مکتب ایک ہیں اور ان کا واحد اختلاف احادیث کی پیروی کے بارے میں ہے ۔۔۔ یہ بھی تعقل اور تدین میں فرق کی ایک قسم ہے۔
اخباریوں نے عقل کو مکمل طور پر معطل کر رکھا ہے اور متون سے اسلامی احکام کے استخراج کے سلسلے میں عقل کی قمیت اور حجیت سے مکمل انکار کرتے ہیں اور اس کی پیروی کو حرام سمجھتے ہیں اور اپنی تالیفات میں اصولیئین ۔۔۔ ایک اور شیعہ مکتب فقہ کے حامی ۔۔۔ پر سخت برہم ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف کتاب و سنت حجت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حجیت کتاب بھی تفسیر سنت و حدیث کی راہ سے ہے اور حقیقت میں قرآن کو بھی انہوں نے حجیت سے گرادیا ہے اور صرف حدیث کے ظاہر کو پیروی کے قابل سمجھتے ہیں۔
اس وقت ہم اسلام میں مختلف طرز فکر کاجائزہ لینے اور ان مکاتب کے پیروکاوں پر بحث کرنے کے متحمل نہیں ہیں جو دین کو عقل سے جدا کرتے ہیں جو خارجیت کی روح ہے۔ اس بحث کا دامن بہت وسیع ہے لیکن ہمارا مقصد صرف یہ اشارہ کرنا تھا کہ مختلف فرقوں کا ایک دوسرے پر کتنا اثر ہے اور ی ہکہ اگر چہ خارجیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی لیکن اس کی روح ہر اسلامی دور اور ہر صدر میں جلوہ گر رہی ہے۔ آج بھی دنیائے اسلام کے چند روشن فکر اور اہل قلم ان کے طرز فکر کو جدید اور عصری زبان میں لے آتے اور اس کوایک قابل توجہ فلسفے کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
قرآن کو نوک نیزہ پر بلند کرنے کی سیاست
''قرآن کو نوک نیزہ پر بلند کرنے کی سیاست،، تیرہ صدیوں سے مسلمانوں میں کم و بیش رائج ہے۔ خاص طور پر جب مقدس مآب اور ظاہر پرست لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، زہد و تقویٰ کی ظاہر داری کا بازار گرم ہو، موقعہ پرست لوگ قرآن نوک نیزہ پر بلند کرنے کی سیات رائج کردیتے ہیں۔ یہاں سے جو سبق حاصل کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے۔
الف:۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جب بھی جاہل، نادان اور بے خبر لوگ پاکیزگی اور تقویٰ کے مظہر سمجھے جانے لگیں اور لوگ ان کو باعمل مسلمان کا نمونہ ( SYMBOL ) سمجھِنے لگیں اس وقت چالاک مفاد پرستوں کو اچھا موقعہ ہاتھ آجاتا ہے ۔ یہ چالاک لوگ ان کو اپنے مقاصد کے لیے آلہئ کار بنا لیتے ہیں اور ان کو حقیقی مصلحین کے افکار کی راہ میں مضبوط رکاوٹ بنالیتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسلام دشمن عناصر باقاعدہ اس ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی اسلام کی طاقت کو انہو ںنے خ ود اسلام کے خلاف استعمال کیا ہے۔ مغربی استعمار کو اس ذریعے سے فائدہ اٹھانے کا وسیع تجربہ حاصل ہے۔ اپنے مفاد کے لیے یہ مسلمانوں کے درمیان جھوٹے جذبات ابھارنا اور خاص طور پر فرقے پیدا کرکے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کس قد شرم کی بات ہے کہ ایک دل جلا مسلمان بیرونی اثر و نفوذ کو ختم کرنے کے لیے اٹھے اور جن لوگوں کو وہ نجات دینا چاہتا ہے ،وہی دین اور مذہب کے نام پر اس کے لےے سد راہ بن جائیں جی ہاں! اگر لوگ عام لوگ جاہل اور بے خبر ہوں، تو منافق خود اسلام کے مورچے سے اپنے لیے استفادہ کریں گے۔
ہمارے اپنے ایران میں جہاں لوگ اہلبیت اطہار کی ولایت اور دوستی پر فخر کرتے ہیں، کچھ منافق اہلبیت کے مقدس نام پر اور ''ولاء اہلبیت،، کے مقدس مورچے کے نام پر قرآن، اسلام اور اہل بیت کے خلاف اور غاصب یہودیوں کے مفاد میں مورچے تعمیر کرتے ہیں (یہ قبل از انقلاب اسلامی کی صورت حال کی طر ف اشارہ ہے۔ مترجم) اور یہ اسلام، قرآن، پیغمبر اکرم اور اہلبیت کرام پر سب سے زیادہ گھناؤنا ظلم ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے:
انی ما اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف علیهم سوء التدبیر ___ '' میں اپنی امت کے لیے فقر و تنگدستی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں بلکہ امت کی جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ کچج فکری ہے۔ فکر کا افلاس میری امت کے لیے جتنا خطرناک ہے اقتصادی افلاس اتنا خطرناک نہیں ہے۔،،
ب:۔دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن سے استنباط کرنے کا ہمارا طریقہ صحیح ہو۔ قرآن اسی صورت میں رہنما اور ہادی ہے کہ اس پر صحیح غور و فکر کیا جائے، اس کی عالمانہ تفسیر کی جائے اور اہل قران جو علم میں قرآن کے راسخین ہیں، کی رہنمائی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جب تک قرآن سے استنباط کرنے کا ہمارا طریقہ صحیح نہ ہو اور جب تک ہم قرآن سے استفادہ کرنے کی راہ اور اس کا اصول نہ سیکھیں ہم اس سے بہرہ مند نہیں ہوسکتے۔ مفاد پرست یا نادان لوگ کبھی قرآن کو پڑھتے ہیں اور بائل مطلب کے پیچھے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے نہج البلاغہ کی زبان سے سنا کہ وہ حق بات کہتے ہیں اور اس سے باطل مراد لیتے ہیں یہ قرآن پر عمل کرنا اور اس کا احیاء نہیں ہے۔ بلکہ یہ قرآن کو مار ڈالنا ہے۔ قرآن پر عمل تب ہے جب اس سے صحیح مطلب درک کیا جائے۔
قرآن ہمیشہ مسائل کو اصول اور کلیہ کی صورت میں پیش کرتا ہے لیکن کلی جزئی پر تطبیق صحیح فہم اور ادراک کے اوپر منحصر ہے۔ مثلاً قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ فلان روز علی علیہ سلام اور معاویہ کے درمیان جنگ ہوگی اور یہ کہ حق علی علیہ سلام کے ساتھ ہے، قرآن میں صرف اس قدر آیا ہے کہ :
( و ان طائفتان من المومنین اقتتلو فاصلحوا بینهما فان بغت احدٰهما علیٰ الاخرٰی فقاتلوا التی تبغی حتی تفیئی الی امر الله )
(سورہ حجرات آیت نمبر ۹)
''اگر مؤمنون کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، تو ان کے درمیان صلح کرادو اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر سرکشی اور ظلم کرے تو جو ظالم ہے اس کے ساتھ جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرلے۔،،
یہ قرآن اور اس کا طرز بیان ہے لیکن قرآن نہیں کہتا کہ فلاں جنگ میں فلاں حق پر ہے اوردوسرا باطل پر؟! قرآن ایک ایک کا نام نہیں لیتا۔ وہ نہیں کہتا کہ چالیس سال بعد یا اس کے بعد معاویہ نام کا ایک آدمی پیدا ہوگا اور علی علیہ سلام کے ساتھ جنگ کرے گا تم علی علیہ سلام کی طرف سے جنگ کرو اورجزئیات پر بحث ہونی بھی نہیں چاہےے قرآن کے ہیے ضروری نہیں ہے کہ موضوعات کو گن کر حق اور باطل پر انگلی رکھ کے بتادے ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے پس اسے چاہیے کہ اصول اور کلیات کو واضح کرے تاکہ جب بھی کسی زمانے میں کوئی باطل حق کے بالمقابل کھڑا ہوتو لوگ ان کلیات کو معیار بنا کر عمل کریں۔یہ لوگوں کا اپنا وظیفہ ہے کہ اصل دکھا دینے (وان طائفتان من المؤمنین اقتلوا ۔۔۔ الخ) کے بعد اپنی آنکھین کھلی رکھیں اور سرکش اور غیر سرکش گروہ میں تمیم کریں اور اگر سرکش گروہ صحیح معنوں میں سرکشی سے ہاتھ اٹھالے تو قبول کریں اور اگر ہاتھ نہ اٹھالے اور حیلہ کرے اور صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو شکست سے بچائے تاکہ نیا حملہ کرنے کا موقعہ پالے اور پھر سرکشی کرنے کے لیے اس آیت کا جس میں خدا فرماتا ہے:
( فان فاء ت فاصلحوا بینهما )
دامن تھام لے، تو اس کے حیلہ کو قبول نہ کریں۔
ان تمام چیزوں کی تشخیص کرنا خود لوگوں کا کام ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان عقلی اور اجتماعی طور پر بالغ ہوں اور اسی عقلی بلوغت کے ساتھ مرد حق اور غیر مرد حق میں تمیز کریں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہر وقت لوگوں کے ساتھ اس طرح رویہ رکھے جس طرح نابالغ بچے کے ساتھ اس کا ولی عمل کرتا ہے، زندگی کی جزئیات کو کسی کے سرپرست کی حیثیت سے انجام دے اور ہر خاص موضوع کی علامت اور محسوس اشاروں سے تعین کرے۔
بنیادی طور پر اشخاص کی پہچان، ان کی صلاحیتوں، اہلیتوں اور اسلام اور اسلام کے حقائق کے ساتھ ان کی وابستگی کو پرکھنا بذات خود ایک فریضہ ہے اور غالباً ہم اس اہم فریضے سے غافل ہیں۔ علی علیہ السّلام فرماتے تھے:
''انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفو الذی ترکه،،
(نہج البلاغہ خطبہ ۱۴۷)
''تم ہرگز حق کو نہیں پہچان سکتے اور راہ راست پر نہیں پہنچ سکتے جب تک اس شخص کو نہ پہچانو جس نے راہ راست کو چھوڑ دیا ہے۔،،
یعنی صرف اصول اور کلیات کی شناخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک مصداق اور جزئیات سے ان کی تطبیق نہ ہو کیونکہ ممکن ہے افراد یا اشخاص کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے یا موضوع کو نہ پہچاننے کی وجہ سے تم اسلام، حق اور اسلام کے رسوم کے نام پر اسلام اور حقیقت کے خلاف اور باطل کے مفاد میں کام کر رہے ہو۔
قرآن میں ظلم، ظالم، عدل اور حق کا ذکر آیا ہے لیکن دیکھناچاہیے کہ ان کے مصداق کون ہےں؟ کہیں ہم کسی ظلم کو حق، اور کسی حق کو ظلم نہ سمجھ رہے رہوں؟ اور پھر انہی کلیات کے تحت اور اپنے خیال میں قرآن کے حکم پر عدالت اور حق کو ختم نہ کر رہے ہوں؟
نفاق کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت:
تمام جنگوں میں سب سے مشکل نفاق کے ساتھ جنگ کرنا ہے کیونکہ یہ اسیے شاطروں کے ساتھ جنگ ہے جو بیوقوفوں کو آلہء کار قرار دیتے ہیں۔ یہ جنگ کفر کے ساتھ جنگ کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے کیونکہ کفر کے ساتھ جنگ میں مقابلہ ایک واضح، ظاہر اور بے پردہ معاملے سے ہے لیکن نفاق کے ساتھ جنگ کرنا ایک پوشیدہ کفر کے ساتھ جنگ ہے۔ نفاق کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک ظاہری چہرہ جو اسلام اور مسلمانی کا ہے اور ایک چہرہ باطن کا جو کفر اور شیطنت ہے اور اس کا پچاننا عام لوگوں اور معمولی افراد کے لےے بہت دشوار ہے اور بسا اوقات ناممکن ہے۔ اس طرح نفاس کے ساتھ جنگ کرنا غالباً شکست کھان کیونکہ عام لوگوں کے ادراک کی لہریں ظاہر کی سرحد سے آگے نہیں بڑھتیں اور پوشیدہ چیزوں کو روشن نہیں کرتیں اور اتنی گہری نہیں ہوتی کہ باطن کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔ امیر المومنین اس خط میں محمد ابن ابی بکر کولکھا گیا، فرماتے ہیں:
''ولقد قال لی رسول الله! انی لا اخاف علی امتی مومنا ولا مشرکاء اما المؤمن فیمنعه الله باایمانه و اما المشرک فیقمعه الل ه بشرکه و لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان، یقول ما تعرفون و یفعل
ماتنکرون ۔،،(۱)
''پیغمبر نے مجھ سے کہا میں اپنی امت پر مومن اور مشرک سے نہیں ڈرتا کیونکہ مؤمن کو خدا اس کے ایمان کی وجہ سے باز رکھتا ہے اور مشرک کو اس کی سرکشی کی وجہ سے رسوا کرتا ہے لیکن تمہارے اوپر منافق دل اور دانا زبان سے ڈرتاہوں کیونکہ وہ وہی کہتا ہے جو تم پسند کرتے ہو اور جسے تم ناپسند کرتے ہو اسے کرگزرتا ہے۔،،اس مقام پر رسول اللہ(صلّی اللّہ علیہ وآلہ وسلّم) نفاق اور منفاق کی طرف خطرے کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ امت کے عام لوگ بے خبر اور ناآگاہ ہیں اور ظاہر داریوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔(۲)
____________________
۱) نہج البلاغہ نامہ ۲۷---- (۲) اسی لیے ہم اسلامی تاریخ کے دھارے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی مصلح نے لوگوں، ان کی اجتماعی و دینی زبوں حالی کی اصلاح کی خاطر قیام کیا ہے اور مفاد پرستوں اور ظالموں کا مفاد خطرے میں پڑا ہے انہوں نے فوری طور پر تقدس کا لبادہ پہن لیا ہے اور تقویٰ اور دین کی ظاہر داری سے کام لیا ہے ۔ عباسی خلیفہ، مامون الرشید جس کی عیاشیاں اور فضول خرچیاں حکمرانوں کی تاریخ میں مشہور و معروف ہیں جب وہ علویوں کو دیکھتا ہے کہ انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں فوراً شاہی جبہ اتار پھینکتا اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر اجتماعات میں آنکتا ہے۔ ابو حنیفہ اس کا فی جس نے اس کے درہم و دینار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے مامون کے اس کام کو سراہتا ہے اور تعریف میں کہتا ہے:
مامون کز ملوک دولت اسلام ---ہگز چون اوند ید تازی ودہقان
مامون کہ اسلامی ممالک کے بادشاہوں میں اس کی طرح کوئی نہیں دیکھا گیا، بد اور دہقان کی طرح سادہ
جبہ ای از حزبداشت برتن و چندان ---سودہ و فرسودہ گشت بروی و خلقان
کسی وت اس کا ریشمی جبہ تھا جو اس کے دوش پر ہوتا تھا اور بہت نرم ونازک تھا مگر اب وہ پرانا ہوگیا اور پھٹ چکا ہے
مرند مارا از آن فزود تعجب ---کردند از وی سوال از سبب آن
ہم نشینوں کو اس پر سخت تعجب ہوا انہو ںنے سوال کیا کہ اس کا سبب کیا ہے
گفت ز شاہان حدیث ماند باقی ---در عرب و در عجم نہ توزی و کنان
اس نے کہا: بادشاہوں کی ایک بات باقی رہنے دو عرب و عجم میں کہ اس کے پاس کوئی سلاہوا سن کا کپڑا نہ تھا
اور دوسروں میں بھی ہر ایک نے ''قرآن کو نیزہ پر بلند کرنے کی،، تخریبی گھسی ٹی سیاست کا سہارا لیا اور (مصلحین کی) تمام زحمتوں اور قربانیوں کی سرکوبی کی اور انقلابات کو ابتداء ہی میں کچل دیا اور یہ لوگوں کی جہالت اور نادانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ رسوم اور حقائق کے درمیان تمیز نہیں کرتے اور اس طرح اپنے اوپر انقلاب اور اصلاح کی راہ بند کرتے ہیں ارو اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب تمام اسباب بے اثر ہوجائیں اور پھر نئے سرے سے سفر شروع کریں۔
یاد رکھنا چاہیے جتنے احمق لوگ زیادہ ہوں گے نفاق کا بازار تانا ہی گرم ہوگا۔
احمق اور حماقت سے جنگ کرنا نفاق کے ساتھ جنگ کرنا ہے کیونکہ احمق منافق کا آلہئ کار ہوتا ہے لہذالازمی طورپر احمق اور حماقت کے ساتھ جنگ کرنا، منافق سے اسلحہ چھین لینے اور منافق کے ہاتھ سے تلوار چھین لینے کے مترادف ہے۔
علی علیہ سلام کی سیرت سے جو عظیم نکتے ہمیں ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس طرح کی جنگ کسی خاص جمعیت کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جہاں بھی کچھ مسلمان اور وہ جو وضع دینی رکھتے ہیں اور غیروں کی ترقی اور استعماری مقاصد کو آگے بڑھانے میں آلہئ کار قرار پائیں اور استعمار گر اپنے مفادات کو بچانے کے لیے ان کو آگے کرکے ان کو اپنے لیے ڈھال بنائیں اور ان کے ساتھ جنگ کرنا ان ڈھال بننے والوں کو ختم کیا جائے تاکہ راہ کی رکاوٹ ختم ہو جائے اور دشمن کے قلب پر حملہ کیا جاسکے خوارج کو بگاڑنے کےلئے معاویہ کی کوشش شاید کامیاب تھیں اسی لیے اس روز بھی معاویہ اور اسی قبیل کے کچھ لوگ جیسے اشعث ابن قیس وغیرہ تخریب کار عناصر نے خوارج کو ڈھال بنا رکھا تھا۔
خوارج کو داستان ہم کو یہ حقیقت سمجھا دیتی ہے کہ ہر انقلاب میں پہلے ڈھال بننے والے کو نابود کر دینا چاہیے اور حماقتوں سے جنگ کرناچاہیے جس طرح علی علیہ سلام نے تحکیم کے واقع کے بعد پہلے خوارج سے نمٹ لیا اس کے بعد معاویہ کا تعاقب کرنا چاہا۔
علی علیہ سلام ___ سچے امام اور پیشوا
وجود علی علیہ سلام، تاریخ و سیرت عی، خلق و خوی علی علیہ سلام، رنگ و بوئے علی علیہ سلام، سخن وگفتگوئے علی علیہ سلام سراسر درس ہے، سرمشق ہے، تعلیم ہے اور رہبری ہے۔
جس طرح علی علیہ سلام کے جاذبے ہمارے لئے سبق آموز اور درس ہیں ان کے دافع بھی اسی طرح ہیں ہم معمولاً علی کی زیارتوں اور اظہار ادب کے سارے پیرایوں میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست کے دوست اور تمہارے دشمن کے دشمن ہیں اس جملے کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ ہم اس نقطے کی طرف جا رہے ہیں جو تمہارے جاذبے کے مدار میں قرار پاتا ہے اور تم جذب کرتے ہو اور اس نقطے سے دوری اختیار کرتے ہیں جس کو تم دفع کرتے ہو۔
جو کچھ ہم نے گزشتہ بحثوں میں کہا ہے وہ علی علیہ سلام کے جاذبہ اور واقعہ کا ایک گوشہ تھا ، خاص طور پر دافعہ علی کے بارے میں ہم نے اختصار سے کام لیا ہے لیکن جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ علی نے دو گروہوں کو سختی سے دفع کیا ہے۔
۱: شاطر منافق
۲: زاہدان امق
ان کے شیعہ ہونے کے دعویداروں کیلئے یہی دو سبق کافی ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور منافقوں کے فریب میں نہ آئیں۔ وہ تیز نظر رکھنے والے بنیں اور ظاہر بینی کو چھوڑ دیں کہ آج جامعہ تشیع ان دو مصیبتوں میں سخت مبتلا ہے۔
والسلام علیٰ من اتبع الهدیٰ
اختتام ترجمہ ۱۳ ستمبر ۱۹۸۵ء بروز جمعہ
بوقت ۴۰ ۔ ۱۲ ظہر
فہرست
پیش لفظ ۴
مقدمہ ۸
قانونِ جذب و دفع ۸
انسانی دنیا میں جاذبہ و دافعہ ۹
جذب و دفع کے سلسلے میں لوگو ں کے درمیان فرق ۱۲
علی علیہ السّلام۔ دوہری قوت والی شخصیت ۲۱
جاذبہئ علی علیہ السلام کی قوت ۲۴
طاقت ور جاذبے ۲۴
تشیّع ۔ مکتب عشق و محبت ۳۱
اکسیرِ محبت ۳۴
حصار شکنی ۴۳
عشق۔ تعمیر ہے یا تخریب ۴۵
اولیاء سے محبت و ارادت ۵۲
مؤمنین کی آپس میں محبت ۵۵
معاشرے میں محبت کی قوت ۵۸
تہذیبِ نفس کا بہترین وسیلہ ۶۲
تاریخ اسلام سے مثالیں ۷۴
دوسری مثال ۷۶
ایک اور مثال: ۸۰
ایک مثال اور: ۸۳
علی علیہ سلام کی محبت قرآن و سنت میں ۸۷
طہارت و پاکیزگی کا خزینہ: ۸۸
جاذبہئ علی علیہ سلام کا راز ۹۳
دافعہئ علی علیہ سلام کی قُوّت ۹۸
علی علیہ سلام کی دشمن سازی ۹۸
ناکثین و قاسطین و مارقین ۱۰۰
خوارج کا ظہور ۱۰۲
اصول عقائد خوارج ۱۱۱
خلافت کے بارے میں خوارج کا عقیدہ ۱۱۲
خلفاء کے بارے میں خوارج کاعقیدہ ۱۱۳
ہمیشہ ان کے ساتھ برسرپیکار رہتے تھے۔ ۱۱۴
خوارج کا خاتمہ ۱۱۴
رُسوم یا روح ۱۱۵
علی علیہ سلام کی جمہوریت ۱۲۲
خوارج کی بغاوت اور سرکشی ۱۲۳
خوارج کی نمایاں خصوصیّات ۱۲۵
اسلامی فرقوں کا ایک دوسرے پر اثر: ۱۴۶
قرآن کو نوک نیزہ پر بلند کرنے کی سیاست ۱۵۰
نفاق کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت: ۱۵۴
علی علیہ سلام ___ سچے امام اور پیشوا ۱۵۷